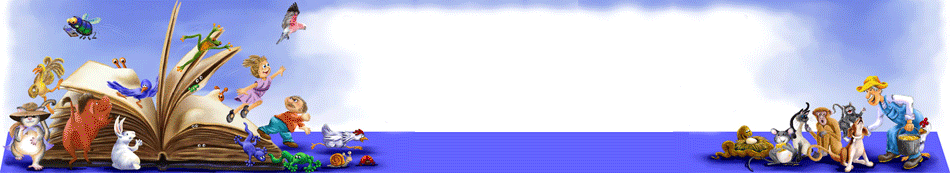زمین کے مرکز سے
میمونہ طارق
۔۔۔۔۔۔۔۔
ایک سر پھرے کی کہانی جو مزید دو کو ساتھ لیکر زمین کا مرکز دریافت کرنے نکل کھڑا ہوا
۔۔۔۔۔۔۔۔
اس ناول کے مصنف جولس ورن (Jules verne) ہیں۔ جولس ورن ۱۸۲۸ء میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ جولس ورن نے ایسی بہت سی چیزوں کے تصور دیے جو اس وقت ناقابل یقین سمجھے جاتے تھے لیکن آج دنیا اُن کے دیے گئے تصورات کے مطابق ناصرف چاند پر پہنچ چکی ہے بلکہ سمندر کے اندر بھی آب دوز چلائی جارہی ہیں۔ ورن نے کچھ ایجاد تو نہیں کیا لیکن مستقبل کے سائنس دانوں کے لیے ایسے نشان ضرور چھوڑ دیے جنھوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے ناقابل یقین ایجادات کیں۔
اُردو ادب کے حوالے سے یہ احساس موجود ہے کہ اس میں مستقبل کا نقشہ کھینچنے کے بجاے ماضی سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ایسا ادب تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں مستقبل کی دنیا دکھائے ہمارے مستقبل کے لیے کارآمد ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماضی کو فراموش کردیا جائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔
اس واقعے کو گزرے زمانہ ہوا لیکن میں جب بھی اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میری زندگی میں اتنی ہلچل کبھی نہیں تھی جتنی اس ایڈونچر نے مچائی ۔اُف وہ بھی کیا دن تھے۔
آپ لوگوں کو ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ میں شروع سے یہ کہانی سناتا ہوں تاکہ کہانی کا لطف اُٹھایا جا سکے۔
ان دنوں میں اپنے چچا کے ساتھ کراچی میں رہتا تھا۔ وہ مختلف سائنسی علوم کے ماہر تھے اور ایک جامعہ میں پڑھاتے تھے۔
چچا نے میرے ابو سے کہہ کر مجھے کراچی بلوایا تاکہ میں ان کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر سکوں۔ چچا کی علمی قابلیت سے ویسے میں بہت متاثر تھا جب اُنھوں نے مجھے بلایا تو حقیقتاً میں بہت خوش تھا۔چچا زمین کے علم یعنی علم ارضیات کے ماہر تھے اور مجھے زمین اور اس کی تہہ کے بارے میں جاننے کا بے حد شوق تھا۔
چچا جان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زمین کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ زمین کے حوالے سے اب تک دنیا بھر میں بہت سارے لیکچر دے چکے ہیں اور وہ مختلف زبانیں جانتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ تھی کہ چچا جان اب تک زمین کے چھ سو مقامات کو اچھی طرح جانچ پرکھ چکے تھے۔ وہ ان مقامات کی لمبائی، چوڑائی، مٹی کا ذائقہ، وہاں کی بُو اور آواز کے متعلق جان کر اور پڑھ کر خود بھی کھردرے قسم کے ہوچکے تھے۔ وہ پچاس سال کے تھے۔ ضرورت سے بڑا چشمہ اپنی ناک پر سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے رہتے تھے۔ ستواں ناک سے ایسا لگتا کہ جیسے کچھ سونگھ رہے ہیں۔ چلتے وقت لمبے لمبے ڈگ بھرا کرتے۔ ہاتھوں کو مسل کر مٹی بنانا ان کی عادت تھی۔ ایسا لگتا کہ جیسے کسی کو مکا جڑنے والے ہیں۔ اپنے کام میں اتنے مگن رہتے کہ خوشی کے لمحات اور تقریبات میں شریک ہونے سے پرہیز کرتے تھے۔
میرے چچا دلاور کوئی بُرے آدمی نہیں تھے۔ ان کی بہت سی عادتیں اچھی تھیں۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ہر بات ماننا مجھ پر لازم تھا۔
اب اس دن کا ذکر آنے لگا ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی ہے۔ ایک دن اُنھوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کیں۔
’’ارحم ارحم ۔‘‘ ان کی آواز میں شدت پیدا ہوتی جارہی تھی۔ میں اس وقت کھانا کھانے والا تھا۔ اس وقت یہ آواز بے وقت کی راگنی لگی۔
لیکن مرتا کیانہ کرتا کے مصداق جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر ان کے کمرے میں پہنچا، ان کا کمرا کسی عجائب گھر کی طرح مختلف معدنیات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھنے میں اتنے منہمک تھے کہ اُنھیں میری آمد کا علم ہی نہیں ہوا۔
’’لاجواب۔‘‘ چچا جان کتاب پڑھتے ہوئے خوشی سے چلّائے۔ ’’بہترین۔‘‘
میں نے غور سے کتاب کو دیکھا، یہ پیلے رنگ کی بہت خستہ سی کتاب تھی، جس میں صرف چچا جان ہی دلچسپی لے سکتے تھے۔
’’آپ نے مجھے بلایا چچا جان۔‘‘ میں نے ان کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
’’جزیروں پر لکھنے والے مشہور مصنف ’بوزور خان‘ کے مطابق بارہویں صدی میں جزیرہ اٹاپو پر ایک شہزادی کی حکومت تھی۔‘‘
’’ یہ کتاب کس زبان میں ہے۔‘‘ اُن کی بات سنتے ہی میں نے پوچھا۔
میں نے سوچا اگر یہ اُردو میں ترجمہ ہوئی تو میں اسے پڑھ سکوں لیکن وہ کتاب کوئی ترجمہ نہیں تھی بلکہ کسی عجیب وغریب زبان میں تھی۔
یہ زبان اس جزیرے کی مقامی زبان معلوم ہوتی تھی جو ٹیڑھے میڑھے، آڑھے ترچھے لفظوں پر مشتمل تھی۔ جسے پڑھنے سے چچا دلاور بھی عاجز تھے۔ وہ مجھے کتاب دکھانے کے لیے اُٹھے، اچانک کتاب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر گرنے لگا۔
چچا جان نے کسی بلی کی طرح جھپٹ کر کاغذ کے ٹکڑے کو جھپٹا، یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ جس پر کسی اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔
’’معلوم نہیں یہ کون سی زبان ہے۔‘‘ چچا جان نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
میں نے غور سے اس ٹکڑے کو دیکھا، یہ مجھے خزانے کی تلاش والے نقشے کے مشابہہ لگا۔ جس میں پہلے کوئی سراغ ملتا ہے، پھر نقشہ اور آخر میں خزانہ۔۔۔ اس ٹکڑے میں مجھے ایک حیرت انگیز ایڈونچر اپنا منتظر نظر آرہا تھا۔
مگر یہ زبان نہ تو مجھے سمجھ آرہی تھی اور نہ چچا جان کو۔۔۔
اتنی دیر میں کھانالگ چکا تھا لیکن چچا جان کے ذہن پر یہ کتاب کچھ ایسی چھائی ہوئی تھی کہ اُنھوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اس لیے میں چچا جان کے اس نئے اور عجیب مشغلے کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔
ابھی میں کھانا ختم کرکے میٹھا کھا رہا تھا کہ ان کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔
وہ ابھی تک بیٹھے اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھور رہے تھے۔ وہ کہنے لگے: ’’ یہ رونک زبان میں لکھا گیا ہے اور اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ میں ہر حال میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ چاہے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔‘‘
اُن کی بات سن کر میں ڈر سا گیا۔ چچا جان کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا رویہ تو بچوں کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا۔ اب میں نے دوبارہ ان الفاظ کو دیکھا،ان کا رویہ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آرہا تھا۔
’’بیٹھ جاؤ ۔‘‘ چچا جان نے تحکمانہ (رعب دار)لہجے میں کہا۔
’’اور جو میں کہوں وہ لکھتے جاؤ۔‘‘
’’اُف کیا مصیبت ہے۔‘‘میں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے مجبور تھا۔
اُنھوں نے مجھ سے لکھوانا شروع کیا۔ یہ تقریباً انگریزی کے ۲۱؍ الفاظ بن رہے تھے ۔ اور وہ بھی بے ترتیب ۔ جس کا نہ سر نظر آرہا تھا نہ پیر۔ میں نے جیسے ہی لکھنا بند کیا۔ اُنھوں نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرنے لگے۔
’’ مجھے جاننا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔‘‘ چچا دلاور بڑبڑا ئے۔
’’ یہ مجھے کسی کھیل کی طرح لگ رہا ہے۔ چھپانے والے نے بڑی خوبی سے اس میں اہم پیغام چھپایا ہے۔‘‘ چچا جان نے کہا۔
میری اس حوالے سے راے بہت خراب تھی لیکن میں اس کا اظہار کرکے چچا جان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔
’’مختلف لوگوں نے ان الفاظ کو لکھا ہے ، یہ کتاب اس کاغذ کے ٹکڑے سے ۲۰۰ سال پہلے کی ہے۔ یہ ٹکڑا اس میں بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ جانتے ہو،آخری بار اس کتاب کو کس نے خریدا۔‘‘
’’یقیناًآپ نے۔‘‘ میں نے کہا۔
چچا جان نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا ۔’’ میرا مطلب ! مجھ سے پہلے۔‘‘ اُنھوں نے کتاب کو دوبارہ دیکھا، اندر والے صفحے پر کسی احمد خانی نام کے آدمی کا نام تھا۔
’’ اوہ یہ تو مشہور کیمیا دان احمد خانی ہیں۔ جو ماہر ارضیات بھی تھے۔ اُنھوں نے اس راز کو ان خفیہ الفاظ میں شاید اس لیے لکھا کہ کوئی ماہر ارضیات ہی اسے دریافت کرسکے۔‘‘
چچا جان نے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ وہ مستقل طور پر کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ میں جب تک ان الفاظ کی کھوج نہیں لگالیتا، میں نہ سوؤں گا اور نا ہی کھانا کھاؤں گا۔‘‘
’’چچا جان ایسا مت کیجیے۔‘‘
’’ نہیں میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔‘‘
’’ ویسے میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ چلو اچھا ہے اب سکون سے سوؤں گا اور کھاؤں گا لیکن یہ میرا صرف ایک خیال تھا۔
چچا جان نے ان خفیہ لفظوں کو جاننے کے لیے مختلف زبانوں کی لغت اپنے سامنے رکھیں اور کئی گھنٹوں تک اس میں سر کھپاتے رہے لیکن وہ کچھ بھی حاصل نہ کرسکے۔
احمد خانی کا نام لاطینی زبان میں لکھا گیا تھا۔ چچا جان کا خیال تھا کہ شاید یہ لفظ قدیم لاطینی ہیں لیکن لاطینی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں تھے۔
چچا دلاور نے ان جملوں کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کی۔ لیکن دھاک کے وہی تین پات، ان لفظوں کے کوئی بھی معنی میرے ذہن میں تو کیا چچا کے ذہن میں بھی نہیں آرہے ہوں گے مگر چچا جان ابھی تک پُرجوش تھے۔ جب کافی دیر تک بھی ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اُنھوں نے غصے میں میز پر مُکّا مارا اور دروازہ زور سے بند کرکے باہر نکل گئے۔
میں نے گہرا سانس خارج کیا۔ اب کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر تک میں نے بھی اس کاغذ کو بھلائے رکھا۔ جب بوریت ہونے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کاغذ اُٹھا لیا اور ان لفظوں پر غو ر کرنے لگا۔ یہ مجھے انگریزی، عربی، لاطینی اور جرمن زبان کا ملغوبہ نظر آرہا تھا۔ یقیناًجس شخص نے بھی لکھا ہے اسے پاگل کہنے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔
کمرے میں حبس کی وجہ سے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسی کاغذ کو پنکھے کے طور پر استعمال کرناشروع کر دیا، ہوا کرتے ہوئے پہلی بار میری نظر اس کاغذ کے دوسری طرف پڑی۔
’’اُف خدایا، یہ کیا۔۔۔ یہاں تو اس کا لاطینی ترجمہ دیا ہوا ہے۔ ‘‘ میں خوشی سے چلا اُٹھا۔میری آنکھیں حیرت اور خوشی سے اُبلنے لگی تھیں۔
میں نے اسے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ فرط جذبات سے کانپ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی میں نے کوئی اہم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔
’’ نہیں۔۔۔ نہیں، یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔‘‘ میں خود پر چلایا۔
’’اگر یہ چچا دلاور کو معلوم ہو گیا تو وہ دنیا کے اس خراب اور خطرناک سفر پر نکل پڑیں گے اور ہو سکتا ہے خود کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔‘‘ میں نے ڈرتے ڈرتے سوچا۔
مجھے اس راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ کاغذ اور کتاب کو اُٹھایا۔ جیسے ہی میں نے ان دونوں چیزوں کو جلانا چاہا۔ چچا کمرے میں داخل ہوئے۔
میں نے خوف سے جھرجھری لی۔ مجھے ڈر تھا کہ چچا جان کو میرے ارادے کا علم نہ ہو گیا ہو لیکن اُنھوں نے محسوس ہی نہیں کیا اور میرے ہاتھ سے کاغذ لے کر اسے دوبارہ پڑھنے لگے۔
اب تو مجھے سچ مچ ڈر لگنے لگا کہ چچا جان بالآخر اس راز کو پا ہی لیں گے۔ میری اب اس معاملے سے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی اور کمرا خالی چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں وہیں صوفوں کے درمیان لیٹ کر سو گیا۔ کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو اُنھیں ویسے ہی کام کرتے ہوئے پایا۔ نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہورہی تھیں۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کی یکسوئی کم ہونے میں ہی نہیں آرہی تھی۔
ان کی لگن دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہورہی تھی لیکن اس راز سے پردہ اٹھانے کا جوکھم میں نہیں اُٹھا سکتا تھا۔
دوسری بار میری آنکھ ان کے چلانے سے کھلی۔ وہ پرجوش انداز میں حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے جیسے اُنھیں آب حیات کا راز معلوم چل گیا ہو۔
’’ارحم! تمھیں پتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک اہم راز ہے۔ ایک ایڈونچر کی نشاندہی کرنے والا کارآمد کاغذ۔۔۔ یہ خفیہ تحریر احمد خانی نے نہیں بلکہ کسی اور نے تحریر کی تھی۔ احمد خانی نے تو کاغذ کے پچھلے حصے میں اس گتھی کو سلجھایا ہے۔
’’جب تم اسنیفل کی پہاڑیوں پر پہنچو گے تو وہاں آتش فشاں کے تین دہانے نظر آئیں گے، ان پہاڑیوں کا سایہ پہلی جولائی کو جس دہانے پر ہوگا وہیں سے زمین کے مرکز تک پہنچنے کا راستہ ہے۔‘‘ احمد خانی
وہ یہ ترجمہ پڑھ کر خوشی سے اُچھلے، ان کے اُچھلنے سے میزیں اِدھر اُدھر گر گئیں، کتاب کو بھی اُنھوں نے ہوا میں اچھال دیا اور بچوں کی طرح خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔
’’ہم شروع کرنے والے ہیں کچھ خاص اور تم میرے ساتھ رہو گے۔‘‘ چچا دلاور نے پرجوش انداز میں کہا۔
لیکن کہاں سے۔‘‘میں نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔
’’ زمین کے مرکز سے۔‘‘
اُنھوں نے نقشہ نکالا اور مجھے بتانے لگے:’’یہ جزیرہ پورا آتش فشاں سے ڈھکا ہوا ہے۔‘‘ اُنھوں نے نقشے میں جزیرے کی جانب اشارہ کیا۔
’’لیکن یہ اسنیفل کی پہاڑیوں کا کیا مطلب ہے؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’یہاں دیکھو۔‘‘ اُنھوں نے نقشے میں ایک جگہ انگلی رکھی۔ ان جزیروں میں روج نامی جگہ تھی جو ان کا دارالحکومت ہو اکرتا تھا۔ اس دارالحکومت کے مغربی کنارے پر یہ پہاڑیاں موجود ہیں جو دیکھنے میں ہڈی کی مانند لگ رہی ہیں۔ یہ پہاڑی ۵۰۰۰ فٹ بلند ہیں اور اسی پہاڑ کے ذریعے ہم زمین کے مرکز تک پہنچنے کا ناقابل یقین کارنامہ سرانجام دیں گے۔
’’کیا۔۔۔ ناممکن۔‘‘ میں چِلّایا۔
’’کیا ناممکن؟‘‘ انکل نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔
’’آپ جن آتش فشاؤں سے گزرنے کا کہہ رہے ہیں وہ گرم لاوے سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے۔‘‘
’’یہ تو کئی برس پہلے آتش فشاں تھے۔ اب تک تو یہ ختم ہوچکے ہیں اور غالباً ناپید ہیں۔‘‘
’’غالباً۔۔۔ واہ یہ خوب کہی۔ اچھا یہ بتائیے سورج کی روشنی جولائی کے پہلے عشرے تک مطلوبہ پہاڑ پر ہوگی۔ کیا احمد خانی ہمیں قصے کہانیاں سنا کر بے وقوف بنائے گا، اور ہم بن جائیں گے۔‘‘
’’احمد خانی ایک بڑے ماہر ارضیات تھے۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ شاید وہ بالکل اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جو زمین کا مرکز کہلاتا ہے۔ احمد خانی یہ بھی جانتا تھا کہ اسنیفل کی دو چوٹیاں بہت اہم ہیں اور سورج کی پوزیشن ایک درست راستے کا انتخاب کرنے میں معاون ثابت ہوگی اور پہلی جولائی کو روشنی آتش فشاں کے جس دہانے پر ہوگی۔۔۔ وہی راستہ اس کا صحیح راستہ ہوگا۔‘‘ چچا دلاور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں چچا جان سے حقیقت میں کافی متاثر تھا۔ موت کے منھ میں جانے سے بہتر تھا کہ میں مرعوبیت کا خول اُتاردوں لیکن یہ بھی چاہتا تھا کہ چچا جان مجھے بزدل نہ سمجھیں۔چچا دلاور کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔
’’اچھا ٹھیک! بالفرض آپ کی بات ٹھیک بھی ہے تو زمین کے اندر درجۂ حرارت کے حوالے سے جو سائنسی نظریات ہیں ان کا کیا ہوگا۔‘‘
’’مجھے ان نظریات کی پرواہ نہیں جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اس کی حقیقت جاننے کا یہی بہتر طریقہ ہے کہ ہم زمین کے اندر جائیں اور درجۂ حرارت کا راز جانیں۔‘‘ چچا دلاور نے اپنی منطق پیش کی۔
’’اُف!‘‘ میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
مجھے واقعی یہ سب ایک عجیب اور بے مقصد ایڈونچر لگ رہا تھا۔ شام کو میں واپس گھر آیا تو چچا جان کو مصروف پایا۔ وہ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔
’’بے وقوف لڑکے! تم کہاں تھے۔ جلدی سے اپنا سامان باندھو۔‘‘
’’کیا ہم واقعی جارہے ہیں؟‘‘ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔
’’ہم کل صبح روانہ ہوں گے۔‘‘چچا جان کا دو ٹوک جواب آیا۔
*۔۔۔*
ہم نے کئی شہروں کا سفر طے کیا۔ یہ سفر ٹرین اور بحری جہاز کے ذریعے طے کیاگیا۔ گیارہ دن بحری جہاز کے سفر میں لگے۔ راستے میں ہم دونوں چچا بھتیجا بیمار بھی ہوئے۔ چچا جان کی طبیعت زیادہ ناساز رہی۔ جب ہم مطلوبہ منزل پر پہنچے تو میں عرشے تک چچا جان کو سہارا دے کر لایا۔
عرشے پر آکر ان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ وہ بہت پرجوش ہونے لگے اور خود ہی چلنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ گر پڑتے کہ میں نے اُنھیں سہارا دیا۔ اُنھوں نے دور پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔
’’وہ ہیں اسنیفل کی پہاڑیاں۔۔۔ یہی راستہ زمین کے مرکز کی طرف جائے گا۔‘‘
’’چچا جان کا جنون دیکھ کر میں مسکرایا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ آگے کا سفر سخت کٹھن اور جان لیوا ہے۔
رات کو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہاں ہماری ملاقات ادریس نامی سائنس دان سے ہوئی۔ ہم نے اِنھیں صرف یہ بتایا کہ ہم سیاح ہیں اور ان جزیروں تک جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے احمد خانی کے بارے میں سوال کیا تو ادریس صاحب بولے: ’’اس جزیرے پر کوئی معلوماتی کتاب موجود نہیں ہے۔ احمد خانی صرف ماہر ارضیات ہی نہیں تھا بلکہ وہ سیاسی معاملات میں بھی اپنی راے دیتا تھا جس پر حکمرانوں نے اس کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر اس کی کتابیں عوام کے سامنے جلادی تھیں۔ احمد خانی ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جس کے حکمران مسلمان نہیں تھے اس لیے وہ خاموش اور گمنام ہوگئے۔‘‘
ادریس صاحب نے ہمیں راستے کے حوالے سے چند احتیاطی تدابیر بتائیں اور ایک گائیڈ کو بھی ہمارے پاس بھیجنے کا کہا جو اسنیفل کی پہاڑیوں کا اسرار جاننے میں ہماری مدد کرے۔ ڈاکٹر ادریس کو اسنیفل کی پہاڑیوں پر پائے جانے والے معدنیات سے غرض تھی۔ اُنھیں شاید اس پہاڑی کی اصل خوبی کا اندازہ نہیں تھا۔
حسب وعدہ اگلے دن ہوٹل کے کمرے میں لال بالوں، لمبے قد کاٹھ اور مضبوط جسم کے مالک داؤد سے ہم ملے۔ اس کی آنکھوں میں وفاداروں والی چمک تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جس پر اعتماد کرنے کا جی چاہنے لگا اور ہم نے بھی یہی کیا۔ داؤد ہمیں مختلف گاؤں سے گزارتے ہوئے اسنیفل کی پہاڑیوں تک لے جانے کے لیے راضی ہوگیا۔ ہم جو تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے اس میں داؤد ہمارا ہمرکاب تھا۔
اگلے دن ہم نے سفر کے لیے ضروری سامان خریدا۔ اس سفر میں ہمیں مختلف آلات کی بھی ضرورت تھی۔ کدال، کمند، لوہے کے جوتے، مضبوط رسی، روشنی کے لیے لالٹین، ۱۵۰ گریڈ تک درجۂ حرارت معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر، ہوا کے دباؤ کے لیے مینو میٹر، گھڑی، قطب، رات میں دیکھنے کے لیے چشمے، دو بندوقیں، بھالے جن کو ساتھ رکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیوں کہ ہمیں جنگل ‘ وحشیوں اور جانوروں کا خوف بھی نہیں تھا۔
خیر۔۔۔ یقیناًانکل کے نزدیک اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ ہم نے جب سفر شروع کیا تھا موسم ابر آلود تھا۔ راستے کے دشوار گزار اور جان لیوا ہونے سے دل گھبرایا جارہا تھا۔ مختلف خیالات اور وسوسے دل میں آرہے تھے۔ اس طرح کے تمام خوف ناک ایڈونچر یاد آنے لگے۔۔۔ جس میں سب مارے جاتے ہیں یا کوئی ایک بچ جاتا ہے۔ وہ ایک بچ جانے والا عموماً گائیڈ ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو کہانی سناسکے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے رشک بھری نظروں سے داؤد کی طرف دیکھا۔ اسنیفل کی پہاڑیوں پر چلے ہوئے دس دن ہوگئے تھے۔ میں اور چچا جان گھوڑوں پر سوار تھے جبکہ دو گھوڑوں پر ہمارا سامان لدا ہوا تھا۔ داؤد پیدل چل رہا تھا۔ اسے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کہا لیکن اس نے پیدل چلنے پر زور دیا۔
راستے میں کئی چھوٹے اور بڑے پہاڑ آئے۔ ہموار سطح کے علاوہ ایسے راستے بھی آئے جو آتش فشاں کی وجہ سے بن گئے تھے۔ داؤد ہماری رہنمائی کررہا تھا۔ وہ ایک عمدہ گائیڈ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا چچا جان لیکر جائے یا نا وہ ہمیں زمین کے مرکز تک ضرورلے جائے گا۔
ایک جگہ ایسی آئی کہ ہمیں اپنے گھوڑے چھوڑنے پڑے۔ ہمارا سفر خاموشی سے جاری تھا۔
موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ آتش فشاں چچا جان کے اندازے کے مطابق مردہ ہوچکے تھے۔ رات ہوچکی تھی۔ ہم نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور سوگئے۔ اگلے دن جاگے تو ایک حیران کن لیکن خوفناک منظر سامنے تھا۔ ہمیں نیچے کی جانب جاتی ہوئی ڈھلوان نظر آرہی تھی۔ میری تو ہمت ہی نہیں ہورہی تھی کہ اس ڈھلوان کو عبور کروں جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔
’’اُف یہ کیا پاگل پن ہے۔‘‘
داؤد نے رسی کو میرے گرد باندھا، ہم ایک دوسرے سے رسی کی مدد سے جُڑ گئے۔
’’یہ اس لیے کہ کوئی ایک گر جائے تو دوسرا اسے سنبھال لے۔‘‘ چچا جان نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔
’’اگر ایک گرے تو باقی دو بھی گریں‘‘۔ میں نے منھ بناتے ہوئے کہا۔
’’اور وہ جو گرے گا۔۔۔ وہ کون ہوگا؟‘‘ چچا جان نے معنی خیز انداز سے کہا۔ میرا منھ مزید بن گیا۔ مجھے پتا تھا کہ شاید گرنے والا میں ہی ہوں۔میں خود کو ایک بھیڑ سمجھ رہا تھا اور دہانے کو بھیڑیا۔ آدھے دن تک ہم نیچے اُترتے رہے۔ بلآخر پہاڑ پر نکلے ہوئے ایک چھجے پر پہنچے۔۔۔ وہاں سے ہمیں وہی تین دہانے نظر آئے جن کا ذکر احمد خانی نے اس کتاب میں رکھے کاغذ میں کیا تھا۔
ان تین دہانوں کو دیکھ کر چچا جان حیرت سے چِلّا اُٹھے۔ وہ پاگلوں کی طرح خوش تھے۔ اس بچے کی مانند جسے اچانک اپنے پسندیدہ کھلونے ڈھیر ساری تعداد میں مل جائیں۔ اب ہمیں نیچے اُتر کر اس سمت جانا تھا۔ جہاں یہ دہانے تھے۔
’’ارے باپ رے۔۔۔ یہ کیا‘‘ چچا جان کی حیرت سے چِلّا نے کی آواز آئی۔۔۔ وہ حیرت سے چِلّا ہی سکتے تھے کیوں کہ حیرت سے یہاں اچھلنا موت کے منھ میں جانے کے مترادف تھا۔
’’کیا ہوا۔‘‘ میں نے کہا۔۔۔ داؤد بھی قریب آیا۔
’’یہ دیکھو!‘‘ چچا جان نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔
’’ارے باپ رے‘‘ میری آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت اُمڈ آئی۔
*۔۔۔*
میرے اُچھلنے کی وجہ ’احمد خانی ‘کا نام تھا۔
’’اس کا مطلب احمد خانی یہاں تک پہنچا تھا۔‘‘ میں بڑبڑایا۔
’’وہ ایک ذہین آدمی تھا۔‘‘ چچا دلاور نے نیچے اُترتے ہوئے کہا۔
’’ہم اسنیفل پہاڑیوں کے اس دہانے تک پہنچ چکے تھے جس کے متعلق اس کاغذ میں لکھا گیا تھا۔
آسمان پر بادل موجود تھے جبکہ ہمیں دھوپ کا انتظار تھا۔ یہ وقت بڑا نازک تھا کیوں کہ سایہ جس سرنگ پر پڑتا ہمیں اسی سرنگ سے اندر جانا تھا۔ اس وقت اگرچہ بادلوں کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار تھا لیکن ہمیں بالکل بھی مزہ نہیں آرہا تھا کیوں کہ ہمیں دھوپ کی طلب تھی۔ دو دن کے انتظار کے بعد ہماری مراد بر آئی اور آسمان سے بادل چھٹنے لگے۔
پہاڑ کا سایہ دوپہر کے وقت عین تیسری سرنگ پر پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی سائے کو درمیانی سرنگ پر پڑتے ہوئے چچا جان نے دیکھا، وہ فرط جذبات سے چلا اُٹھے۔
’’آگے بڑھو میرے دوستو، آگے ہی آگے، زمین کے پیالے کی طرف۔‘‘
داؤد اور میں نے خاموشی سے سامان اُٹھایا۔ اسے ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا اور نیچے اُترنے کے لیے پَر تولنے لگے۔ نیچے جھانکتے ہوئے ہمیں دوسرا سرا نظر نہیں آرہا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے نیچے اُترنا شروع کیا۔ شروع شروع میں ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا۔ کناروں پر قدرتی طور پر راستے بنے ہوئے تھے۔ ہم کئی گھنٹے تک نیچے اُترتے رہے۔ بالآخر ہمارے پاؤں زمین سے ٹکرائے۔
’’اوہ ہم پہنچ گئے۔‘‘ میں نے کہا۔ ’’لیکن یہاں سے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آرہا۔‘‘ میں نے اپنی خوشی چھپائی۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر ہمیں راستہ نہیں ملتا تو ہم واپس چلے جاتے لیکن چچا دلاور نے بھلا کسی کو خوش ہوتے دیکھا تھا کیا؟ میری بات ختم ہوتے ہی کہنے لگے۔
’’ابھی ہم یہاں آرام کریں گے، میں نے بائیں جانب ایک سرنگ دیکھی ہے۔‘‘
’’اُف۔‘‘ میں نے کندھے اُچکاے۔ تھکن سے بُرا حال تھا۔ مستقل نیچے اُترنے سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔
ہم نے رسیوں اور کپڑوں کو پھیلا کر بستر تیار کیا، کھانا کھایا اور لمبی تان کر سوگئے۔
اوپر سے کسی سوراخ سے آنے والی ہلکی سی روشنی سے ہماری آنکھ کھلی، ہم بیدار ہوئے تو چچا جان نے کہا: ’’کیوں بھتیجے کیسی پُرسکون رات گزری۔‘‘
’’ہاں رات تو پرسکون تھی لیکن میں ابھی تک اسی شش و پنج میں ہوں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط۔۔۔‘‘
’’اب کوئی فائدہ نہیں۔۔۔ ہم سطح سمندر تک پہنچ چکے ہیں، بیرو میٹر دیکھ لو۔۔۔‘‘ یہ کہہ کر چچا جان نے ایک ڈائری نکالی اور اس میں کچھ لکھنے لگے۔
’’چلو بھتیجے! اب ہم وہاں قدم رکھنے لگے ہیں جہاں دنیا کے کسی آدمی کے قدم نہیں پہنچے ہیں۔‘‘
’’کیا احمد خانی بھی۔‘‘ میں نے کہا۔
’’جی احمد خانی بھی غالباًیہاں سے زیادہ آگے نہیں جاسکا ہے یا شاید گیا ہو۔‘‘ چچا جان نے بے یقینی سے کہا۔
داؤد اس تمام عرصے میں خاموش تھا۔ وہ خاموش طبیعت کا مالک تھا اور بہت کم ہی اس کے منھ سے کوئی لفظ نکلتا۔
سرنگ میں جانے کے لیے ہم نے لالٹینیں جلائیں۔ یہ لالٹینیں بیٹری سے چلتی تھیں۔ سرنگ روشنی میں نہاگئی تھی۔
ہم نے سرنگ میں قدم رکھا۔۔۔ اب ہمارا سفر نیچے سے نیچے کی جانب شروع ہوگیا تھا۔ مستقل کئی گھنٹے ہم نے نیچے ہی نیچے کی جانب سفر جاری رکھا۔ سرنگ رنگ رنگ کے پتھروں سے سجی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ درجۂ حرارت میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تھا اور ہوا کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی ٹھیک تھا۔
رات ہوچکی تھی، ہم نے رات کا کھانا کھایا۔۔۔ اس دوران نجانے کیا ہوا کہ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ آخر کار میں نے اپنی بے چینی کا ذکر چچا جان سے کر ہی دیا۔
’’مزید سفر کے لیے ہمارے پاس بہت کم پانی ہے اور راستے میں کسی چشمے سے پانی کے حصول کی اُمید بھی نہیں ہے۔‘‘
’’پریشان مت ہو بھتیجے! پانی ہم وافر مقدار میں ڈھونڈلیں گے۔‘‘
’’لیکن مجھے ان پتھریلی چٹانوں سے پانی ملنے کی اُمید نہیں۔‘‘ میں نے سرنگ کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
’’اور ہم زیادہ نیچے بھی نہیں پہنچے ہیں کہ پانی نکل آئے۔‘‘
’’ہا ہا ہا۔۔۔ بھتیجے تمھیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ہم سطح سمندر سے دس ہزار فٹ نیچے ہیں۔‘‘
’’کیا۔‘‘ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ’’اگر ایسا ہوتا تو درجہ حرارت ۸۰ ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا اور ہم جل کر راکھ ہوچکے ہوتے۔‘‘
’’یہ دیکھو! دلاور چچا نے کچھ کہنے کے بجاے مجھے اپنا حساب دکھایا۔۔۔ سائنسی نظریات کی دھجیاں میں نے بکھرتے ہوئی دیکھیں جو زمین سے متعلق کی گئی تھیں۔ وہ سب سائنسی نظریات غلط تھے۔ بالکل غلط۔۔۔
*۔۔۔*
اگلی صبح ہم پھر تازہ دَم ہو کر اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر یہ راستہ بھی ایک ایسی جگہ پر ختم ہوا جہاں سے چار مختلف سرنگیں نکل رہی تھیں اور ہمیں ان سرنگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔
’’اب ہم کس راستے سے جائیں۔‘‘ میں نے پراُمید لہجے میں پوچھا کہ جواب آئے گا ’’واپس‘‘۔۔۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
چچا جان نے کسی تاخیر کے بغیر مشرقی سرنگ کا انتخاب کیا اور ہم اس سرنگ کی تاریکی میں ڈوب گئے۔
اوپر، نیچے، ٹیڑھی میڑھی، گول گول گھومتی ہوئی اس سرنگ نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ شام ۶ بجے ہم تھک ہار کر سوگئے اور اگلے دن پھر تازہ دم ہو کر اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ اس دوران ہم نے بہت کم ہی کوئی بات کی ہوگی۔ ابھی ہم تین گھنٹے ہی چلے ہوں گے کہ میں ٹھٹک کر رک گیا۔
’’تم تین گھنٹے میں ہی تھک گئے۔‘‘ چچا دلاور نے طنزاً کہا۔
’’نہیں! میں قطعاً نہیں تھکا۔۔۔ آپ دیکھیے کہ ہم نیچے جانے کے بجاے مستقل اوپر جارہے ہیں اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو باہر نکل جائیں گے۔‘‘
چچا جان کو شاید لگ رہا تھا کہ اُنھوں نے مشرقی سرنگ کا انتخاب کرنے میں غلطی کی ہے لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے، میں حیران ہو کر ان سے پیچھے رہ کر راستہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے فوراً ان کے ساتھ ہولیا۔
اس سے آگے ہو کر میں پھر ایک جگہ رکا۔
’’اب کیا ہوا۔‘‘ چچا جان نے بے زاری سے کہا۔
’’آپ کو چٹانوں میں کوئی بدلاؤ سا محسوس نہیں ہورہا کیا۔‘‘ میں نے کہا۔
’’چٹانیں کچھ مٹی کی لگ رہی ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے کیلشیم کی ان چٹانوں کو۔‘‘
’’خیر جناب آگے بڑھو۔‘‘ اُنھوں نے میری بات مکمل طور پر نظر انداز کردی۔
’’حیرت ہے۔۔۔ لیکن ہم اس جگہ پر ہیں جہاں دنیا کا پہلا پودا اور پہلا جانور موجود تھا۔‘‘
مجھے کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آرہی تھیں۔ میں نے کیلشیم سے بنی ہوئی چند اشکال اور خول اٹھائے۔
چچا جان نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہاں آکر چچا جان نے اعتراف کیا کہ اُنھوں نے غلط سرنگ کا انتخاب کیا ہے لیکن وہ اسی راستے آگے بڑھنے کے لیے اب بھی پرعزم تھے۔
مصیبت یہ تھی کہ پانی تیزی سے ختم ہورہا تھا اور پانی کے ختم ہونے کا مطلب زندگی ختم ہورہی تھی۔ ہمارے پاس دو دن سے زیادہ کا پانی نہیں بچا تھا اور پانی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔
ہم لوگ سرنگ میں آگے ہی آگے کی جانب اپنی موت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جمعے والے دن رات کے وقت ہم نے بہت زیادہ پیاس محسوس کی۔ سرنگ میں چلتے ہوئے مجھے لگا کہ شاید بے چاری لالٹینوں کی روشنیاں مدہم ہورہی ہیں لیکن جب میرا ہاتھ دیوار سے لگا تو میں چونک پڑا۔
’’ارے یہ تو کوئلے کی کان ہے۔‘‘
’’ہاں کوئلے کی کان۔۔۔ کان کنوں کے بغیر۔‘‘ چچا دلاور کا جواب جلدی سے آیا۔
میں نے منھ بنالیا۔ ہم نے رات یہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح اُٹھ کر ہم نے غور سے اس سرنگ کا جائزہ لیا۔ یہ تقریباً ۱۰۰ فٹ کشادہ اور ۵۵ فٹ لمبی تھی۔ مجھے اس دوران بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔
تھوڑی ہی دیر میں اس بے چینی کی وجہ سمجھ میں آگئی۔ اس کان میں میتھین گیس موجود تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ ہمارے پاس جو لالٹینیں تھیں وہ بیٹری سے چلنے والی تھیں۔ اگر آگ سے چلنے والی ہوتیں تو ہم اب تک جل کر بھسم ہوچکے ہوتے۔ ہم جلدی سے اس جگہ سے آگے بڑھے۔۔۔ مجھے لگا کہ اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو شاید ایک ماہ تک بھی سرنگ پار نہ کرسکیں گے۔
وہ شاید ۶ بجے کے قریب کا وقت تھا۔ آخر کارہم ایک ایسی جگہ آگئے جو ایک کمرے کی مانند ہر طرف سے بند تھی۔
’’اُف یہ کیا۔۔۔‘‘ یہ لفظ ہم تینوں کے منھ سے ایک ساتھ نکلا۔
’’لگتا ہے ہم غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھے۔ ہمیں واپس انھیں سرنگوں تک جانا ہوگا۔‘‘ چچا دلاور بولے۔
’’ہاں اگر ہم زندہ بچ گئے تو۔۔۔ کیوں کہ کل پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا۔‘‘ میرے لہجے میں ترشی آگئی تھی۔
’’اور تمھاری ہمت بھی ختم ہوچکی ہے۔‘‘ چچا دلاور نے طنزاً کہا۔ اب میں کیا کہتا۔۔۔مجھے چپ ہونے میں ہی عافیت لگی۔
میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگر کوئلے کی کان اس وقت ہیرے کی بھی ہوتی تو میرے لیے ایک پیالے پانی سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ کچھ اور نہیں تو سو کر میں پانی سے متعلق خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔
اگلے دن ہم جلد ہی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیں ۴ سے ۵ دن لگیں گے واپسی اسی سرنگ تک پہنچتے ہوئے۔۔۔ جس کا انتخاب ہمارے اندازے کے مطابق غلط تھا۔ اب چچا جان نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ غلط سرنگ کا انتخاب کر بیٹھے ہیں۔
واپسی کے اس سفر میں ہم نے بہت ساری مشکلات برداشت کیں۔ ان تکلیفوں کا سامنا ہم تینوں کو کرنا پڑرہا تھا۔ داؤد مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس نے ان مشکلات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ میری اپنی حالت یہ تھی کہ پانی ختم ہوچکا تھا۔ جسم میں طاقت گویا بالکل ختم ہوگئی تھی اور کسی بھی لمحے ان پتھریلی چٹانوں پر ڈھیر ہوسکتا تھا۔ بالآخر ہم مشرقی سرنگ کے پاس پہنچ گئے لیکن مجھے یہی منزل لگ رہی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی میں نقاہت کے مارے بے ہوش ہوگیا۔ میری آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ چچا جان نے اپنے نرم بازوؤں میں مجھے تھام لیا ہو، ان کی بھرّائی ہوئی آواز سنائی دی۔
’’نالائق لڑکے!‘‘
میں نے بولنے کی کوشش کی کہ میں ٹھیک ہوں لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ کوئی مجھے پانی پلا رہا ہے۔ ایک آواز سماعت سے ٹکرائی۔
’’پیو میرے بچے پیو! یہ پانی اسی وقت کے لیے میں نے اپنی بوتل کے پیندے میں بچا کر رکھا تھا۔‘‘ یہ یقیناًچچا جان کی آواز تھی۔ ’’یہ آخری پانی ہے جو تم نے پی لیا۔‘‘
’’شکریہ چچا جان! دل کی گہرائیوں سے شکریہ!‘‘ میرے لبوں نے حرکت کی۔
’’میں نے کئی بار خود کو روکے رکھا اس پانی کو پینے سے۔‘‘ چچا جان نے بتایا۔
’’اب ہمارا پانی ختم ہے، ہمیں واپس اسنیفل جانا ہوگا۔‘‘ میں نے کہا۔
’’واپس جائیں۔‘‘ چچا جان نے خود کلامی نہیں بلکہ چِلّا کر کہا۔
’’ہاں! ہاں ہمیں واپس جانا ہے۔ ہمیں اب ایک لمحے یہاں نہیں رُکنا۔‘‘ میں نے بھی چِلاّ کر کہا۔
’’پیارے ارحم! کیا ان چند قطروں نے تمھیں ہمت نہیں بخشی کہ ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ میں تمھارے منھ سے کیا سن رہا ہوں۔ ہم کامیابی کے کنارے کھڑے ہیں اور اب ہم یہاں سے واپس نہیں جاسکتے۔‘‘
’’پھر تو ہمیں ذہنی طور پر خود کو موت کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔‘‘ میں نے چڑ کر کہا۔
’’تم اور داؤد واپس چلے جاؤ۔ میں تو اپنا سفر جاری رکھوں گا۔‘‘ چچا جان نے ضد کا دامن کَس کر پکڑا۔
’’آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟‘‘
’’ضد نہ کرو! جاؤ۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔‘‘
مجھے چچا جان کی اس کیفیت پر سخت حیرانی ہورہی تھی۔ میں نے داؤد کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھایا لیکن یہ کیا۔ داؤد تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔
’’داؤد۔‘‘ میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا لیکن اس نے نیچے کی طرف جانے والی سرنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ’’ماسٹر کے ساتھ جاؤں گا۔‘‘
’’کیا! تمھارا دماغ ٹھیک ہے۔ ماسٹر دیوانہ آدمی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ڈوب کر مرجائیں۔ داؤد کیا تم مجھے سن رہے ہو۔‘‘
میں داؤد کی خاموشی سے جھنجھلا اُٹھا۔ داؤد نے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی۔ میں نے اپنی ناکامی دیکھی تو زمین پر بیٹھ گیا۔
’’سنو ارحم! پرسکون ہوجاؤ! میری بات غور سے سنو۔‘‘
چچا جان نے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوگیا۔
’’پانی کی کمی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اپنے پورے سفر میں نے ہم نے پانی تلاش ہی نہیں کیا۔ اب ہم پانی تلاش کریں گے اور مجھے اُمید ہے کہ اب ہم ایک دن میں پانی تلاش کرہی لیں گے۔ کہو اب کیا کہتے ہو۔‘‘
’’ایک دن مزید۔۔۔ پھر۔‘‘ میں نے کہا۔
’’اگر ہم مقررہ وقت میں پانی تلاش نہ کرسکے تو ہم واپس آجائیں گے۔‘‘
چچا جان نے یقین دلاتے ہوئے کہا تو میں خاموش ہوگیا۔ مجھے معلوم تھا کہ چچا جان کے نزدیک اس سفر کی اہمیت کیا ہے اور وہ اتنی بڑی آفر کررہے ہیں۔ ان کی بات ایک دن کے لیے مزید مان لینی چاہیے ورنہ ہم واپس اس جگہ چلے جائیں گے جہاں سے ہمارا قلبی تعلق ہے یعنی زمین کی سطح پر۔
اب ہم نے دوسری سرنگ میں اُترنا شروع کردیا۔ یہ سرنگیں ذرا ٹھنڈی تھیں۔ شاید ابتدا میں یہ گرم رہی ہوں پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی۔۔۔ ماہر ارضیات کے لیے یہ چٹانیں کسی جنت کے پتھروں سے کم نہ تھیں۔ یہ وہ چٹانیں تھیں جنھیں پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا وقت ان چٹانوں کی ہئیت کو دیکھتے ہوئے گزارا۔
مشکلات اور پریشانیوں کو انگیز کرتے ہوئے ہم آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے کان پانی کی آواز سننے کے لیے کسی خرگوش کے کان کی مانند کھڑے تھے لیکن پانی کے چشمے کی آواز تو درکنار ایک قطرے کی آواز بھی اگر سنائی دی ہو۔ چلتے چلتے حالت اتنی دگرگوں ہوگئی کہ میں یکلخت زمین پر گر پڑا۔
اس وقت میرے منھ سے ایک ہی آواز برآمد ہورہی تھی۔
’’مدد۔۔۔ مدد۔۔۔ میں مررہا ہوں۔‘‘
*۔۔۔*
جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے پاس چچا دلاور اور داؤد کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ معلوم نہیں وہ سو رہے تھے یا مر گئے تھے۔ معلوم نہیں۔۔۔ اس وقت تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں انسانوں سے کئی ہزار میل دور ہوں۔ کسی وقت بھی سرنگ بیٹھ سکتی ہے اور ہمارا قیمہ بن سکتا ہے، کسی کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی تین سر پھرے آئے ہوں گے۔ موت قریب سے قریب تر نظر آرہی تھی۔
سناٹا ایسا چھایا ہوا تھا کہ جیسے کسی قبرستان کا منظر ہو۔ اچانک میں نے داؤد کو دیکھا وہ ہاتھ میں روشنی لیے جارہا تھا۔ ’’داؤد ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔‘‘ میں چلایا۔ ’’خدا کے لیے! ہمیں یوں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔‘‘ میری آواز بھرّانے لگی۔ ’’داؤد اگر تم ایک بہادر مرد ہو تو یوں نہ کرو، واپس آجاؤ۔‘‘
اگلے ہی منظر نے مجھے شرمندہ کردیا۔ داؤد باہر کی جانب نہیں جارہا تھا بلکہ وہ سرنگ میں نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یقیناًوہ پانی کی تلاش میں گیا ہوگا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ میں ایک دم شرمندہ ہوگیا۔ لیکن اس خاموشی میں کیا اس نے پانی کی آواز سن لی تھی؟
*۔۔۔*
اگلے ایک گھنٹے تک داؤد اوپر نہیں آیا تو میرے دل میں وسوسے آنے لگے۔ وہ ہمیں چھور کر کسی دوسرے راستے سے نہ نکل گیا ہو۔ میں جو وجہ سوچتا وہ پہلی وجہ سے بڑی ہوتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہوں۔
اچانک میں نے قدموں کی چاپ سنی۔ یقیناًیہ داؤد کے قدموں کی چاپ تھی۔ داؤد نے آکر چچا جان کو جگایا۔
چچا جان کسمسا کر اُٹھے: ’’خیریت۔‘‘
داؤد نے جذبات سے عاری مختصراً جواب دیا۔ ’’پانی‘‘
’’پانی!‘‘ میں حیرت سے اُچھل کر کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے مجھ پر وارفتگی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ میں خوشی سے اُچھل رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ افریقا کے قدیم جنگلات میں آج بھی جس طرح غیر تہذیب یافتہ لوگ جشن مناتے ہیں کچھ ایسی ہی کیفیت میری بھی تھی۔
ہم تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے کی جانب لپکے۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ہمیں پانی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔
’’بالکل شک نہیں! یہ یقیناًپانی ہے۔‘‘ میں خوشی سے چِلّایا۔
’’جی بھتیجے۔۔۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہوسکتا۔‘‘
پہلے تو ایسا لگا کہ آواز اوپر سے آرہی ہے۔۔۔ مزید غور کیا تو آواز پشت کی جانب دیوار سے آنے لگی۔ داؤد نے پانی کا صحیح اندازہ لگا یا اور کدال سے سوراخ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی سخت محنت کے بعد ۲ فٹ گہرا اور ۶ انچ چوڑا سوراخ ہوہی گیا۔
یہ انتظار جان لیوا تھا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پانی ہمارے لیے دنیا کی سب سے اہم شے بن گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی ہم سے پوچھتا کہ آپ کے نزدیک دنیا کی سب سے اہم چیز کیا ہے تو یقیناًہم کہتے۔۔۔ ’’پانی‘‘
داؤد نے آخری چوٹ لگا کر زور سے پانی کو خوش آمدید کہا۔ پانی کا ریلا پوری قوت سے اندر کی طرف آیا، جیسے باہر سے کسی نے زور سے پانی کو اندر دھکیلا ہو۔
یکلخت مجھے داؤد کی چیخ سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں چیخا۔ میری توجہ مکمل طور پر پانی پر تھی۔ میں نے چہکتے ہوئے پانی میں تیزی سے ہاتھ ڈالا اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ خوف ناک چیخ مار کر واپس نکال لیا۔
’’یہ اُبلتا ہوا گرم پانی ہے۔‘‘ میں نے دلبرداشتہ ہو کر کہا۔ میرے لہجے میں درد کو محسوس کرتے ہوئے چچا دلاور نے تسلی دی۔
’’فکر نہ کرو! یہ جلد ٹھنڈا ہوجائے گا۔‘‘
اور واقعی تھوڑی دیر بعد پانی ٹھنڈا ہوگیا۔ پینے کے لیے بہت سارا پانی جمع ہوچکا تھا۔ ہم ندیدوں کی طرح پانی پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ذائقے کو نظر انداز کرتے ہوئے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ کچھ دیر بعد جب طبیعت سیر ہوگئی تو لگا پانی میں معدنیات کا ذائقہ ہے۔
’’ہم شاید وہ لوگ ہیں جنھوں نے یہ پانی دریافت کیا۔ ہمیں اب اس ندی کو کوئی نام دینا چاہیے۔‘‘ چچا جان گویا ہوئے۔
’’ میرے خیال میں داؤد نے اسے دریافت کیا ہے، اسی کے نام پر اس کا نام رکھا جانا چاہیے۔‘‘
یہ بالکل درست ترکیب تھی ہم نے داؤد کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اس ندی کا نام ’’داؤد ندی‘‘ رکھ دیا۔
ہم نے اپنے مشکیزے پانی سے لبالب بھر لیے۔۔۔ لیکن ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں کہ نیچے کی جانب سفر کرتے ہوئے اب پانی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کررہا تھا اور ہم جب چاہتے اس پانی سے فائدہ اُٹھاسکتے تھے۔
’’اب یقیناًکوئی رکاوٹ نہیں کہ ہم اس سفر کو جاری نہ رکھ سکیں۔‘‘ میں مسکرا کر بولا تو چچا جان اور داؤد مسکرا اُٹھے۔ داؤد کو مسکراتے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ورنہ سنجیدگی ہر وقت اس کے چہرے پر پھیلی رہتی تھی۔ ہم نے آرام کیا۔
اگلے دن ہم اُٹھے اور اپنا سفر شروع کیا۔ مختلف پر پیچ، ٹیڑھے میڑھے، اوپر نیچے کے راستوں پر سفر کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے، راستے میں ایک کنواں بھی آیا، جسے ہم نے رسیوں کی مدد سے عبور کیا۔ پانی ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا اس لیے پانی کا مسئلہ اب نہیں رہا تھا۔ درمیان میں ایک ہموار سڑک بھی آئی تھی جس پر ہم کئی میل چلتے رہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق ہم سطح سمندر سے ۲۱ میل نیچے تھے یعنی سمندر ہمارے اوپر تھا۔ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات ہرگز نہ تھی۔
آخر کار ہم ایک غار نما کمرے میں آگئے، جہاں ہم نے آرام کرنا تھا۔ اگلی صبح ہم اُٹھے۔ یہ ایک بڑا غار تھا جو کسی بڑے ہال کی طرح لگ رہا تھا۔ داؤد ندی پاس ہی بہہ رہی تھی۔ اب پانی پینے میں کوئی دِقت نہیں تھی۔
چچا جان اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے، مجھے بیدار ہوتے دیکھا تو کہنے لگے۔ ’’میں واپسی کے لیے نقشہ بنا رہا ہوں تاکہ ہمیں مشکلات پیش نہ آئیں۔‘‘
’’اوہ تو کیا آپ یہ کرسکتے ہیں؟‘‘ میں حیران ہوا۔
’’برخوردار! میں پہلے بھی کئی نقشے ترتیب دے چکا ہوں اور میں نے اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ہم نے اب تک ۲۵۰ میل سفر طے کیا ہے۔‘‘
چچا جان نے کہا اور اپنی ڈائری میں حساب لکھنے لگے۔
’’ہم تقریباً ۵۰ میل نیچے کی جانب گئے ہیں۔‘‘
’’۵۰ میل!‘‘ میں چلایا۔ ’’سائنسدانوں کے مطابق یہ زمین کی سخت سطح ہے جسے Crust کہتے ہیں اور سائنس دانوں کے مطابق یہاں کا درجۂ حرارت ۱۵۰۰ ڈگری ہونا چاہیے۔‘‘
’’ہونا چاہیے؟‘‘ میرے بچے! تم دیکھو اگر ۱۵۰۰ ڈگری درجۂ حرارت ہوتا تو یہ چٹانیں پگھل چکی ہوتیں اور ہم بھلا یہاں جل کر کباب نہ بن جاتے۔ عموماً ایسے کیسوں میں حقائق سائنسی نظریات پر غالب آجاتے ہیں۔‘‘
’’ہم اب کہاں ہیں، زمین کی سطح سے زمین کی گہرائی ۸۰۰،۴ میل ہے اور ہم نے ان ۸۰۰،۴ میں سے ۵۰ میل کا سفر ۲۰ دنوں میں مکمل کیا ہے۔‘‘
’’ہاں تم ٹھیک جارہے ہو۔ آگے بڑھو۔‘‘
’’اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے مرکز تک پہنچنے کے لیے ہمیں ۵ سال کا عرصہ لگے گا۔‘‘
’’اگر ہم افقی سمت میں سفر کے بجاے عمودی سمیت میں سفر کریں تو شاید ہمیں بہت کم وقت لگے۔ شاید بہت ہی کم۔‘‘ چچا جان نے بات آگے بڑھائی۔ میں حیرت سے ان کا منھ تکنے لگا۔ وہ میری حیرت کا مطلب سمجھ گئے۔ ’’ٹھیک ہے! تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سرنگ سیدھی نیچے نہیں جاتی۔‘‘
میں مزید کچھ کہہ کر اُنھیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو خاموش رہا۔ ہم نے اپنے سفر کو غیر معمولی طور پر تیز کرلیا۔ نیچے جانے کے لیے ہمیں رسی کا استعمال کرنا پڑا۔ ان چند دنوں میں کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی لیکن اگلے ہی دن جو واقعہ پیش آیا میں زندگی بھر اسے نہیں بھول سکتا۔ میں جب بھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو اندر تک کانپ جاتا ہوں، خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔
*۔۔۔*
۱۷؍ اگست کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم اب مستقل نیچے کی جانب سفر کررہے تھے۔ ہمارے اوپر چٹانیں، براعظم، ممالک، شہر اور ڈھیر سارے انسان تھے۔ میں لالٹین لیے رہنمائی کی غرض سے آگے آگے تھا۔ میرے پیچھے چچا جان اور پھر داؤد بھی چلا آرہا تھا۔
میں مستقل اوپر چٹانوں کی ساخت پر غور کررہا تھا اور اپنے اس کام میں اتنا منہمک تھا کہ درحقیقت مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میں چچا جان سے کوئی بات کرنے لگا۔۔۔ لیکن جواب نہ ملنے پر میں نے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں سٹپٹا گیا۔
داؤد اور چچا جان غائب تھے۔ مجھے لمحے کے ہزارویں حصے میں اندازہ ہوا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ شاید میں بہت تیز چل رہا ہوں۔۔۔ یا پھر یہ ہوسکتا ہے کہ وہ سستانے کے لیے رُک گئے ہوں۔ میں فوری پر جو سوچ سکتا تھا میں نے سوچا۔
’’بہتر یہ ہے کہ میں اُنھیں ڈھونڈنے کے لیے واپس جاؤں۔‘‘ میں بڑبڑایا۔
میں اُلٹے قدموں واپس ہونے لگا۔ یہ میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں غصے کے عالم میں دیواروں کو گھورنے لگا۔ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
’’چچا جان۔۔۔ داؤد۔‘‘ میں حلق پھاڑ کر چِلّایا۔۔۔ لیکن آواز دیواروں سے اپنا سر ٹکراتی ہوئی واپس آگئی۔۔۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اب میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔
میں سچ مچ ڈر گیا۔ خاموشی سے خوف آنے لگا۔ اپنے خوف کو بھگانے کے لیے میں نے زور زور سے بڑبڑانا شروع کردیا۔
’’میں اُنھیں ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی دوسری سڑک موجود نہیں۔‘‘
میں چلتا رہا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ان دونوں کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ ایسے غائب ہوئے جیسے تھے ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ میری بڑبڑاہٹ بھی ختم ہوئی۔ میں داؤد ندی کی رہنمائی میں چل رہا تھا۔ اب میں واپس سرنگ میں آیا۔ میں نے پانی کے لیے ندی میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ہاتھ سخت دُھول اور مٹی والی زمین سے ٹکرائے۔ داؤد ندی غائب ہوچکی تھی۔
*۔۔۔*
دنیا کی کوئی بھی زبان میری اس حالت کو بیان کرنے سے قاصر تھی۔ میں سیکڑوں میل زمین کے نیچے ایک قبر میں موجود تھا۔ بھوک پیاس سے ہونے والی موت مجھے بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ ہم جب واپس جانے کے لیے مڑے تو داؤد ندی نے دوسری جانب سرنگ میں بہنا شروع کردیا ہوگا۔ میں غلطی سے راستہ کھو بیٹھاتھا۔ چچا جان اور داؤد آگے جاچکے ہیں یا پھر واپس چلے گئے ہیں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔
’’میں کھو گیا ہوں۔‘‘ میں زور سے چِلّایا۔
میں اس وقت زمین کے اندر تھا اور یہ سرنگ بند ہوجائے تو یقیناًمیں اس کا وزن نہیں سہار سکتا۔ یہ صورتحال کسی بھی شخص کو پاگل کردینے کے لیے کافی تھی۔ یہاں کوئی انسان میری مدد کے لیے بھی نہیں آسکتا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر مجھے صرف ایک ہی ذات نظر آئی۔ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے زمین جیسی اربوں زمینیں بنائی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ اس رب کی بارگاہ میں اٹھادیے۔ زندگی میں اتنی رقت آمیزدعا میں نے پہلی مرتبہ مانگی تھی۔ میرے دل کو سکون اور قرار مل گیا۔
میرے پاس ۳ دن کا کھانا اور پانی سے بھری ایک بوتل تھی۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرلوں گا لیکن مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نیچے جانے والا یا اوپر۔ بالآخر میں اوپر کی طرف چلنے لگا۔ میں نہایت محتاط انداز سے اس سرنگ تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے داؤد ندی الگ ہوئی اور میں راستہ کھو بیٹھا۔ مجھے اُمید تھی کہ میں داؤد ندی کو ڈھونڈ لوں گا یا پھر سطح زمین پر پہنچنے کا راستہ۔۔۔ میں نے ہلکا سا کھانا کھایا اور اوپر کی جانب چلنا شروع کیا۔ میں کوشش کررہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے راستہ تلاش کرسکوں لیکن راستہ اوپر کی جانب سے بند تھا۔ میرے ہاتھ چٹان سے جا ٹکرائے۔
یہ اُمید بھی اب ختم ہوگئی تھی۔ میں مرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس جگہ میرا مقبرہ بننے والا ہے۔ میں نے بلند آواز سے رونا چاہا لیکن میرے حلق سے جانوروں جیسی آواز نکلی، اچانک میرے ہاتھ سے لالٹین گر گئی، روشن کم ہوئی، مزید کم اور بالآخر روشنی ٹمٹماتے ہوئے بند ہوگئی۔
ایک وحشیانہ انداز میں چیخ میرے حلق سے نکلی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مجھ پر جنون طاری ہوگیا۔ میں نے نکلی ہوئی چٹانوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر باہر نکلنا چاہا۔۔۔ میرا جسم سے رگڑ لگنے کے باعث خون رسنے لگا۔ جیسے ہی تھوڑی سی جگہ نکلنے کی نظر آئی، میں بھاگنے لگا۔ گھنٹوں بھاگتا رہا لیکن دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔
جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو کسی انبار پر لیٹا پایا۔ آنسو میرے گال سے گر رہے تھے اور جسم سے خون بھی رس رہا تھا۔ ’’میں اب تک مرا کیوں نہیں۔‘‘ میں حیران تھا۔
اس احساس نے کہ میں ابھی زندہ ہوں مجھے ایک نئی اُمید دی۔ میں دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں ملنے لگا۔ مجھے بہت گہرائی سے ہلکا سا شور سنائی دیا۔ یہ آواز اوپر چٹانوں سے آرہی تھی۔
میں غور سے ان آوازوں کو سننے لگا تاکہ ان آوازوں کی اصل وجہ دریافت کرسکوں کہ آیا یہ گیس نکلنے کی آواز ہے یا چٹانیں گرنے کی۔یہ آواز چٹان کی دوسری جانب سے آرہی تھی۔ ’’ارے نہیں۔۔۔‘‘ میں حیرت سے چِلّا اُٹھا۔ یہ آواز گیس یا چٹانوں کی ہرگز نہیں تھی۔ یہ تو چچا جان کی آواز تھی۔ یہ یقینی طور پر ان ہی کی آواز تھی۔ میں نے دوبارہ غور سے آواز سنی۔
’’مدد۔۔۔ مدد۔۔۔ چچا جان۔۔۔ میں یہاں ہوں۔‘‘ میں رینگتا ہوا دیوار کے قریب آیا۔ میری آواز کافی نحیف تھی۔ کئی سیکنڈ گزر گئے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ یہ چند سیکنڈ مجھے کئی صدیوں پر محیط لگے۔
’’ارحم! میرے بچے۔۔۔ یہ تم ہو۔‘‘
’’جی۔۔۔‘‘ میں بمشکل بولا۔
’’تم کہاں چلے گئے تھے؟‘‘
’’میں کھو گیا تھا۔‘‘
’’اور تمھارا لیمپ؟‘‘
’’وہ خراب ہوچکا ہے۔‘‘
’’لیکن اپنی ندی۔۔۔ داؤد ندی۔‘‘
’’وہ مجھ سے کھو گئی۔‘‘
’’ارحم گھبراؤ نہیں! ہم جلد تمھیں تلاش کریں گے۔‘‘
’’چچا مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔‘‘میں چِلّایا۔ ’’مجھ سے باتیں کرتے رہیں۔‘‘
’’اپنی ہمت بڑھاؤ ارحم۔‘‘ چچا جان کی آواز آئی۔ ’’ہم تمھیں اس سرنگ میں اوپر اور نیچے تلاش کررہے ہیں۔‘‘
’’مجھے خوف تھا کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔‘‘ میں نے کہا۔ سرنگ میں آواز نکلنے کے بعد اجنبی ہوجاتی تھی۔ اصل میں ہم ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔
’’ہم آگے چل کر اوپر نیچے سے راستہ تلاش کررہے ہیں۔‘‘ چچا جان کی آواز آئی۔ ’’ہوسکتا ہے ہم کئی میل آگے چل کر راستہ تلاش کرپائیں۔ تم گھبرانا نہیں۔‘‘
’’کئی میل۔‘‘ یہ الفاظ مجھے کسی مرثیے کے بول لگ رہے تھے۔
میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے لیکن میں چل نہ سکا۔ میں نے خود کو گھسیٹا۔۔۔ لیکن بہت دیر ہوچکی تھی۔ اچانک ڈھلوان شروع ہوگئی تھی اور میں گرنے لگا۔۔۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے چٹان کو پکڑنا چاہا، اپنے آپ کو پیچھے کی جانب دھکیلا بھی۔۔۔ لیکن یہ سب بے سود ثابت ہوا۔
میں گرا اور گرتا چلا گیا۔ گہری اور اندھیری سرنگ میں۔
میرا سر کسی چٹان سے لگا اور پھر آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔
*۔۔۔*
جب میں دوبارہ ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ایک سخت بستر پر لیٹا پایا۔ میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ میری سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔
’’یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔‘‘ یقیناًیہ میرے چچا کی آواز تھی۔ میرے لبوں پر زندگی بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسی لمحے داؤد بھی ہمارے قریب آگیا۔
’’ہم کہاں ہیں چچا جان۔‘‘ میں نے پوچھا۔ ’’یہ کیا دن ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ’’رات کے ۱۱ بج رہے ہیں آج ۱۹؍ اگست اور اتوار کا دن ہے۔ تمھارے سر پر پٹی بندھی ہے اور تمھیں نیند کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمھیں باقی تفصیلات صبح بتاؤں گا۔‘‘
میری آنکھیں یہ سنتے ہی دھیرے دھیرے بند ہونے لگیں ۔۔۔یعنی میرا ایڈونچر ۴ دنوں پر مشتمل تھا۔
اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ غار کا فرش نرم تھا۔ چمکتی ہوئی ریت بھی موجود تھی۔ غار میں قوس و قزح کی طرح روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غار میں کوئی ٹارچ یا لالٹین موجود نہیں تھی۔ یقیناًیہ روشنی باہر کہیں سے آرہی تھی۔ میں نے تصور میں ہوا چلنے کی آوا زسنی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے پانی ٹکرا رہا ہو، یہ ایک ناممکن بات تھی۔ کیوں کہ ہم زمین سے ۱۰۰ میل نیچے تھے۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ یا کوئی بڑی دراڑ آئی ہے جو سمندر کو کھینچ کر یہاں تک لائی ہو۔ ان ہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا جان آتے دکھائی دیے۔
’’صبح بخیر ارحم۔‘‘ اُنھوں نے کہا۔ ’’اب تم بہتر دکھائی دے رہے ہو۔‘‘ داؤد تمھارے زخموں کا علاج کرتا رہا۔ اس نے ایک خاص دوا تیار کی ہے تمھارے زخموں کے لیے اور سنو! تمھارے زخم بہت تیزی سے بھر رہے ہیں۔ داؤد حیرت انگیز آدمی ہے۔ اب تم کھانا کھانا پسند کروگے؟‘‘
میں بھوکا تھا اس لیے میں نے انکار نہیں کیا اور کھانا کھانے لگا۔ چچا جان نے بتایا :’’ تم جس طرح گرے تھے، تمھارا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں! اب ہم الگ نہیں ہوں گے۔‘‘
کیا ہم زمین کی سطح پر نہیں ہیں۔‘‘ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ’’یقیناًنہیں۔‘‘
’’پھر تو میں واقعی پاگل ہوچکا ہوں، میں سورج کی روشنی دیکھ رہا ہوں اور لہروں کی آواز سن رہا ہوں۔‘‘
چچا جان میری بات سن کر مسکراے۔ ’’تم جو دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔‘‘
شاید میں حیرت سے مرجاتا۔ اُنھوں نے مزید کہا۔ ’’میں مزید وضاحت نہیں کرسکتا۔۔۔ تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔‘‘
’’چلیں۔‘‘ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔
’’ایک منٹ! کیا تم بہتر محسوس کررہے ہو؟ اگر ہاں تو خود کو سمندری سفر کے لیے تیار رکھو۔‘‘
’’سمندری سفر؟‘‘ میں چِلّایا۔
’’بس تم تیار رہو۔۔۔ اور شاید کشتی کا یہ سفر کافی لمبا ہو۔‘‘
میں دوڑتا ہوا غار سے نکلا۔ میری آنکھیں چندھیاگئی۔ کئی دنوں سے سورج کی روشنی کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرلیں اور پھر جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ایک حیرت انگیز نظارہ میرے سامنے تھا۔
’’سمندر۔۔۔ سمندر۔‘‘ میں چِلّایا۔
’’جی۔۔۔ مرکزی سمندر۔‘‘ اسے یہ نام میں نے دیا۔ چچا جان مسکرا کر بولے۔
سمندر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنا دور جتنا میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ یہ سب کچھ نہایت حیرت انگیز تھا۔ اب تک ہماری تحقیق سے بالکل مختلف چیز۔۔۔ ایک نئی دنیا۔
میں اور چچا جان ساحل کے ساتھ چل رہے تھے۔ آزاد اور خوش گوار ہوا میں سانس لے رہے تھے۔ اندھیری سرنگ میں ہم نے ۴۷ دن گزارے تھے۔ نیچے ایک جگہ خوبصورت آبشار گر رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی سے یہ آبشار گر کر سمندر میں غائب ہوجاتی۔ تقریباً ۵۰۰ گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک موڑ کاٹا۔ یہ ایک بڑا اور گھنا جنگل تھا۔ میں دنیا کے تقریباً ۲۰۰۰ کے قریب درختوں کی پہچان کرسکتا تھا لیکن یہ درخت عجیب سے تھے اور آج تک میں نے اس قسم کے درخت نہیں دیکھے تھے۔
’’ارے باپ رے۔۔۔ یہ جنگل تو مشروم(کھمبی) کا جنگل ہے۔ کھمبیوں پر مشتمل یہ درخت چالیس فٹ لمبا اور اس کی چھڑیاں بھی تقریباً ۴۰ فٹ تھیں اور یہ حیرتیں ہماری جان لے رہی تھیں۔
’’یہ نمونے جو تم دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے باغوں میں پودوں کی صورت میں ہے۔ جب کہ یہاں طاقتور درختوں کی صورت میں اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے۔‘‘ چچا جان نے ایک اندازہ لگایا۔
’’اگر پودوں کے حوالے سے یہ ایک اندازہ ٹھیک ہے تو کیا جانوروں کے حوالے سے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا؟‘‘ میں نے اردگرد بے چین سے نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔
’’ہاں میرے بچے! وہ ہڈیاں دیکھو جو کنارے پر پڑی ہیں۔ اتنی طاقتور جیسے درخت کے تنے ہوں۔‘‘
میں نیچے بیٹھ کر غور سے ایک جبڑے کا معائنہ کرنے لگا جو ڈائنا سورس سے ملتے جلتے جانور کی داڑ معلوم ہورہی تھی۔‘‘
’’آپ نے صحیح کہا۔‘‘ میں چِلّایا۔
’’یہ طاقت ور جانور زندہ تھے اور پھر زیر زمین سمندر کے کنارے مر گئے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ او میرے خدا۔۔۔ ہوسکتا ہے کسی چٹان کے پیچھے ان میں سے کوئی جانور زندہ ہو۔‘‘
میں نے ارگرد دیکھا۔۔۔ مگر اس ویران ساحل پر کوئی زندہ جاندار ہمارے سوا نظر نہ آیا۔
ساحل پر گھومتے گھومتے ہم کافی تھک چکے تھے۔ اگر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو ہمیں آرام کرنا ہوگا، ہم نے سوچا اور واپس غار کی طرف بڑھ گئے۔
اگلی صبح ہم تازہ دَم ہو کر اُٹھے۔ سمندر کے پانی سے غسل کیا۔ ناشتہ کرکے ہم دوبارہ ساحل پر چلنے لگا۔
’’ہم کہاں ہیں اور زمین سے ہمارا کتنا فاصلہ ہے۔‘‘ میں نے پوچھا۔
’’ہم اسنیفل پہاڑی سے ۱۰۰۰ میل اوپر اور زمین کے ۱۱۰ میل اندر ہیں۔‘‘ چچا جان نے بتایا۔
’’کیا ہم واپس جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔‘‘
’’واپس‘۔‘ چچا جان مجھے گھور کر بولے اور پھر چِلّا کر کہا: ’’اپنا سفر ختم کیے بغیر؟‘‘
’’لیکن ہم مرکزِ سمندر تک پہنچ گئے ہیں۔‘‘ میں نے دبی آواز میں کہا۔
’’میرے خیال سے ہم نے ۱۵۰ میل ہی پار کیا ہے۔‘‘
’’اور ہم اسے کیسے پار کریں گے۔‘‘ میں نے کہا۔۔۔ کیوں کہ یہاں کشتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
’’کیا آپ کا ارادہ اسے تیر کر پار کرنے کا ہے۔‘‘ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ چچا جان نے کوئی جواب دیے بغیر ایک جانب اشارہ کیا۔
’’وہ دیکھو۔‘‘ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں یہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔
*۔۔۔*
میرے سامنے ایک کشتی کھڑی تھی، جسے داؤد نے صنوبر اور چیڑ کے درخت کی لکڑیوں سے بنایا تھا۔ مختصر سامان کے ساتھ اس قسم کی کشتی بنانا واقعی ایک ہنر تھا۔ داؤد کی قدر دل میں مزید بڑھ گئی۔ ۱۳؍ اگست کی صبح ۶ بجے ہم نے اپنا سامان کشتی پر لادا اور اس وسیع سمندر میں سفر کرنے لگے جس کا دوسرا کنارہ فی الحال دور دور تک نظر نہیں آرہا تھا۔ داؤد پیشہ ور ملاحوں کی طرح اسے چلا رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد داؤد نے مچھلیاں پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ مچھلی پکڑنے والا کنڈا اس کے سامان میں موجود تھا۔ اس میں چارا لگا کر داؤد نے اسے سمندر میں ڈال دیا۔
’’داؤد بھی پاگل ہوگیا ہے۔ اس سمندر میں بھلا مچھلی کہاں سے آئی۔‘‘ میں نے سوچا لیکن دوسرے لمحے ہی داؤد نے رسی ایک جھٹکے سے کھینچی۔ کنڈے میں ایک مچھلی تڑپ رہی تھی۔ اس مچھلی کے متعلق میں نے پڑھا تھا۔ یہ ہماری دنیا میں ناپید ہوچکی ہے۔ اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بینائی نہیں ہوتی۔
دوسرے دن سمندر میں کافی تیزی آگئی تھی۔ ہم اس سفر سے بور ہورہے تھے۔ اوپر سے جب چچا جان نے بتایا کہ ہمیں یہ سمندر ۱۵۰ میل پار کرنا تھا لیکن ہم تین مرتبہ اتنا سفر طے کرچکے ہیں، لیکن اب تک کوئی کنارا نظر نہیں آیا۔
دو دن گزر گئے۔ دلچسپ اور پرجوش مرحلہ تو اس وقت شروع ہوا جب سمندر کی گہرائی معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ داؤد نے کدال کو رسی کے ساتھ باندھ کر اسے پانی میں پھینکا۔ کدال واپس آئی تو وہ ادھ کھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کدال پر پنجوں یا غالباً دانتوں کے نشان تھے۔
’’یہ یہ کس چیز کے نشان ہیں۔‘‘ میں گھگھیا کر بولا۔
’’دانتوں کے۔‘‘ داؤد کی طرف سے سپاٹ جواب آیا۔
’’اُف خدایا۔‘‘ میں کانپ اُٹھا۔ میں اتنا بڑا اور خطرناک جانور دیکھنا ہرگز پسند نہیں کروں گا اور وہ بھی اتنا مضبوط کہ جو فولاد کو کھاسکے۔
شام کے وقت میں سوگیا۔ اُٹھا تو پانی میں ایک عجیب سی ہلچل دیکھی۔ دوسرے لمحے میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہاں کوئی ہیبت ناک جانور تھا جو کسی چھپکلی کی مانند نظر آرہا تھا اور پھر اچانک ہی ایک مگرمچھ جیسا جانور بھی نظر آیا۔ وہ دونوں تختے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ ہمیں کچا نگل جاتے، اُنھوں نے آپس میں لڑنا شروع کردیا۔ میں نے بندوق چلانی چاہی تو داؤد نے مجھے روک دیا۔ یہ بندوق ان کا بال بھی بیکا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ جانور ابتدائی رینگنے والے جاندار تھے۔ اس میں ایک تو مچھلی نما چھپکلی کی مانند تھا جبکہ دوسرا دیو ہیکل جانور کسی اژدھے کی طرح لگ رہا تھا جس پر سمندر کچھوے کی طرح کا سخت خول تھا۔
ان دونوں جانوروں میں کئی گھنٹوں تک انتہائی خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب وہ ہلتے تو پانی زور سے ہماری کشتی کے تختے سے ٹکراتا اور کشتی ڈولنے لگتی۔ دونوں جانور لڑتے لڑتے لہروں میں غائب ہوگئے۔ کافی دیر بعد اژدھے کی طرح لگنے والا جانور کا سر پانی میں تیرتا نظر آیا۔ وہ یقیناًشکست کھا چکا تھا۔
سمندری مچھلی یا چھپکلی کہاں غائب ہوئی؟ کیا وہ دوبارہ ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے آنے والی ہے؟
*۔۔۔*
یہ جمعہ ۲۱ ؍اگست کا دن تھا۔ ہم اب تک ۸۰۰ میل سے زیادہ سفر طے کرچکے تھے۔ ہم نے اپنی پوزیشن کا اندازہ لگایا تو ہم بالکل برطانیہ کے نیچے تھے۔
آہستہ آہستہ آسمان گہرے بادلوں سے بھرنے لگا۔ ہوا میں تیزی آگئی اور یہ تیزی اس قدر شدید تھی کہ اگر کوئی مجھے ہاتھ لگاتا تو اسے کرنٹ ضرور لگتا۔ رات کے وقت طوفان کے آثار واضح ہوئے۔ ہوا نے ہمیں تختے پر لیٹنے کے لیے مجبور کردیا تھا۔
’’ہمیں بادبان کو نیچے کرلینا چاہیے؟‘‘ میں چلایا۔
’’نہیں نہیں!‘‘ انکل نے فوراً منع کیا۔ ’’ہوا کو ٹکرانے دو۔ اس طرح ہم منزل کے مزید قریب ہوجائیں گے۔‘‘
چچا جان کی بات سن کر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ طوفان ہم سے زور سے ٹکرایا۔ تختہ کبھی بہت زیادہ بلند ہوتا اور کبھی تیزی سے نیچے آتا۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں داؤد کے صرف لمبے بال ہی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے۔
طوفان کی دل دہلا دینے والی آوازیں ہماری جان لینے کے در پے تھیں۔ بجلی کی چمک سے ہم ایک دوسرے کے خوفزدہ چہرے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھکڑ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے۔
طوفان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ ہنوز دو دن تک وقتاً فوقتاً جاری رہا، تھکن کی وجہ سے ہمارا بُرا حال تھا لیکن داؤد اس موقع پر بھی بالکل تازہ دَم لگ رہا تھا۔
رات ۱۲ بجے کے قریب طوفان نے اتنی شدت اختیار کرلی کہ ہمیں خود کو اپنی اس چھوٹی سی کشتی کے ساتھ باندھنا پڑگیا۔ اچانک آگ کا آدھا سرخ اور آدھا سفید گولا تقریباً ہمیں چھوتا ہوا ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ میری آنکھیں اس تاریکی میں روشنی دیکھ کر چندھیا سی گئیں، حالت یہ تھی کہ کان بادلوں کی گرج کی وجہ سے بہرے ہوگئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ساری زمین بارود کا ڈھیر ہے جو دھماکے سے پھٹتا جارہا ہے۔
اچانک ایک شور سا بلند ہوا، یہ شور سمندر میں چٹان کے ٹوٹنے کی آواز تھی جس سے لہریں پیدا ہوئیں اور لہروں نے ہمیں ساحل پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اچھال دیا۔ ہمارا تختہ یعنی کشتی تباہ ہوچکی تھی۔ اس موقع پر بھی داؤد ہمیں ٹوٹے ہوئے تختے سے نکال کر محفوظ جگہ لے آیا۔ ۳ دن گزر گئے تھے۔ اب ہم سونا چاہتے تھے۔ ہم نے کھانا کھایا اور لمبی تان کر سوگئے۔
*۔۔۔*
اگلے دن موسم خوشگوار تھا۔ طوفان کے آثار ختم ہوچکے تھے۔ ’’تم بہت زور سے خراٹے لیتے ہو۔‘‘ انکل نے مسکرا کر مجھے صبح بخیر کہتے ہوئے کہا۔
’’جی۔۔۔‘‘ میں نے جھینپ کر کہا۔ پھر اپنی جھینپ مٹانے کے لیے پوچھا: ’’کیا ہمارا سفر اب مکمل ہوچکا ہے؟‘‘
بالکل نہیں! اب ہم زمین کے مرکز کی طرف بڑھنے کے لیے خشکی کا راستہ اختیار کریں گے۔‘‘
’’اور ہم واپس کیسے جائیں گے۔‘‘ مجھ پر واپسی کی دھن سوار تھی۔ ’’جب ہم زمین کے مرکز پر پہنچ جائیں گے تو کوئی نیا اور آسان راستہ باہر نکلنے کے لیے تلاش کرلیں گے، یا پھر ہم۔۔۔؟ چچا جان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔
’’یا پھر۔۔۔؟‘‘
’’یا پھر ہم اسی راستے سے واپس جاسکتے ہیں۔ داؤد نے کھانے کا انتظام کرلیا ہے۔ کیا تمھیں داؤد پر اعتماد نہیں ہے۔‘‘ چچا دلاور جلدی سے بولتے چلے گئے۔
’’میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے چٹان کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف دیکھا جہاں داؤد نے خشک مچھلی، نمکین گوشت، پانی اور ضروری آلات سنبھال کر رکھے تھے۔ صرف ہماری بندوقیں نہیں تھیں۔ وہ ہم کھوچکے تھے۔
’’اور ہماری کشتی؟‘‘ میں نے چچا جان کی طرف دیکھا۔
’’میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔‘‘ چچا جان نے کہا۔ ’’تمھیں شاید یقین نہیں آرہا کہ ہمارا تعلق اوپر کی دنیا سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے حساب کے مطابق ہم ۹۰۰ میل سمندر کی سطح کے نیچے سفر کرچکے ہیں۔ ہم ۲۷۰۰ میل اسنیفل سے دور ہیں اور غالباً ہم اس وقت Mediterrranean سمندر کے نیچے ہیں۔‘‘
چچا جان نے کہا اور جیب سے اپنا قطب پیما نکالا۔ ایسے جیسے ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ انھوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ چچا جان نے قطب پیما کی سوئی کو دیکھا اور اچانک ان کے چہرے کا رنگ سفید ہوگیا۔
’’کیا مسئلہ ہے؟‘‘ میں نے کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے قطب پیما لے لیا، اب چونکنے کی باری میری تھی۔ سوئی کا اشارہ شمال کی جانب تھا، جب کہ ہم اسے جنوب خیال کررہے تھے۔
طوفان کے دوران ہوا مخالف سمت پر چل پڑی تھی اور جو کنارے ہم تین سے چار دن پہلے چھوڑ چکے تھے اب دوبارہ وہیں کھڑے تھے۔
*۔۔۔*
اس وقت ہماری حالت کچھ ایسی ہورہی تھی کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کررہا تھا۔
چچا دلاور بھی جھنجھلا چکے تھے۔ ’’قسمت میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، لیکن میں بھی اب واپس نہیں جاؤں گا۔‘‘
داؤد نے دوبارہ تختہ بنایا اور سامان اس پر لادا۔ چچا جان نے میری کیفیت بھانپ لی تھی، اس لیے انھوں نے سفر فوراً شروع نہیں کیا بلکہ ہم نے اس ساحل کی سیر کرنے کا سوچا۔
ساحل عجیب و غریب نمونوں سے بھرا ہوا تھا۔ چچا جان کو ایک انسانی کھوپڑی بھی ملی اور تھوڑی دیر میں ہمیں یہاں قبرستان ہونے کا اندازہ ہوا۔ شاید کسی زلزلے نے یہاں موجود لوگوں کو زندہ دفن کردیا تھا۔ کیا واقعی یہاں انسان آباد تھے۔ کیا اب تک کوئی یہاں رہ رہا ہوگا؟ ہم نے سامنے موجود ایک جنگل کی طرف رخ کیا۔ جنگل میں چیڑ، صنوبر اور صندل کے دیوقامت درخت بھی موجود تھے۔ اچانک میں نے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا ہاتھی دیکھا۔ وہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ کوئی معمولی پتے ہوں۔ اس قسم کے اور بھی ہاتھی نظر آئے۔
چچا جان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن میں نے التجا کرکے انھیں روکا۔ چچا جان نے میری بات مان لی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہاں ہمیں ایک بڑی جسامت کا آدمی دکھائی دیا۔ فیل بان لگ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً ۱۲فٹ ہوگا۔
’’چچا جان یہاں سے چلیے۔ مجھے خطرے کی بو آرہی ہے۔‘‘ میں نے چچا جان کو کھینچتے ہوئے کہا۔ چچا جان نے میری تجویز سے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہم الٹے قدموں لوٹ آئے۔ چچا جان نے یہاں سے مختلف نمونے جمع کرنے شروع کردیے جو ہم واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔
یہاں ہم نے حیرت انگیز طور پر اپنی دنیا کا بنا ہوا ایک خنجر دیکھا یہ ہمیں ۳۰۰۰ سال پرانا لگا۔ ایک دیوار پر ہم نے الف اور خ لکھا ہوا دیکھا تو ہم اچھل پڑے۔ حیرت انگیز بات تھی۔ کیا احمد خانی یہاں تک آچکا تھا۔ اس نے اپنا نام یہاں کیوں لکھا۔ اس کا مطلب یہاں سے راستہ اندر کی جانب جاتا ہے۔ یہ ایک غار تھا۔ میں نے اور چچا جان نے غار کا جائزہ لیا۔ غار اندر سے بند تھا یا بند ہوگیا تھا۔ اس غار کو کھولنے کا منصوبہ بنایا جانے لگا۔
’’ہم کدال سے اسے توڑسکتے ہیں۔‘‘ چچا جان نے تجویز پیش کی۔
’’میرا خیال ہے یہ عام ہتھیاروں سے نہیں ٹوٹے گی۔ ہمیں بارود استعمال کرنا ہوگا۔‘‘
’’شاندار۔‘‘ انکل نے جوش میں تالی بجائی۔ ’’چلو ہوجاؤ شروع۔‘‘ آدھی رات تک ہم نے چٹان میں ایک بڑا گڑھا کھودا اس میں بارود بھرا اور ایک لمبی سی رسی لی اور غار سے باہر آکر اسے چھوڑ دیا، ہم تھک چکے تھے۔ اس لیے لیٹتے ہی نیند آگئی۔
صبح اٹھتے ہی ہم نے کشتی کو کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تاکہ وہ دھماکے سے محفوظ رہ سکے۔
’’کیا تم تیار ہو۔‘‘ چچا جان نے میری طرف دیکھ کر کہا۔
’’بالکل تیار۔‘‘ میں نے جواب دیا۔ میرا دل اس وقت دھک دھک کررہا تھا۔
’’پھر آگ لگادو۔‘‘
میں نے رسی کو آگ لگائی اور کنارے کی طرف بھاگ کر کشتی پر کود گیا۔ ہم تینوں کشتی پر بیٹھے دھماکے کا انتظار کرنے لگے۔
۱۔۔۔۲۔۔۔۳۔۔۔۴۔۔۔ چچا جان کی آواز سنائی دی اور پھر دھماکا ہوگیا۔ سمندر کا پانی تیزی کے ساتھ غار کی طرف بڑھا۔۔۔ ساتھ ہی ہماری کشتی بھی غار میں پانی کے ساتھ داخل ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم ایک خوفناک کنوئیں میں گرتے جارہے ہیں۔ بالآخر ہم رک گئے۔ پانی نیچے بڑھتا جارہا تھا ہم آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ پانی بہت تیزی سے بھر رہا تھا۔ ہماری رفتار بڑھنے لگی، ہم تختے سمیت اب اوپر ہی اوپر سفر طے کرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم کسی گلاس میں بند ہوں اور جس میں کوئی پانی بھر رہا ہے۔ اس نے اپنے اطراف دیواریں دیکھیں۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے ہم کسی لفٹ پر سوار ہوں، اب ہمیں اپنی موت کا انتظار تھا۔ یقیناًایک وقت آئے گا جب اوپر راستہ بند ہونے کی وجہ سے پانی ہمیں کچل کر رکھ دے گا۔ ایک خوفناک موت ہماری منتظر تھی۔۔۔ نہیں بلکہ ہم موت کے منتظر تھے۔
*۔۔۔*
ہم خطرناک حد تک تیز رفتاری کے ساتھ اوپر جارہے تھے۔ چچا جان نے میرے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ لیے تھے۔
’’ارحم! زندگی کی امید رکھو۔‘‘
اچانک درجہ حرارت مجھے بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔
’’اگر ہم ڈوبے نہیں تو جل کر ہی مر جائیں گے۔‘‘ میں چلایا۔
کئی گھنٹے گزر گئے، گرمی کی شدت جب بہت زیادہ بڑھی تو ہم نے کپڑے اتارنے شروع کردیے۔
’’کیا ہم آگ میں زندہ کھڑے ہیں۔‘‘ میں چلایا۔ ’’سرنگ کی دیواریں گرم اور سرخ ہوچکی ہیں اور سنیے چچا جان گرج دار دھماکے کی آوازیں آرہی ہیں۔
چچا جان! آپ سن رہے ہیں ہم کسی زلزلے کے زد میں آگئے ہیں۔ ہمارے اردگرد دیواریں چٹخ رہی ہیں اور ہمارے نیچے پانی ابل رہا ہے۔‘‘
تم غلط ہو ارحم!‘‘ یہ زلزلے سے کہیں زیادہ ہے۔‘‘
وہ زور سے بولے۔ ’’یہ لاوا ہے۔‘‘
’’کیا لاوا۔۔۔؟‘‘
’’یعنی ہم آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر ہیں جو پھٹنے و الا ہے اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔‘‘
’’کیا۔۔۔؟‘‘ میں نے انھیں گھور کر دیکھا۔ ہم جلتے اور ابلتے ہوئے لاوے کے کنوئیں میں ہیں۔ ہم زمین کے ساتھ تپ رہے ہیں، ہمارے اردگرد گرم آگ کے بگولے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔‘‘
’’ارحم! کیا تم دنیا کی روشنی دیکھنے کے خواہش مند ہو؟ ہمارے لیے زمین کے اندر سے نکلنے کا یہ اچھا موقع ہے۔‘‘
میں نے اوپر کی سمت دیکھا، مدہم سی روشنی نظر آئی۔ جیسے دیوار میں معمولی سا سوراخ ہو تو روشنی اندر کی جانب آتی ہے۔ یہ مدہم روشنی آہستہ آہستہ تیز اور بڑی ہوتی جارہی تھی، اچانک ہماری کشتی (جو اب صرف تختہ رہ گئی تھی) رک گئی۔
’’لگتا ہے ہم کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے؟‘‘
نہیں بھتیجے پریشان مت ہو، آتش فشاں پہاڑ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ رکتا ہے، چلتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔‘‘
تختہ ایک بار پھر اوپر کی جانب حرکت کرنے لگا اور اس بار اتنی تیزی سے حرکت ہوئی کہ مجھے صرف یہ یاد رہا کہ تختہ گول گول گھوم رہا تھا۔ دھماکے ہورہے تھے۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ داؤد کا چہرہ تھا جو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہم کسی گولی کی مانند دہانے سے نکلے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خلا میں تیر رہے ہوں۔ اس کے بعد ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔
*۔۔۔*
جب میں نے آنکھیں کھولیں تو داؤد مجھے میری بیلٹ سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے انکل کو تھامے ہوئے تھا۔ میں نے اپنے اردگرد دیکھا۔ ہم کسی اونچی چوٹی پر تھے۔ اگر داؤد ہمیں نہ بچاتا تو شاید ہم نیچے گر چکے ہوتے۔ چچا جان خود کو زمین پر پا کر خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہم جزیرے پر نہیں تھے۔ یہ جگہ برف باری سے بھری ہوئی تھی۔ پہاڑ سے نیچے سر سبز زیتون اور انجیر کے درخت نظر آرہے تھے۔ اس کے پیچھے ہمیں ایک چھوٹی بندرگاہ نظر آرہی تھی۔ بہت سارے گھر تھے اور یقیناًجو کشتیاں ہمیں نظر آرہی تھیں وہ مچھیروں کی تھیں۔
میں نے اب آگے کا سوچنا شروع کردیا تھا۔ اگر ہم زندہ تھے تو یہ کسی معجزے سے ہرگز کم نہیں تھا۔ یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔
ہم دو گھنٹے مسلسل چلتے رہے۔ اب ہمارے سامنے ایک خوبصورت ملک پھیلا ہوا تھا۔ ہم کہاں تھے؟ اس سوال کا جواب اس وقت ہم تینوں جاننے کے خواہش مند تھے۔
زیتون، جنگلی انگور اور انار کے درختوں سے ندیدوں کی طرح پھل ہم نے توڑے اور کھانے شروع کیے۔ تازہ، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ زیتون کے درختوں کی اوٹ سے ایک بچے نے جھانکا۔
’’ارے۔۔۔ وہ۔۔۔ اب ہم معلوم کرسکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں؟‘‘ بچہ ہمیں دیکھ کر خوفزدہ لگ رہا تھا اور بھلا خوف زدہ کیوں نہ ہوتا۔ ہم تینوں آدھے کپڑوں میں، الجھے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے جو موجود تھے۔
چچا جان نے پہلے جرمن زبان میں اس پہاڑ کا نام پوچھا جس سے ہم نکلے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔
پھر انگریزی میں پوچھا، جواب ندارد۔
فرنچ زبان میں بات کی تو پھر خاموشی، اس دفعہ چچا جان نے اتالوی میں پوچھا تو لڑکے نے جلدی سے جواب دیا۔
’’اسٹروم بولی‘‘ یہ کہہ کر لڑکا پلٹا اور تیزی سے بھاگا۔
’’واہ۔۔۔ بہت خوب ہم Maditerranean کے مرکز کی سطح پر آگئے ہیں اور تیز آتش فشاں Etna کے ذریعے باہر نکل آئے۔ واہ واہ۔۔۔ بہت خوب۔‘‘ میں چہکا۔
آہ۔۔۔ کیا سفر تھا، بہت ہی شاندار، مشکلات سے بھرپور۔۔۔ لیکن باکمال سفر۔۔۔ میری زندگی کا یادگار ایڈونچر۔۔۔ ہم ایک آتش فشاں سے داخل ہوئے اور دوسرے آتش فشاں سے باہر نکلے۔ اثنا اور اسنیفل پہاڑیوں کا فاصلہ تقریباً ۳۶۰۰ میل دور ہے۔
اس جزیرے کے لوگ توہم پرست تھے۔ وہ ہمیں بھوت سمجھنے لگے اور ہمیں ایک پرانی سی کشتی دے کر اپنی جان چھڑالی۔
ایک مچھیرے سے ہم نے کپڑے اور کھانا لیا اور مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے اپنے ملک پہنچے۔ اس وقت تک ہماری یہ کہانی جرمنی، ہالینڈ، امریکا، کینیڈا وغیرہ میں پھیل چکی تھی۔
لوگوں کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ہم زمین کے مرکز سے ہو کر آئے ہیں۔
ہم اپنے ساتھ کچھ نمونے بھی لائے تھے جس نے ہماری کہانی پر یقین دلانے میں لوگوں کی مدد کی۔ یہ نمونے ہم نے ملک کی ایک مشہور لیبارٹری میں جمع کرادیے۔
داؤد سے جدا ہونے کا وقت آچکا تھا۔ وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتا تھا۔ داؤد نے کئی بار ہماری جان بچائی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم اس کے احسان مند تھے۔
ہم نے اس سفر سے بہت شہرت حاصل کی تھی۔ چچا جان کی خدمات کا اعتراف دنیا بھر میں کیا گیا۔ وہ واقعی اس کے حقدار تھے۔ ہم پر فلمیں بنائی جانے لگی تھیں۔
میں نے اب مستقل طور پر چچا جان سے فیض اٹھانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔
اس ایڈونچر کے بارے میں جب کبھی سوچتا ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوجاتی ہیں۔
اے اللہ! تیرا شکریہ۔۔۔ تو نے ہمیں عافیت میں رکھا۔
*۔۔۔*