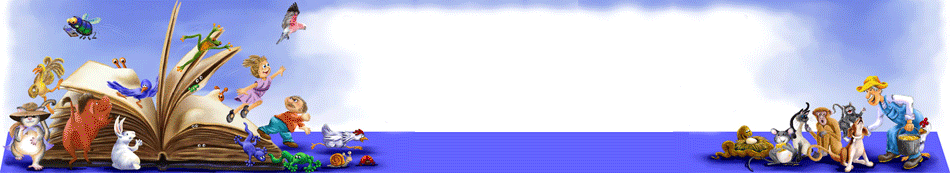ہم شکل ، ہم راز
شکیل صدیقی
۔۔۔۔۔
ایک دل چسپ اور حیرت انگیز کہانی سلطان احمد کی زبانی
میری آنکھ اچانک کھل گئی۔
میں نے تپائی کی طرف رکھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ساڑھے تین بجے تھے۔ میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں اور دوڑ لگانے قریبی پارک میں جاتا ہوں۔ آج وقت سے پہلے آنکھ کھلنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔
خواب گاہ کا ایر کنڈیشنر ہلکی آواز سے چل رہا تھا اور سوئچ بورڈ پر لگا ہوا چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ خواب گاہ میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اس لیے کوئی چیز واضح انداز میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے۔ لہٰذا باہر کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔
’’سو جاؤ میاں سلطان ،کوئی خاص بات نہیں ہے۔‘‘ میں نے کہا اور کروٹ بدل لی۔
’’ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔‘‘
’’گھر۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔‘‘
ایک عجیب سے آواز آئی اور میں چونک گیا۔ غالباً اسی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی مگر گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے میں اس سے واقف نہیں ہو سکا تھا۔
وہی آواز پھر ابھری تو میں نے انداز لگایا کہ کوئی شخص راہ داری میں چل رہا ہے اور یہ اس کے قدموں کی آواز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ایک پاؤں میں تکلیف ہے، اس لیے وہ ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اتنی رات کو میری خواب گاہ کی طرف کون آسکتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز خواب گاہ کے دروازے پر آکر ختم ہوگئی اور پھر دروازے کا ہینڈل گھومنا شروع ہوا۔ میں نے چوں کہ بٹن دبا کر اسے اندر سے لاک کیا ہوا تھا، اس لیے وہ کھل نہ سکا۔ باہر کھڑے ہوئے آدمی نے دو تین بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ قدموں کی چاپ پھر بائیں طرف والی کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ اس کھڑکی میں شیشے کے پٹ تھے ،اس لیے شیشہ توڑ کر وہ شخص اندر آسکتا تھا۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگنے لگا۔
میرے سرہانے بجلی کی گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا جسے دبا کر میں کسی ملازم کو بلا سکتا ہوں۔ ملازموں کے کوارٹر حویلی کے احاطے ہی میں ہیں اور عمارت سے ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ انھیں سونے کے کمرے تک پہنچنے میں دو منٹ لگتے۔ بہر حال دو منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنی دیر میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے فرش پر کھڑے ہو کر شب خوابی کے لباس کی ڈوریاں کسیں اور چپل پہن کر دائیں کھڑکی کی طرف گیا۔ پردہ ہٹا کر میں نے ملازموں کے کوارٹر کی طرف دیکھا۔ وہاں سناٹا اور اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو گھنٹی کی آواز وہاں تک پہنچ گئی مگر ملازم گہری نیند سو رہے تھے یا پھر کسی نے گھنٹی کا تار کاٹ دیا تھا۔
یکایک ایک ہلکا سا چھناکا ہوا اور بائیں طرف کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس طرح سے چوری چھپے داخل ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اب مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانی تھی۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے اپنی پیشانی پسینے سے چپچپاتی محسوس کی۔ پیشانی پر ہاتھ پھیر کر میں نے خود کو دلاسا دیا اور بٹن دبا کر تالا کھول لیا۔ اس دوران ایک اور چھنا کا ہوا اور کھڑکی کا دوسرا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے چٹخنی گرا دی۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور پردہ اڑ کر ایک طرف کو ہو گیا۔ اوپری چھجوں پر چوں کہ تیز روشنی کا بلب لگا ہوا تھا اور کھڑکی کے قریب کی سب چیزیں واضح طور پر نظرآری تھیں، اس لیے مجھے وہ آدمی صاف دکھائی دیا جس کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اندر آنا چاہتا تھا۔
وہ لمبا، مضبوط جسم اور ڈراؤنے چہرے والا تھا۔ اس کے جسم پر معمولی سی شلوار قمیص تھی۔ چہرے پر نمایاں چیز اس کی مونچھیں تھیں جنھیں اس نے راج پوتوں کی طرح کونوں سے بل دے کر اٹھا رکھا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں اس وقت بد حواس تھا اور میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کے باجود میں نے اس کی کلائی پر زخم کا ایک لمبا سا نشان دیکھ لیا۔ وہ اسی ہاتھ کی کلائی تھی جس میں اس نے خنجر پکڑ رکھا تھا۔
اس شخص نے جیسے ہی اپنا پیر کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھا اور کمرے میں آنا چاہا، میں نے دروازہ کھولا اور راہ داری میں چلا گیا۔ میں دو قدم بڑھا تو مجھے اپنی چپلوں کی سٹر پٹر، سٹر پٹر سنائی دی۔ یہ آواز سن کر کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ پھر میرے جلاد صفت ماموں گلزار احمد کا کمرا تو نزدیک ہی تھا۔ آواز سن کر وہ بھی جاگ سکتے اور میری خبر لے سکتے تھے، اس لیے میں نے چپلیں وہیں اتاریں اور دوڑ لگا دی۔
راہ داری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر میں نے چکر دار زینے اترنے شروع کر دیے۔ زینے کشادہ تھے اور دائیں طرف ریلنگ بھی لگی تھی۔ میں جب نیچے پہنچا تو میں نے اوپری راہ داری سے ’’دھپ۔۔۔دھپ۔۔۔دھپ۔۔۔‘‘ کی آوازیں آتی سنیں۔ میرا کمرا خالی پا کر شاید وہ آدمی میرے پیچھے آرہا تھا۔ میں نے نچلی راہ داری میں پہنچ کر اس دروازے کی طرف دوڑ لگا دی جو دالان میں کھلتا تھا۔ وہاں اندھیرے کا راج تھا مگر میں اندازے سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ لکڑی کی وزنی بلی ہٹا کر میں نے دروازہ کھولا اور صحن میں چلا گیا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ صحن میں گھاس تھی جس پر شبنم پڑ چکی تھی۔ میں ننگے پاؤں تھا۔ اس لیے گھاس کی ٹھنڈک میرے جسم میں جذب ہونے لگی۔ مجھے بے اختیار چھینک آگئی۔ لگاتار دو بار چھینکنے کے بعد مجھے یقین ہوگیا کہ اس شخص سے پیچھا نہیں چھڑا سکوں گا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے مگر پھر مجھے اپنے پیارے اور وفادار ریگی کا خیال آیا۔ ریگی ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا بلکہ اس کی تکا بوٹی کر سکتا تھا۔
’’ریگی۔۔۔ رگی۔‘‘ میں نے دائیں طرف منہ کر کے اسے آواز دی۔
جواب میں ’’غاؤں غاؤں‘‘ کی سی بھاری آواز آئی، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ریگی میرے پاس کیوں نہیں آرہا ہے؟ وہ رات بھر بہت مستعد اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ میرے اور حویلی کے مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتا۔ وہ جرمن نسل کا شیفرڈ ہے۔ میں نے کئی بار اسے خرگوشوں اور بلیوں پر جھپٹتے اور انھیں چیرتے پھاڑتے دیکھا ہے۔ وہ حقیقت میں میرا محافظ تھا۔
’’ ر یگی، ریگی۔۔۔ یہاں آؤ۔‘‘ میں نے انگریزی میں کہا۔
میں اپنے کتے سے انگریزی میں باتیں کرتا تھا۔ وہ میری باتوں کا جواب اسی زبان میں نہیں دے پاتا البتہ بھوں بھوں اور کوں کوں کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کرتا تھا لیکن اس وقت وہ درد ناک آوازیں نکال رہا تھا۔ دوسری بار بھی جب اس نے ’’غائوں غاؤں‘‘ کر کے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو میں دوڑ کر اس کی طرف گیا۔ ریگی میرا پیارا ریگی کروٹن کے ایک پودے کے قریب لیٹا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ احاطے پر جو تیز قوت والی روشنیاں لگی تھیں ان کی وجہ سے لان کا وہ حصہ روشن تھا۔ مجھے ریکی کے منھ کے قریب بہت سارا خون پڑا دکھائی دیا! ایک لمحے کے لیے تو میں سناٹے میں رہ گیا۔ پھر میرا دل چاہا کہ میں دھاڑیں مار کر رونے لگوں۔ ریگی میرا پانچ سال کا دوست تھا۔ میرا ہم درد، میرا رفیق اور غم گسار سب ہی کچھ وہی تھا۔ میں نے اپنی سسکیوں کو منھ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ،مگر آنکھوں پر بھلا کیسے پہرا بٹھاتا؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے اور ریگی پر گرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ ریگی کو زہر دیا گیا اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ قاتل حویلی میں داخل ہو تو اسے ریگی کے نوکیلے دانتوں اور تیز دھار پنجوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔
یہ مجھ پر تیسرا قاتلانہ حملہ تھا۔ میں اس صورت میں وہاں کیسے رک سکتا تھا جب اس حویلی کے درو دیوار میرے دشمن ہو رہے تھے؟ ضروری تو نہیں تھا کہ قاتل چوتھی بار بھی ناکام رہتا۔ آئندہ وہ کام یاب ہو جاتا تو میں دنیا سے کوچ کر جاتا۔
دالان کا دروازہ چر چرایا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آگیا۔ یقینا قاتل وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے ریگی کو دم توڑتی حالت میں چھوڑا اور پھاٹک کی طرف بھاگا۔ بڑا پھاٹک بند تھا۔
پھاٹک اسی وقت کھلتا تھا جب کاریں اندر آتی یا باہر جاتی تھیں۔ پھاٹک پر متعین دربان فجر کے وقت مجھے مستعد ملتا تھا اور جب میری کار پھاٹک کے قریب پہنچتی تھی تو میں پھاٹک کھولتا تھا۔ ڈرائیور ملازمین کے کوارٹر میں رہتا تھا اور منھ اندھیرے مجھے لارنس گارڈن تک پہنچا یاکرتا تھا جہاں میں صبح کی دوڑ لگاتا اور ہلکی ورزش کیا کرتا تھا مگر آج تو میں اپنے وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ گیا تھا اس لیے دربان جاگتا جیسے ملتا؟
میں نے اس کے کیبن میں جھانک کر دیکھا تو وہ اپنے اسٹول پر لڑھکا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی بندوق ایک کونے میں پڑی تھی اور وہ کیبن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پڑا تھا۔اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گہری نیند میں تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔
میں نے اسے آوازیں دیں اور ہلایا جلایا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ مجبوراً میں نے اس کی جیبیں ٹٹولیں۔ چابیوں کا گچھا مجھے اس کے پتلون کی دائیں جیب سے مل گیا۔ جس سے نہ صرف یہ کہ میں نے بغلی دروازہ کھول لیا بلکہ اسے باہر سے مقتل بھی کر دیا۔ جب میں حویلی سے دور ہو رہا تھا تو مجھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس میں گھسٹتے ہوئے پاؤں کی ’’گھر۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر‘‘ بھی شامل تھی۔ قاتل کے پاؤں سلامت ہوتے تو میں اس سے بچ نہ پاتا اور اس کے قابو میں آجاتا۔ میری جان اس لیے محفوظ رہ سکی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان تھا اور اسے میری موت منظور نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ قاتل لنگڑا تھا اوربھاگ کر مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا۔
حویلی سے سڑک تک پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میری اجڑی ہوئی حالت اور میرے جسم پر شب خوابی کا لبادہ دیکھ کر ہر شخص شبہ میں پڑ سکتا ہے۔ خیال آیا کہ گلبرک کے علاقے اور پھر لاہور شہر میں میرے سیکڑوں دوست ہیں۔ میں انھیں اپنا واقعہ سنا کر مدد لے سکتا ہوں مگر پھر بات ماموں گلزار کے کانوں تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتی اور میں دوبارہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔
یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی کہ اگر میں نے اس حالت میں سفر کیا تو میرا راز کھل جائے گا، اس لیے مجھے کسی دوست کی مدد لینی چاہیے۔ میرے قریبی دوست وحید کا بنگلہ تھوڑے فاصلے پر تھا مگر میں وہاں جا کر سب کو چونکانا نہیں چاہتا تھا۔
وحید بھی میری طرح صبح کی دوڑ کا شوقین تھا، اس لیے میں اس پارک کی طرف چلا گیا جہاں وہ دوڑ لگانے آتا تھا۔ میں اس حصے میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہوگیا جہاں کاریں پارک کی جاتی تھیں۔ وحید پندرہ منٹ بعد وہاں آیا۔ جب وہ کار سے اتر کر پارک کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے سیٹی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر اشارے سے اسے قریب بلایا۔وہ نڈر اور بے خوف لڑکا تھا۔ میرے قریب چلا آیا پھر حیرت سے پلکیں جھپکا کر بولا:
’’ارے سلطان تم! یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟‘‘
’’بس بھائی! کچھ نہ پوچھو آج جو گنگ کے لیے کچھ جلدی اٹھ گیا تھا۔‘‘
’’ پھر شب خوابی کے لباس میں یہاں کیوں چلے آئے؟ ویسے بھی تم یہاں نہیں آتے۔ تم تو لارنس گارڈن جاتے ہو؟‘‘
’’میں ذرا جلدی میں تھا۔‘‘ میں نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کے سامنے کیا بہانہ بناؤں؟ وہ میرا ہم درد بھی تھا اس لیے اس سے باتیں کرتے وقت میری آواز بھرا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو!
’’تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟‘‘ اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر کہا۔
میں نے ہار ماننے والے انداز میں کہا: ’’او کے! میں بعد میں بتا دوں گا۔ پہلے میرے لیے ایک جوڑا کپڑے اور کچھ رقم کا بندو بست کر دو۔ میں۔۔۔‘‘
وہ بولا: ’’ہاں، کہو خاموش کیوں ہو گئے؟ تم کافی پر اسرار لگ رہے ہو دوست۔‘‘
وحید کو سائنس سے بہت دل چسپی تھی۔ شاید اس لیے اس کی سوچ بھی گہری تھی۔ ہم دونوں مل کر انسان کے غائب ہونے پر تجربات کر رہے تھے۔ اسکول کی سائنس لیبارٹری میںاور وحید کے بنگلے کے تہ خانے میں بھی۔ ہم لوگوں کو ضمنی طور پر کام یابی حاصل ہو چکی تھی۔
میں نے کہا: ’’میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم گاڑی لے کر اپنے گھر جاؤ اور جو چیزیں میں نے مانگی ہیں انھیں لے کر یہیں آجاؤ۔‘‘؎ ’’اوہ! اتنا پر اسرار معاملہ ہے؟‘‘
’’جاؤ بھی اللہ کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ ہر معاملے میں تمھارا ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔‘‘
’’یہ تم کہہ رہے ہو سلطان؟‘‘ اس نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔
’’ہا ں میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں سے دفع بھی ہو جاؤ۔‘‘ میں نے پریشانی میں اسے کار کی طرف دھکیلا:
’’ا ور سنو ایک جوڑی جوتے بھی لیتے آنا۔ تمھارے جوتے میرے آجائیں گے۔‘‘
اس نے اپنے شانے ہلائے اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرے سر کے پچھلے حصے پر دو سینگ نکل آئے ہوں۔ پھر اس نے سر ہلایا اور اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔
وہ دس پندرہ منٹ میں میرے لیے سب چیزیں لے آیا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی اس لیے مجھے وہ وقفہ طویل معلوم ہوا۔ وحید کے کپڑے مجھے کچھ ڈھیلے معلوم ہوئے مگر اس میں کوئی ہرج نہیں تھا۔ میں نے کپڑے پہننے کے بعد وحید کے گال تھپ تھپائے اور محبت سے کہا:
’’اچھا میرے دوست! اب میں چلتا ہوں۔ تمھارا شکریہ۔‘‘
’’کہاں جارہے ہو؟ چلو میں پہنچا دوں۔‘‘
’’ کسی خاص جگہ نہیں جارہا ہوں۔ آج اسکول میں ملاقات ہوگی۔‘‘
’’ یقین نہیں آتا۔‘‘ اس نے کہا۔
اس نے مجھے ایک ہزار رپے دیے جو میں نے قبول کر لیے۔ میں اسے حیران، پریشان، سوالیہ نشان چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ آگے جاکر میں نے کئی بار مڑ کر دیکھا کہ کہیں وحید میرا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔
زمیں مجھ پر تنگ اور آسماں مجھ پر نامہربان تھا، اس لیے اس شہر، اس ملک یا پھر اس دنیا سے کہیں دور چلا جانا چاہتا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ ہو۔ کوئی رفیق، کوئی عزیز،کوئی ہمد رد نہ ہو۔
کراچی اور لاہور کے درمیان کئی سو میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اتنی دور چلا جاؤں تو ممکن ہے میں اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا یہ کوئی اچھا حل نہیں تھا۔ یہ صرف ایک فرار تھا، وقتی نجات تھی، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ میں کوئی مناسب فیصلہ کر لیتا۔ میں ایک کم زور اوربے حوصلہ لڑکا ہوں۔ اچھی کتا بیں اور اچھی تعلیم بھی مجھ میں حوصلہ اور ہمت نہیں پیدا کر سکی، اس لیے کہ میرا ماحول بہت خوف ناک سا ہے۔ ماحول کا بھی انسان پر گہرا اثر پڑتا ہے۔
کراچی پہنچنے کے لیے ہوائی سفر کرنا تھا یا پھر ریل کے ذریعہ سے جانا تھا۔ میں ائیر پورٹ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر بھی مجھے چھپ چھپا کر رہنا تھا۔ میں نے کتابوں کی ایک دکان پر جاکر تازہ اخبار اٹھایا اور اس میں ریلوے کے اوقات دیکھے۔ شالیمار ایکسپریس کو چھے بجے صبح روانہ ہونا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے تیسرے درجے کا ٹکٹ لیا اور ریل کے آنے پر اس میں سوار ہو گیا۔ دھکم پیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور مجھے ایک سیٹ مل گئی۔ میں نے اخبار کھول کر اپنے سامنے کر لیا،تاکہ اگر میری تلاش میں حویلی سے آدمی روانہ ہو چکے ہوں تو انھیں نظر نہ آؤں۔ میری گھبراہٹ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی اور ہر گزرنے والا لمحہ مجھے ڈس رہا تھا۔ ذہن میں اس وقت انتشار تھا، خیالات کی یلغار تھی۔ اگر ریل تھوڑی دیر بعد نہ چل پڑی ہوتی تو شاید میں اتر پڑتا۔
’’چھک۔۔۔چھک۔۔۔چھک۔۔۔چھکا چھک۔۔۔‘‘ ریل کے پہیے پٹری پر دوڑنے لگے اور پلیٹ فارم پر موجود تمام چیزیں تیزی سے پیچھے جانے لگیں۔ میرا پیارا شہر لاہور مجھ سے بچھڑ رہا تھا۔ میری امی، میرے ماموں، میرے چچا اور میرے دوست ،میرے چاہنے والے اور مجھ سے نفرت کرنے والے سب ہی مجھ سے جدا ہو رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس جدائی پر خوب آنسو بہاؤں اور چیخ چیخ کر روؤں، مگر میں نے ضبط کر لیا، دل کو سمجھا لیا۔
میں سلطان احمد، حشمت احمد مرحوم کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری پرورش بالکل شاہ زادوں کی طرح کی تھی۔ ایک روز حادثے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی کار جب شاہدرہ کے قریب ایک پل کو طے کر رہی تو اچانک دائیں طرف مڑ کر ریلنگ سے ٹکرائی اور پھر دریا میں جاگری۔ اتنی بلندی سے گرنے پر ابا جی کو بہت چوٹیں آئیں اور انھوں نے ہسپتال جاکر دم توڑ دیا۔
کافی عرصے بعد کسی نے ،شاید چچا رحمت نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حادثاتی موت نہیں مرے بلکہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں ۔ کسی بد خواہ نے جان بوجھ کر ان کی کار کا بریک ڈھیلاکر دیا تھا تاکہ جب وہ کسی بھری پری سڑک پر سے گزرتے ہوئے سامنے آنے والی کسی گاڑی سے بچنے کے لیے بریک لگائیں تو کار نہ رکے اور وہ کسی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائیں۔
حادثہ اس طرح پیش نہیں آیا جیسے کہ ان کے دشمنوں نے سوچ رکھا تھا لیکن بہر حال وہ حادثے سے دو چار ہو گئے اور یوں میری دنیا اندھیری ہوگئی۔
ابا جی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ کہتے تھے:
’’سلطان! میں تمھیں بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے وطن کے آسمان پر جگمگائو اور علم کی روشنی پھیلاؤ۔ انجینئر، ڈاکٹر یا صنعت کار تو اپنے بچوں کو سب ہی والدین بنانا چاہتے ہیں مگر میں تمھیں سائنس داں بنانا چاہتا ہوں میرے لعل! تم میری یہ خواہش پوری کرو گے نا؟‘‘
’’ہاں ضرور۔ میں ڈاکٹر عبدالسلام یا سلیم الزماں صدیقی بنوں گا اور اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔‘‘ میں ان کے گلے میں بانہیں ڈال کر جواب دیتا۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ساتویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس وقت تو بچوں کو ابتدائی سائنس پڑھائی جاتی ہے اور تجربے گاہ میں نہیں لے جایا جاتا مگر مجھ میں سائنس سے دل چسپی پیدا کرنے کے لیے ابا نے بہت سی باتصویر سائنسی کتابیں خرید دی تھیں۔ مسلمان سائنس دانوں کی بہت سی کتابیں اور تصویر یں لا کر دی تھیں جنھوں نے دنیا میں نام پیدا کیا تھا اور لوگوں کی سوچ کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ جیسے ابن باجہ، ابن الہیثم ، جابر بن حیان، الکندی اور البیرونی وغیرہ۔ ابا جی مغرب کی موجودہ ترقی کو مانتے تھے اور اس کے سائنسی کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف بھی کرتے، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عروج انھیں مسلمانوں ہی کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اگر بے راہ روی نہ اپنائی ہوتی اور تین سو سال سے ایک لمبی نیند میں مصروف نہ ہوتے تو آج ترقی ،کام یابی اور خوش حالی کا پرچم ان ہی کے ہاتھوں میں ہو تا۔
ابا جی یہ اور ایسی بہت سی باتیں کیا کرتے تھے، جن میں سے بہت کم میری سمجھ آتی تھیں۔ اس وقت جب کہ میری عمر تیرہ سال ہے اور میں نویں جماعت میں ہوں مجھے کچھ کچھ اندازہ ہے کہ وہ میرا شعور بیدار کرنے کے لیے کتنی کوشش کیا کرتے تھے۔
وہ اس زمانے میں میرے لیے بہت سے الیکٹرونک کھلونے لائے تھے اور انھوں نے امی سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب میں ساتویں کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لوں گا تو وہ مجھے کمپیوٹر خرید دیں گے مگر وہ اس سے پہلے ہی چل بسے۔ اس زمانے میں ابا جی نے مجھے بہت سے الیکٹرونک کٹس بھی لا کر دیے تھے۔ پلاسٹک کی تھیلی میں سے چھوٹے چھوٹے پرزے نکالتے جاؤ اور انھیں جوڑ کر کوئی نہ کوئی چیز تیار کر لو۔
’’ کھٹ کھٹا کھٹ ۔۔۔کھٹ کھٹا کھٹ۔۔۔‘‘ شالیمار کا بھاری انجن پٹریوں پر دوڑ رہا تھا اور پٹریاں شور مچا رہی تھیں۔ منظر پیچھے بھاگ رہا تھا مگر یادیں آگے آرہی تھیں۔ میرا ماضی میرے سامنے گھوم رہا تھا۔ ابا جی کی موت کے بعد امی غم سے نڈھال ہو گئیں۔ انھوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں تباہ کر ڈالیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابا جی کی جدائی سے امی کے دل میں کوئی ناسور پیدا ہو گیا ہے جو پھر کبھی نہ بھر سکے گا۔
ابا جی کی موت کے بعد چچا جان نے ہم لوگوں کو سہارا دیا اور اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیا مگر ما موں گلزار کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ظاہر میں تو وہ اسی طرح سے محبت سے پیش آتے تھے مگر ان کے دل کا چور نہیں چھپتا تھا۔ چچا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ماموں گزار اپنے خاندان کے ساتھ بھاٹی گیٹ کے پیچھے رہتے تھے مگر ابا جی کے بعد انھوں نے امی سے معلوم نہیں کیا کہہ سن کر حویلی ہی میں جگہ بنالی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ آکر رہنے لگے۔ ان کے خاندان میں ممانی کے علاوہ میری دو ماموں زاد بہنیں اور ایک بھائی شامل تھا۔
شروع میں تو سب ٹھیک تھے اور ان کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب مجھے آنکھیں دکھانے لگے۔ میرا ماموں زاد بھائی احمد تو کبھی کبھار ہاتھا پائی پر بھی اتر آتا تھا۔
ریل ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لوگ چڑھنے اترنے لگے، قلی سامان کندھوں پر اٹھائے دوڑ رہے تھے اور پلیٹ فارم کی طرف سے بھانت بھانت کی آوازیں آرہی تھیں۔
’’ چائے والا۔۔۔ چائے والا، ناشتا لے لو باؤ جی۔‘‘ ایک چائے والا میری کھڑکی کے قریب آکر چیخا:
’’بن ڈبل روٹی، مکھن۔‘‘
ناشتے کا وقت ہو گیا تھا اور بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے میں نے ناشتے کی ٹرے چائے والے سے لے لی۔ بن مکھن اور گڑ کی چائے مجھے خراب معلوم ہوتی رہی اور جی متلاتا رہا مگر میں خود پر قابو پائے رہا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آگے جا کر ان سے زیادہ خراب حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناشتا حلق سے اتار کر میں نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد چائے والا آگیا اور اس نے برتن واپس مانگے۔ میں نے کھڑکی سے ٹرے اسے لوٹا دی۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور اس سے پوچھا: ’’کتنے پیسے ہوئے؟‘‘
’’پندرہ رپے باؤ جی؟‘‘ وہ بولا۔
میں نے نوٹوں کے بنڈل میں سے پندرہ رپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ پھر انھیں واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت میرے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی کی نظریں میری جیب پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ کیا وہ جیب کترا تھا؟ اگر یہ حقیقت تھی تو مجھے اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے تھا، کیوں کہ یہی ہزار رپے جو مجھے وحید نے دیے تھے میرا کل اثاثہ اور پونجی تھے۔ میں کراچی پہنچ کر اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا اور نہ کسی سے مدد لینا چاہتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ گم نامی کی پرسکون زندگی بسر کروں گا۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے کوئی خوف نہیں ہو تا جو سادگی سے رہتے ہیں۔
میں چوں کہ صبح ہی صبح اٹھ گیا تھا اور رات کا آخری حصہ میں نے دھما چوکڑی میں گزارا تھا اس لیے اب نیند مجھے ستا رہی تھی۔ میں اخبار کے اندرونی صفحات پڑھ رہا تھا مگر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گرد و پیش سے بے خبر ہو چکا تھا۔ میں چوں کہ کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا اس لیے مجھے اچھی ٹیک ملی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آنے والے ہوا کے جھونکے خوش گوار لگ رہے تھے۔
دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی جگہ سے چہل قدمی کی اور جب ملتان کا اسٹیشن آیا تو پلیٹ فارم پر اتر پڑا۔ ملتان کا حلوا سارے پاکستان میں مشہور ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور ملتانی حلوے کی خوش بو بھی پریشان کر رہی تھی اس لیے میں ایک ٹھیلے کی طرف
لپکا۔ میں نے ٹھیلے والے سے پوچھا: ’’کیا حساب ہے؟‘‘
اس نے جواب دیا: ’’پینتیس رپے کلو جناب عالی! ایک ایک چھٹانک کے پیکٹوں میں، خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی پیش کرو۔‘‘
’’ٹھیک ہے۔ ایک کلو دے دو۔‘‘ میں نے کہا۔
اس نے ایک کلو کا پیکٹ میری طرف بڑھا دیا جس میں سولہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ رکھے تھے۔ ادائی کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں پتلون کی خالی جیب سے ٹکرائیں۔ مجھے چکر سا آگیا اور دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ خیال آیا کہ ممکن ہے میں نے غلط جیب میں ہاتھ ڈال دیا ہو، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیزی سے میں نے دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا مگر نوٹوں کا وہ بنڈل کہیں نہ ملا جو میں نے جیب میں ڈالا تھا۔
’’ کی ہویا باؤ جی؟ تسی کڑے واسدے پریشان ہو؟‘‘ ٹھیلے والے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
’’ اوہ کچھ نہیں، کسی نے جیب کاٹ لی ہے۔‘‘ میں نے گھبرا کر کہا۔ پھر پلٹ کر اپنے ڈبے کی طرف بھاگا اس خیال سے کہ نوٹ جیب میں رکھتے وقت بے دھیانی میں گر گئے ہوں۔ اپنی بینچ کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں دیکھنے پر وہ رقم مجھے نہیں ملی۔
ریل نے دوبارہ سیٹی بجائی۔ پھر وہ جھٹکے سے چل پڑی۔ میں اپنی نشست پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے برابر والی جگہ خالی رہی اور وہاں کوئی نہیں آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب صبح کے وقت میں چائے کے پیسے دے رہا تھا تو اس شخص کی نگاہیں میرے نوٹوں پر جمی ہوئی تھیں جو برابر میں بیٹھا تھا۔ بات صاف ہوگئی تھی کہ مجھے نیند میں دیکھ کر اس نے رقم اڑا لی۔
کراچی تک سفر اونگھتے ہوئے کٹ گیا۔ درمیان میں آنکھ اس وقت کھلی تھی جب ریل سکھر روہڑی کے پل پر سے گزری تھی۔ لوہے کے اس عظیم الشان پل کے نیچے سے دریاے سندھ پر سکون انداز میں بہ رہا تھا، مگر یہی دریا جب اپنا غیظ و غضب دکھاتا ہے تو آبادیوں کی آبادیاں اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔
سٹی اسٹیشن کراچی پر اترنے کے بعد میں عمارت سے باہر آیا تو کوئی بھی چیزنئی نہیں معلوم ہوئی۔ لاہور اور کراچی میں زیادہ فرق نہیں تھا سوائے تانگوں کے۔ لاہور میں تانگے تھے اور ان کی جگہ کراچی میں آٹو رکشا یا ٹیکسیاں۔
بسوں کے اڈے پر ایک آدمی رکشے کے نزدیک کھڑا’’ صدر۔۔۔ صدر۔۔۔ صدر۔۔۔‘‘ کی آوازیں لگا رہا تھا۔ میں اس رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ صدر کراچی کا مشہور علاقہ ہے اور زیب النسا اسٹریٹ رنگ و نور سے جگمگا تا بازار۔ اس سڑک کو دیکھنے کے اشتیاق میں ، میں یہ بھی بھول گیا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں دو وقت کا بھوکا ہوں۔ رکشے والے نے ایک بھرے پرے بازار میں تھوڑی دیر بعد اتار دیا۔ وہ آدمی جو آوازیں لگا رہا تھا اس نے لوگوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری تو سٹی گم ہوگئی جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔’’نکالو شاباش دوروپیہ۔‘‘
میں نے عاجزی سے کہا: ’’خان صاحب! اس وقت میری جیب خالی ہے۔ جیب کٹ چکی ہے کبھی اور دے دوں گا۔‘‘
اس نے ہاتھ ہلا کر کہا:’’ کبھی دے دے گا؟ پیسہ نہیں ہے تو رکشہ میں کیوں بیٹھتا ہے؟‘‘
میری عاجزی دیکھ کر اس نے بات نہیں بڑھائی اور بڑ بڑا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ دو چار آدمی جو وہاں جمع ہو گئے تھے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے کیوں کہ میرے جسم پر معقول لباس تھا اور میں کوئی گر اپڑا لڑکا نظر نہیں آتاتھا۔
زیب النسا اسٹریٹ کی سیر کرکے میں سیدھا چل پڑا۔ کراچی کی یہ سڑک لاہور کے مال روڈ سے ملتی جلتی ہے۔ ویسے ہی لوگ، ویسی ہی دکانیں اور ویسی ہی جلتی بجھتی روشنیاں۔
بھوک پھر ستانے لگی۔ بلکہ یہ کہنامناسب ہو گا کہ مجھ پر نقاہت طاری ہونے لگی۔ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا، اس لیے بھوک برداشت کر رہا تھا مگر بھوک بھلا کب تک برداشت ہوتی!
پیدل چلتے ہوئے ایم۔ اے۔ جناح روڈ پر آگیا۔ وہاں مجھے ریڈیو پاکستان کی پرانی اور باوقار عمارت نظر آئی۔ میں تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر سڑک پار کر کے دو سری طرف فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ اس وقت زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ ایک دو آدمی گزر رہے تھے۔ اورنگ زیب مارکیٹ کے سامنے ایک بن کباب والا کھڑا توے پر کباب سینک رہا تھا اور چار آدمی اس کے ٹھیلے کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے مانگوں گا تو یہ بھکاری سمجھ کر دھتکاردے گا اور بے عزتی بھی کرے گا اس لیے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے اس کے شوکیس میں سے ایک بن چرالوں تو کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ سوچنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل۔ جب میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کرنے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں ایک ہاتھ سے گلاس تھامے اسے مٹکے میں ڈال رہا تھا جیسے وہاں صرف پانی پینے کی نیت سے رک گیا ہوں، لیکن میرا دوسرا ہاتھ بن کو چھو رہا تھا۔
یکایک وہ لڑکا کراری آواز میں بولا: ’’واہ بیٹا استادوں سے استادی! رکھ کر ایسا تھپڑ دوں گا کہ منھ گھوم جائے گا۔‘‘ پھر اس نے میری کلائی پکڑلی۔ اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔
میں نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھیں، ناک، ہونٹ اور سر کے بال بالکل میرے جیسے تھے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہاتھا کہ جیسے میں خود کوآئینے میں دیکھ رہا ہوں۔
اس نے جب مجھے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔
پرویز مستانہ کی زبانی
وہ ریڈیو پاکستان کی طرف سے سڑک پار کر کے میرے ٹھیلے کے قریب آیا۔ پھر پانی پینے کے بہانے شوکیس میں ہاتھ ڈال کر ڈبل روٹی نکالنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے والا تھا کہ میں نے اسے اپنی طرف گھورتے پایا۔ میں نے چونک اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو۔ اس کا چہرہ ،آنکھیں ،ناک، کان سب کچھ میری طرح تھا، بالکل میری طرح !کوئی بھی تو فرق نہیں تھا۔ یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں میں آئینہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔
’’یہ کیا گھپلا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے؟‘‘
اس نے رو دینے والی آواز میں کہا: ’’مجھے سلطان احمد کہتے ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں۔ دو وقت سے بھوکا ہوں اس لیے میں نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا ورنہ میں چورنہیں ہوں بھائی۔‘‘
’’بھائی!‘‘ اس کا یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ مجھے بھائیوں جیسا ہی لگ رہا تھا اور میرا دل نہ جانے کیوں اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ میں نے اپنے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ ’’اچھا ادھربیٹھ جا۔ تجھے بند کباب کھلاؤں گا مفت۔ فکر نہ کر۔ اپن بھی دوستوں کے دوست ہیں۔‘‘
وہ بھیگی بلی کی طرح اسٹول پر بیٹھ گیا اور میری طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ سلطان مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھوں کے راستے میرے دل میں اترا چلا جارہا ہو۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے تھا اور بھوک کی کم زوری کے باوجود اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک دار اور ہونٹ گلاب کی طرح سرخ تھے۔
میں نے دل میں سوچا ،واہ اللہ میاں! تم نے چہرہ تو ہم لوگوں کا ایک جیسا بنایا ہے مگر قسمت میں کتنا فرق ہے۔ میں نالے پر رہنے والا میلا کچیلا لڑکا اور وہ صاف ستھرا چمک دار۔ یقینا کسی اچھے اور مال دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو گا۔
میں نے ہلکی چٹنی اور ہلکی مرچ کا ایک بند کباب بنایا اور پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریے کے ساتھ قبول کیا۔
اس کا ’’شکریہ‘‘ کہنا مجھے بہت بھلا معلوم ہوا، اس لیے کہ ہمارے محلے میں تو کوئی شکریہ وغیرہ نہیں بولتا۔ سب غلط سلط طرح سے ابے تبے کر کے بولتے ہیں، زبان ٹیڑھی کر کے۔ کوئی ادب لحاظ نہیں کرتا۔
وہ کھا بھی اچھے طریقے سے رہا تھا۔ نہایت مہذب انداز سے۔ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ جب اس نے کھانے کے بعد خالی پلیٹ میری طرف بڑھائی تو میں نے ایک گلاس دھو کر اسے پانی پیش کیا۔ پانی بھی اس نے شکریے کے ساتھ قبول کیا۔
’’تمھاری قسمت کتنی اچھی ہے۔ تم بالکل بے فکر اور آزاد ہو۔‘‘ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
میں نے کہا: ’’اپنی اپنی سوچ ہے۔ مجھے تمھاری قسمت اچھی لگتی ہے۔ تم لاہور میں کہاں رہتے ہو؟ اور کیا کرتے ہو؟‘‘
’’ میں گلبرگ میں رہتا ہوں اور ابھی پڑھتا ہوں دسویں جماعت میں۔ میرے والد صاحب کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ اب میں اس کا مالک ہوں۔‘‘
’’افوہ! تمھارے تو مزے آگئے۔ بہت عیش سے گزر رہی ہوگی؟‘‘
’’ہاں بہت، اگر تم چاہو تو یہ عیش تم بھی اٹھا سکتے ہو۔‘‘ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ٹھیلے کے پاس کوئی نہیں تھا اور جو گاہک تھوڑی دیر پہلے وہاں کھڑے تھے ،بندکباب کھا کر جاچکے تھے۔
’’وہ کیسے؟‘‘ میں نے حیرت سے کہا۔
اس نے ترکیب بتائی: ’’میری جگہ لے کر۔ میں اپنی زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں۔‘‘
میں نے تعجب سے کہا: ’’اتنے مال دار ہو کر بھی پریشان ہو! ساری پریشانیاں تو غریب لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ سب مصیبتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔‘‘
’’ نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی! ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تم مجھے ہی دیکھ لو۔‘‘سلطان احمد نے کہا۔
’’ کیوں؟ تمھارے ساتھ کیا ہوا؟‘‘
اس پر سلطان نے اپنی کہانی سنائی۔ پھر بولا: ’’اب بتاؤ ایسی حالت میں، میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا۔اگر رہتا تو میری بھی جان چلی جاتی۔ اپنی جان بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں وہاں سے بھاگ آؤں اور کسی ایسی جگہ پر رہوں جہاں مجھے نہ کوئی جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو۔ ایسی جگہ میرے لیے کراچی ہی ہو سکتی ہے۔ باقی جگہوں پر ایک آدھ جان پہچان والا مل جاتا ہے۔‘‘
’’افوہ! تو تم اتنے مشہور لڑکے ہو؟‘‘میری حیرت کسی طرح سے دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔
سلطان نے جواب دیا:’’ میں اتنا مشہور نہیں ہوں مگر میرا خاندان نام والا ہے اور ہم باعزت لوگ ہیں۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کیوں کہ عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے سرفراز کر دے۔ جسے چاہے نواز دے۔‘‘
’’ہاں بھئی! یہ بات تو ہے۔‘‘ میں نے اعتراف کیا۔ اس کی باتیں مجھے متاثر کر رہی تھیں۔
’’ تو پھر کیا کہتے ہو؟ میری جگہ لینے پر تیار ہو؟‘‘ سلطان نے پوچھا۔
’’صحیح بات بتاؤں؟‘‘
’’ہاں، کیا؟‘‘
’’مجھے ڈر لگتا ہے۔‘‘
سلطان کھل کھلا کر ہنسا:’’ دیکھنے میں تو تم بہادر لگتے ہو مگر تمھارا دل چڑیا جیسا ہے۔‘‘
میں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا: ’’اپنا دل بھی بڑا ہے، مگر معلوم نہیں وہاں میرے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں۔ تیری جگہ میں بے موت مارا نہ جاؤں۔‘‘
’’میں تو بزدل اور کم زور ہوں اس لیے بھاگ کر چلا آیا۔ تم تو بہادر ہو بھائی! تم ان لوگوں سے بدلا لینا اور انھیں سیدھا کر دینا۔ پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے بھائیوں کی طرح۔ میرا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں تنہا اور اکیلا ہوں۔‘‘
’’بالکل اکیلے؟‘‘
’’نہیں ماں جی ہیں، میں ان کے بارے میں تو تمھیں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ رشتے کے بھائی بہن ہیں۔‘‘
’’ہاں یاد آیا۔ ابھی تو تم نے بتایا تھا کہ انھیں بھولنے کا مرض بھی ہے، مگر وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں اور تم جب سامنے جاتے ہو تو انھیں سب کچھ یاد آجاتا ہے۔ اور ہاں انھیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔‘‘
سلطان احمد نے سر ہلایا: ’’بھائی پر ویز! میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں رہوں گا، میرے ٹھکانے کا بھی تو مسئلہ ہے۔‘‘
’’کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے میں تمھاری جگہ رہوں گا، اسی طرح تم میری جگہ رہو۔ یہاں تمھاری جان کو کوئی خوف نہیں ہو گا۔ مستانوں کی سی زندگی ہے۔ ہم تو آزاد پنچھی ہیں۔ کام کرنا اور اس کے بعد گھومنا پھرنا، مزے کرنا۔‘‘
سلطان نے کہا: ’’اچھی طرح سوچ لو۔ وہاں بھی مزے ہوں گے، مگر مختلف قسم کے۔ تم ایسی آزادی سے نہیں گھوم پھر سکو گے۔ زندگی وہاں بہت پابند ہے۔ شان و شوکت میں جکڑی ہوئی۔ تم مست ملنگ انداز میں نہیں گھوم سکتے۔ کہیں جانے سے پہلے اچھی طرح تیار ہونا ،خود کو چمکیلا بنانا اور پھر سینٹ، پرفیوم چھڑک کر جانا پڑتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر۔‘‘
’’ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔‘‘میں نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری رگوں میں سنسناہٹ دوڑ رہی ہے۔ دوسرے شہر جا کر چچا، ماموں کو چکر دینا اور سلطان کا کردار ادا کرنا کیسی حیرت انگیز اور عجیب سی بات تھی۔ ایسی چیزیں میں نے فلموں میں ہی دیکھی تھیں مگر یہ حقیقی
زندگی کی بات تھی اور راز کھلنے پر اس میں جان کا خطرہ بھی تھا۔
’’ اونھ! دیکھا جائے گا۔‘‘ میں نے سوچا۔ پھر میں نے کرید کرید کر سلطان سے سوالات کیے تاکہ میں کہیں مار نہ کھاؤں۔ مجھے ابھی سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حویلی میں سب کو چکر دے دوں گا، لیکن اسکول میں تو بہت مشکل پیش آئے گی جہاں ہر جگہ اور ہر ایک لڑکے سے مجھے انگریزی بولنی پڑے گی۔
میں نے سوچا کہ میں زیادہ تر خاموش رہوں گا۔ ایک خاموشی ہزار بلائیں ٹالتی ہے۔
میں نے اس سے کہا: ’’اب میں تمھیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج جمعہ ہے اس لیے میں نے بند کباب کا ٹھیلا لگا لیا ورنہ میں برابر والی گلی میں موٹر سائیکل کے ورکشاپ پر کام کرتاہوں۔ گھر ادھر نالے کے سامنے ہے۔ میری سات بہنیں ہیں اور۔۔۔‘‘
’’ سات بہنیں!‘‘ سلطان نے میری بات کاٹ کر گہرا سانس لیا اور آنکھیں پھاڑ دیں۔
’’ہاں! اور سب کی سب ایک نمبر کی چڑیلیں ہیں۔ میں چوں کہ سب سے چھوٹا ہوں اس لیے وہ مجھ پر خوب حکم چلاتی ہیں۔ پرویز یہ کر دو۔۔۔ پرویز وہ کر دو۔۔۔ ان سب سے۔۔۔‘‘
’’کسی سے باتیں کر رہا ہے مستانے؟‘‘ ٹھیلے کے سامنے سے اچانک فیقہ نے کہا۔ میں گھبرا گیا کہ سلطان اچانک کہاں چلا گیا اور فیقہ کہاں سے آگیا۔ حقیقت تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئی تو مجھے ہنسی آنے لگی۔ فیقہ کو سامنے سے آتا دیکھ سلطان جلدی سے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیا تھا ورنہ ہم دونوں مصیبت میں پڑ جاتے اور وہ بھوت بھوت چیختا ہوا بھاگ جاتا۔
میں نے ناک سکیٹر کر کہا: ’’باتیں، نہیں جی باتیں کہاںکر رہا تھا۔ اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ سات بج گئے ہیں اور بکری پچیس رپے کی ہوئی ہے۔ گھر کیا جواب دوں گا۔‘‘
’’ کہہ دینا لوگوں نے بند کباب کھانا چھوڑ دیے ہیں اور تکے بوٹیاں کھانا شروع کر دی ہیں۔ ‘‘اس نے پان میں رچے ہوئے اپنے لال دانتوں کی نمائش کی اور چلا گیا۔
فیقہ ورک شاپ میں مستری تھا اور میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اسے اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ اس کا اصل نام رفیق تھا جو بگڑ کر فیقہ رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان پھر اسٹول پربیٹھ گیا اور اطمینان کا سانس لے کر بولا:
’’میرا خیال ہے کہ اس طرح تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کہیں اور چل کر باتیں کریں، کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔‘‘
میں نے کہا:’’یہ تو ٹھیلا بند کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیاہے۔ تم یہیں رکو میں آتا ہوں۔‘‘
میں ٹھیلا دھکیلتا ہوا نالے کی طرف چلا گیا۔ وہاں پانچویں جھگی ہماری تھی۔ میں نے ٹھیلا آنگن میں کھڑا کیا۔ پھر گھڑونچی کے پاس جاکر بیچ والے گھڑے سے دو کٹورے پانی نکال کر منھ دھویا اور الگنی پر پڑے ہوئے تولیے سے خشک کر کے جھونپڑی پر آخری نظر ڈالی اور دروازے کی طرف مڑا تو آپا ذکیہ کی سخت آواز سنائی دی:’’ تو آگیا۔۔۔ دوڑ کے مجھے چھالیہ تو لادے آٹھ آنے کی۔ اور ہاں تھوڑا سا چونا بھی لیتا آئیو۔‘‘
’’میں نہیں لا رہا۔ مجھے بہت سے کام ہیں۔‘‘
آپا نے منھ ٹیڑھا کر کے کہا:’’اوہو لاٹ صاحب کا بچہ۔ اسے کام ہے۔ ذرا سی چھالیہ لانے سے دم نکلا جا رہا ہے۔‘‘
’’درخشاں سے منگوا لینا آپا! میں ایک گھنٹے میں آؤں گا۔‘‘ میں نے کہا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔
مجھے سلطان کے پاس جانے کی جلدی ہو رہی تھی اور لوگ بیچ میں کام بتا رہے تھے۔
سلطان مجھے وہاں کھڑا ہوا مل گیا۔ پہلے تو میں اسے اپنی دکان پر لے گیا جو اورنگ زیب مارکیٹ کے نیچے تھی پھر میں اسے جھگی کی طرف لے گیا اور میں نے اشارے سے اپنی جھگی دکھائی اور کہا: ’’اب تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔‘‘
’’ٹھیک ہے۔‘‘سلطان نے سرہلا کر رضا مندی ظاہر کی۔
ریڈیو پاکستان کے برابر جانوروں کا ہسپتال تھا جو شام ہونے کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ اس کا احاطہ سنسان پڑا رہتا تھا۔ ہم لوگ وہاں کرکٹ کھیلا کرتے یا دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔
میں وہیں چلا گیا۔ پچھلا حصہ سنسان تھا اور وہاں پیلی روشنی والا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں بر آمدے کے زینوں پر بیٹھ گیا اور میں نے سلطان کو اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں نے سلطان کو اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی اور اپنے سب دوستوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ دماغ پر زور ڈال ڈال کر سب رشتے داروں کے بارے میں سوچا اور سلطان کو بتا دیاتاکہ اسے اپنا کردار ادا کرنے میں آسانی رہے۔
سلطان احمد نے بھی مجھے سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہم نے اپنے کپڑے بدلے، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ یہ طے کیا کہ ہم ٹھیک ایک سال بعد یہیں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم جدا ہو گئے۔
وہ رات میں نے کراچی اسٹیشن پر گزاری۔ صبح میں خیبر میل میں سوار ہو گیا۔ ریل میں بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ میری قسمت کیسی عجیب اور دل چسپ ہے۔ میں جو ایک موٹر سائیکل ورک شاپ میں کام کرتا اور اس کے بعد سڑکوں پر مارا مارا پھرتا تھا، اچانک اتنے عروج پر پہنچ گیایا یوں سمجھئے کہ پہنچنے والا تھا۔
مستانہ مجھے لوگوں نے اس لیے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں مست تھا۔ مجھے کسی بات کی پروا نہیں رہتی تھی۔ تعلیم میں نے برائے نام ہی حاصل کی تھی۔ اسکول جانے کو صبح صاف ستھرے کپڑے پہننا مجھے اچھا لگتا تھا لیکن ابا کی آمدنی اتنی نہیں تھی۔ بڑی آپا ذکیہ اور باجی فرزانہ نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی تھی ورنہ باقی بہنیں میری طرح کوری تھیں۔
محلے پڑوس کے کچھ آدمی کہتے تھے کہ وقار قریشی میرے اصلی ابا نہیں ہیں اور مجھے سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے ہیں۔ میں نے جب بھی اس بات کو سنا ہنسی مذاق میں ٹال دیا، مگر کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا تھا کہ وہ کہیں صحیح نہ کہہ رہے ہوں۔
میں مکینک تھا۔ ایک مکینک کی زندگی ہی کیا ہوتی ہے؟ دن رات استاد کی جھڑکیاں اور گالیاں سننا پھر شام کو روکھی سوکھی کھا کر سو رہنا۔ اگلے دن پھر کام پر پہنچ جانا۔ ابا کہتے تھے کہ جب میں کام سیکھ جاؤں گا تو پھر مجھے دکان کھلوا دیں گے۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھوں گا، رقم وصول کروں گا۔ بہت سے لوگ میرے نیچے کام کریں گے، پھر ایک یاماہا موٹر سائیکل لے لوں گا، خوب گھوموں گا۔ یہ سوچتے سوچتے معلوم نہیں کب مجھے نیند آگئی اور میں خواب میں یاماہا چلانے اور کلفٹن کی سیر کرنے لگا۔
صبح منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے ٹرین میں ناشتا کیا۔ ناشتا بہت لذیذ تھا۔ کڑک چائے اور پراٹھا۔ مزے ہی آگئے۔ ویسے تو میں ایک پر اٹھا کھاتا ہوں مگر اس روز دو کھا گیا۔ دوپہر تک میں سوچتا رہا کہ صاف ستھرے اور مہذب لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں گا اور ان لوگوں سے مصافحہ کروں گا تو کیا لگوں گا۔ میری ٹانگیں تو نہیں کانپنے لگیں گی!
ملتان کا اسٹیشن آنے سے پہلے ڈبے میں بہت سے لوگ اچانک گھس آئے۔ جگہ تو تھی نہیں، اس لیے کچھ تو دھکم پیل کرنے لگے اور چند ایک فرش پر بیٹھ گئے۔ میں کھڑکی کے قریب والی چھوٹی سیٹ پر بیٹھا تھا جس پر ایک وقت میں ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ ایک شائستہ اور معقول سا آدمی جب فرش پر بیٹھ گیا تو مجھے شرم سی آنے لگی۔
’’بھائی میاں! یہاں بیٹھ جاؤ!‘‘ میں نے کہا۔
’’ا و نئیں بادشاہو! تسی آرام نال بیٹھے رہو۔ سانوں اگلے سٹیشن تے اترنا ہے۔‘‘ وہ بے پروائی سے بولا۔
’’ کہاں جارہے ہو؟‘‘ میں نے سوال کیا۔
’’ بس ملتان تک۔‘‘ اس نے جواب دیا۔ پھر مجھے گھورنے لگا۔ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔
’’کیوں جار ہے ہو؟‘‘ میں نے بھویں سکیڑیں۔
’’سس۔۔ سفر کیسا رہا؟ تم کراچی گئے تھے نا؟‘‘ اس نے پوچھا ۔
مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں کب کراچی کیا تھا؟ میں تو کراچی سے آرہا تھا۔ میں چند لمحوں خاموش رہا۔ کوئی بات کہہ کر میں اسے شبہ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔
’’میں تمھاری برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔‘‘ اس نے جیسے مجھے یاد دلانے کی کوشش کی۔
’’ ہاں، ہاں پھر؟‘‘ میں نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ سلطان نے ملتان پر جیب کٹنے کا واقعہ سنایا تھا۔ ممکن ہے یہ شخص اس بارے میں کچھ جانتا ہو یااسی نے وہ واردات کی ہو۔
’’ہاں میری جیب کٹ گئی تھی۔‘‘ میں نے کہا۔
’’جیب نہیں کٹ گئی تھی بلکہ تم نے پسینا پونچھنے کے لیے رومال جیب سے نکالا تھا تو تمھارے نوٹ سیٹ پر گر گئے تھے۔ میرے دل میں بے ایمانی آگئی ،اس لیے میں نے وہ رقم اٹھالی اور ڈبے سے اتر گیا۔ بعد میں، میں نے جسے بھی یہ واقعہ بتایا اس نے لعنت ملامت کی۔ میں جب سے پریشان تھا کہ تمھیں کہاں اور کیسے تلاش کروں؟ شکر ہے کہ تم دوبارہ مل گئے۔‘‘
میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھے سلطان احمد سمجھ رہا ہے جب کہ میں پرویز مستانہ ہوں۔
’’اچھا تو مال نکالو۔ اگر تمھیں غلطی کا احساس ہوگیا ہے تو میری رقم واپس کرو۔ غلطی کااحساس ہو جانا بھی اچھی بات ہے۔‘‘
اس آدمی نے نو سو رپے کے قریب رقم واپس کی۔ میں سوچنے لگا کہ سلطان احمد کا روپ دھار نا میرے حق میں مفید ثابت ہوا۔ شروع ہی میں مجھ پر دولت کی دیوی مہربان ہوگئی۔
’’کیا اچھے آدمی کا سایہ پڑنے سے بھی قسمت بدل جاتی ہے؟‘‘
جیسے جیسے ریل گاڑی لاہور کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جارہی تھیں۔ مجھے یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ جب میں تین روز بعد حویلی میں قدم رکھوں گا تو وہاں رہنے والوں کو کیا بتاؤں گا؟ اپنی غیر حاضری کا کیا بہانہ پیش کروں گا۔ میں نے سوچا کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ سب لوگ دہل کر رہ جائیں اور انھیں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو ایک ترکیب سمجھ میں آگئی۔
شام سات بجے کے قریب جب ریل گاڑی کوٹ لکھ پت پر پہنچی تو سگنل کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ عموماً ریل گاڑی وہاں نہیں رکتی۔ میں اس موقع کا منتظر تھا اس لیے فوراً ہی گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسٹیشن کی عمارت سے باہر تھا۔ کوٹ لکھ پت صنعتی علاقہ ہے۔ وہاں بہت سی ملیں اور کارخانے ہیں۔ بہت سے کارخانے ایسے بھی ہیں جو ابھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اس سے ملا ہوا ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے۔ میں مزدوروں کی کالونی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے اپنی عمر کا ایک لڑکا دکھائی دیا۔ میں نے سلام کر کے اس سے مصافحہ کیا پھر پوچھا: ’’میرا ایک کام کر دو گے دوست؟‘‘
’’ہاں کہو۔‘‘
’’میرے گھر فون کر کے کہہ دو کہ سلطان احمد یہاں پڑا ہے۔‘‘
اس نے حیرت سے کہا: ’’یہاں پڑا ہے سے تمھارا کیا مطلب؟ تم تو زمین پر سیدھے کھڑے ہو؟‘‘
میں نے کہا:’’ میں زخمی بن کر چوہدری عبد الجبار ملز کے قریب زمین پر پڑا رہنا چاہتا ہوں۔ ذرا گھر والوں سے شرارت کرنا چاہتا ہوں۔‘‘
’’اپنے والدین کو پریشان کرو گے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔‘‘ اس لڑکے نے کہا۔ وہ کوئی بااخلاق اور نیک لڑکا تھا اس لیے اسے میری باتیں پسند نہیں آرہی تھیں۔
میں نے مجبوراً جھوٹ بولا: ’’میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس شرارت سے صرف بھائی بہن پریشان ہوں گے۔‘‘ میں نے اسے اطمینان دلایا مگر پھر بھی وہ ہچکچایا۔ تو میں نے اسے سو رپے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس پر تیار ہو گیا۔ ایک دکان پر جاکر اس نے میرے سامنے حویلی والوں سے بات کی اور یہ خبر پہنچا دی۔ دوسری طرف سے بہت کچھ پوچھا گیا مگر اس نے بات ختم کر دی۔
’’اب تم جاؤ، تمھارا کام ہو گیا۔‘‘ میں نے کہا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔
وہاں ایک کارخانہ تعمیر ہو رہا تھا، اس لیے وہاں بے ترتیبی سے تمام چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ میں نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ جگہ سنسان پڑی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اور چہرے پر خراشیں ڈالیں۔ پھر ہاتھ پاؤں پھیلا کر ایک مشین کے پاس لیٹ گیا اور حلق سے بے تکی آوازیں نکالنے لگا جیسے مجھے وہاں کسی نے زخمی کر کے ڈال دیا ہے۔ توقع کے مطابق حویلی والے ڈیڑھ گھنٹے میں آگئے۔
’’ سلطان، سلطان، بابو سلطان! آپ کہاں ہیں؟‘‘ کسی نے پوچھا۔ پھر روشنی کا ایک دائرہ رینگتا ہوا مختلف جگہوں پر گیا۔
’’آہ۔۔ آہ۔۔ آہ۔۔‘‘ میں آواز کے ساتھ کراہا۔
روشنی کا دائرہ میری طرف گھوما۔ پھر بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ’’ارے چھوٹے صاحب تو یہاں پڑے ہیں۔‘‘ کسی نے گھبراہٹ سے کہا اور پھر سہارا دے کر میرا سر اپنے زانو پر رکھ لیا اور میری کنپٹیاں تھپ تھپانے لگا۔
میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے قریب تین آدمی کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں ایک ماموں ہوں گے، ایک چچا اور تیسرا کوئی یقینا ڈرائیور ہوگا، وہ بوڑھا مگر صحت مند آدمی تھا۔ اسے یقینا سلطان احمد سے بہت محبت رہی ہوگی اس لیے وہ مجھے بھینچ بھینچ کر پیار کر رہا تھا۔ ’’سلطان۔۔۔بابو سلطان ہوش میںآ۔۔۔ مینوں دس، اے کی ہویا؟‘‘
’’آہ۔۔ پانی پانی۔‘‘ میں نے درد ناک آواز نکالی۔
’’وقت ضائع نہ کرو حمیدے! اسے اٹھا کر گاڑی تک لے چلو۔ پتا نہیں کیا معاملہ ہے۔‘‘ ایک آدمی نے گونج دار آواز میں کہا، جس کالہجہ حاکمانہ تھا۔ ان کی گھنی اور اٹھی ہوئی مونچھوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ماموں گلزار ہوں گے۔ سلطان احمد نے مجھے ان کا جو حلیہ بتایا تھاوہ اس پر پورے اترتے تھے۔
ڈرائیور نے مجھے گود میں اٹھالیا اور کارخانے سے باہر لے جاکر کار کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ ماموں برابر ہی میں بیٹھ گئے اور چچا آگے۔ کار اسٹارٹ ہو کر چلنے لگی تو ماموں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے جوابات دیے اور انھیں بتایا کہ مجھے اغوا برائے تاوان والوں نے پکڑ لیا تھا۔ وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگاہوں۔
معلوم نہیں انھیں میری کہانی پر یقین آیا یا نہیں۔ وہ ہوں، ہاں، کر کے رہ گئے۔ پھر چچا نے بہت سے سوالات کیے۔ اس کے بعد ماموں سے کہا کہ اس واقعے کی رپورٹ پولیس میں کرنی چاہیے، لیکن ماموں تیار نہیں ہوئے کہ اس سے خاندان کی بدنامی ہوگی۔
ڈیڑھ گھنٹے بعد، رات دس بجے جب میں نے حویلی میں قدم رکھا تو بہت سے بچوں نے میرا استقبال کیا۔ پھر اپنے بے تکے سوالات سے میرا ناک میں دم کر دیا۔ ماموں نے منع کر دیا تھا کہ میں بچوں کو اغوا والی بات نہ بتاؤں، کوئی اور بہانہ کر دوں۔
میں نے الٹے سیدھے بہانے بنادیے۔
امی کے پاس چلیں بھائی جان۔‘‘ ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو سوچتا رہ گیا کہ وہ میری کون سی بہن ہو سکتی ہے۔ وہ سب ایک جیسی لگ رہی تھیں۔ سلطان نے مجھے تفصیل سے ان کے نام اور ناک نقشے سے آگاہ کر دیا تھا مگر وہ سب اس وقت ذہن میں گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ راحیلہ کی ناک لمبی تھی، فوزیہ کی آنکھیں چھوٹی بڑی تھیں اور ثوبیہ کے بال سنہری تھے اور دانت ترچھے یا راحیلہ کی گردن لمبی تھی اور ثوبیہ ناک سے بولتی تھی اور بھائی جان کے بجائے ’’بھاینجان‘‘ کہتی تھی۔
میں نے سوچا اس وقت نام یاد کرنے اور ان کی شناخت کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سلطان کی امی سے ملنا ضروری تھا۔ وہ دوسری منزل کے بیچ والے کمرے میں رہتی تھیں۔ میں اپنی اس ماموں یا چچا زاد بہن کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ راہ داری میں ماموں ٹہل رہے تھے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ان سب کو تو دھوکا دے دیا ہے، لیکن ایک ماں کو دھوکا دینا مشکل ہے۔ میرا بھانڈا پھوٹنے والا ہے! وہ ایک صاف ستھرا کمرا تھا جہاں بائیں طرف جاء نماز کی چوکی اور دائیں طرف ایک چھوٹی سی میز اور دو کرسیاں پڑی تھیں جب کہ بیچ میں ایک بیڈ تھا۔ ایک بوڑھی مگر باوقار خاتون جن کے چہرے پر بہت سی جھریاں پڑی تھیں، اس پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ نرم ملائم اور رنگت کھلی ہوئی تھی۔ بال بالکل سفید تھے۔ ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ ہاتھ میں موٹے دانوں کی تسبیح تھی جسے وہ گھما رہی تھیں۔
جب میں ان کے قریب پہنچا تو انھیں دیکھ کر مجھے رنج ہوا، اس لیے کہ ان کی آنکھیں بے نور تھیں۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا تو اسی لڑکی نے کہا: ’’بھائی جان آگئے۔‘‘
’’اللہ تیرا شکر ہے۔‘‘ انھوں نے بے ساختہ کہا پھر مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس وقت وہ مجھے سلطان کی نہیں بلکہ اپنی امی محسوس ہوئیں۔ ان کے سینے سے لگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی سب مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ محبت کرنے والی اور اپنی آغوش میں پناہ دینے والی۔
’’ کہاں چلا گیا تھا سلطان؟ کیا مجھ سے ناراض ہے؟‘‘ انھوں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پھر ان کی پلکیں بھیگ گئیں اور رخساروں پر آنسو پھسلنے لگے۔
’’ میں کہیں نہیں گیا تھا امی! بس ذرا یونہی۔‘‘ میں نے گول مول بات کرنی چاہی مگر میراحلق رندھنے لگا۔
وہ لڑکی اور ماموں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا کہ بات بن گئی۔ سلطان کی امی چوں کہ نابینا ہیں اس لیے مجھے اپنا بیٹا سمجھ رہی ہیں۔ کمرے میں سناٹا ہو گیا تو انھوں نے میرا چہرہ اوپر کیا اور پھر اسے انگلیوں سے ٹٹولنے لگیں۔ جیسے اپنی انگلیوں سے اسے پڑھ رہی ہوں۔
’’ناک، کان، آنکھیں اور ہونٹ سب کچھ تو ویسے ہی ہیں، مگر تو سلطان نہیں ہے۔ سچ سچ پتا دے تو کون ہے اور میرا بیٹا کہاں ہے؟‘‘ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھیں۔
’’ ڈھب۔۔۔ڈھب۔۔۔ ڈھب۔‘‘ میرا دل اتنی آواز کے ساتھ دھڑکنے لگا کہ اس کی دھمک مجھے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔
ایک دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی سلطان احمد کی زبانی
جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی طرح زندگی کے بھی دو سرخ ہوتے ہیں، حقیقی اور مصنوعی، ظاہری اور باطنی۔ میں سلطان احمد جب جانوروں کے ہسپتال سے پرویز مستانہ کے گھر کی طرف جارہا تھا تو مجھے خیال آرہا تھا کہ اب میں حقیقی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوں جہاں ذہنی سکون کے ساتھ جسمانی تکلیفیں بھی ہیں۔ ایک طرف گندے نالے کی بو پریشان کرتی ہے تو دوسری طرف بارش، گرمی اور سردی مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ میں لاہور میں جس حویلی میں رہتا تھا اس پر موسم کا اثر نہ ہوتا تھا۔ تقریباً آدھی حویلی ایر کنڈیشنڈ تھی۔ اس وجہ سے اندر کا موسم ایک جیسا رہتا تھا۔ ہمیشہ ایک خوش گوار سی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہتی تھی مگر یہاں کراچی کی اس جھگی میں مجھے صبر و شکر کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ زندگی کے بے حد تلخ ترش اور بے ذائقہ رخ کو بھی ہنس کر گزارنا ہے۔
میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ زندگی ایک بے لگام اور منہ زور گھوڑا ہے، دوڑتا ہے تو سرپٹ دوڑتا ہے اور جب کہیں اڑ جاتا ہے تو سوار کو زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ اب مجھے بہرحال اس بے لگام گھوڑے پر بیٹھنا تھا!
میں گھر کے دروازے پر پڑا ہوا ٹاٹ کا پردہ ہٹاکر اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ صحن میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور وہاں ایک بڑی عمر کی لڑکی کھڑی تھی:
’’اے لو، اب آئے ہیں شہزادے صاحب۔‘‘اس نے دوسری لڑکی سے کہا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی: ’’کیوں رے! چھالیا لایا میرے لیے یا یونہی ہاتھ ہلا تا چلا آرہا ہے؟‘‘
’’چھالیہ؟ آپ نے چھالیہ لانے کو کب کہا تھا؟‘‘ میں نے چونک کر کہا۔
’’دیکھ رہی ہو فرزانہ بہن! لاٹ صاحب کا دماغ!‘‘ اس نے دوسری لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔پھر میری طرف پلٹ کر بولی: ’’جب تو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی زلفیں سنوار رہا تھا، اس وقت میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ شاہی سپاری کا ایک پیکٹ لیتا آئیو؟‘‘
ایک لمحے میں مجھے یاد آگیا کہ میں سلطان احمد نہیں پرویز مستانہ ہوں۔ اب مجھے اس کا پارٹ ادا کرنا ہے۔ اس کی بول چال، رنگ ڈھنگ کی میں کافی مشق کر چکا تھا اور اب مجھے ویسا ہی کر کے بتانا تھا۔ یقینا جب پرویز مجھ سے ملنے آیا ہوگا تو اس کی بڑی بہن آپا ذکیہ نے اسے چھالیہ لانے کو کہا ہوگا۔ میں نے کہا: ’’ٹھیریے، ابھی لا کر دیتا ہوں میں بھول گیا تھا۔‘‘
’’ا ے لو ہم ٹھیریے ہو گئے۔ اتنی شریفانہ زبان۔ مستانے! کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے؟ تواتا شریف زادہ کیسے ہو گیا؟‘‘ انھوں نے ہاتھ ہلا کر کہا۔
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگی۔ خیال آیا کہ اگر میں نے نہایت شریفانہ اور مہذبانہ زبان استعمال کی تو یہ لوگ اجنبیت محسوس کریں گے اور چونک جائیں گے۔ ممکن ہے مجھ پر شبہ بھی کرنے لگیں، اس لیے مجھے جیسا دیس ویسا بھیس کے مطابق کھڑی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔
بہرحال اس وقت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں پلٹا اور جھگی سے نکل آیا۔ پھر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا نالے کے دائیں جانب گیا۔ پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر لکڑی کا ایک کیبن تھا جو دور ہی سے نظر آتا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا تو میں نے اسے بند پایا۔ ذہن پریشان سا ہو گیا کہ اس وقت شاہی سپاری کہاں تلاش کروں؟
اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا۔ جہاں نالا ختم ہوتا اور ایک سڑک اسے کاٹتی تھی وہاں بائیں طرف مجھے روشنی دکھائی دی اور چند بچے کھیلتے نظر آئے۔ میں اس طرف چلا گیا۔ وہ پان سگرٹ کی ایک دکان تھی۔ میں نے اس سے چھالیہ کا پیکٹ مانگا تو اس نے ڈبے میں سے ایک پیکٹ نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے پیسے دیے اور وہاں سے واپس ہوا۔
دکان پر دو لڑکے کھڑے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک مجھے بری طرح گھورنے لگا۔ اس کے اس طرح گھورنے پر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ لڑکا لمبے قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک اندھیری گلی میں کھینچ لیا۔
’’تت۔۔۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہے ہو؟‘‘
’’واہ بیٹا! اپنے باپ کو بھول گیا۔ اب ہم کون ہونے لگے؟ آنکھیں کھول کر دیکھ ہم راجو دادا ہیں۔ اس محلے کے راجا۔ یہاں ہماری حکومت ہے۔‘‘
’’اچھا تو مجھ سے کیا چا ہے؟‘‘ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔
’’ لاؤ کمیشن نکالو۔ دادا ٹیکس۔‘‘ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
’’کیسا کمیشن؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’خوب انجان بن رہے ہو۔‘‘ اس نے ناک سکیٹر کر کہا: ’’مگر ہاتھ تو تم نے بہت اونچی جگہ مارا ہے۔ نیشنل کا جاپانی ٹرانزسٹر تو چور بازار میں کافی مہنگے داموں میں گیا ہو گا؟‘‘
ٍٍ ’’ٹرانزسٹر؟ کیسا ٹرانزسٹر؟‘‘ میں نے ہونقوں کی طرح کہا۔
اس نے کہا: ’’وہ جو تم نے دو روز پہلے آپا فاطمہ کے ہاں سے اڑایا تھا۔ رمضانی کہہ رہا تھا کہ پانچ بینڈ کا ٹرانزسٹر تھا۔ چور بازار میں آسانی سے ڈیڑھ ہزار کا گیا ہوگا۔ لاؤ پانچ سو مجھے دو ورنہ میں سب کو بتا دوں گا۔‘‘
معلوم نہیں کیا قصہ تھا۔ اگر اس لڑکے کا نام راجو تھا اور وہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا تھا تواس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چوری دو روز پہلے پرویز مستانہ نے کی تھی۔ میں چوں کہ اس کا ہم شکل تھا اور اس کی جگہ لے چکا تھا اس لیے وہ میری گردن داب رہا تھا۔
میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ پرویز مستانہ کیا چور تھا؟ کیا میں نے انجانے میںغلط لڑکے پر بھروسا کر کے کوئی عذاب مول لے لیا ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ بہت سے سوالات میرے دماغ میں چکرانے لگے۔
فی الحال تو اس غنڈے سے مجھے اپنی جان چھڑانی تھی۔ میں نے چند لمحوں تک غور کیا تو ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے کہا: ’’تم نے رمضانی کی بات پر اعتبار کیوں کرلیا؟ وہ جھوٹ بک رہا ہے۔ میں نے کوئی چیز نہیں چرائی میں تو آپا فاطمہ کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔‘‘
’’استادوں کو چکما دے رہا ہے۔‘‘ اس نے ناگواری سے کہا۔
وہ تیرہ چودہ سال کا لڑکا تھا مگر اتنے پختہ انداز میں بات کر رہا تھا جیسے پچیس،تیس سال کا ہو۔
’’چکمے کی بات نہیں ہے۔ اگر بات ثابت ہو جائے تو میں کمیشن دینے کو تیار ہوں۔‘‘میںنے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔
’’ ٹھیک ہے۔ میں آج تو تجھے چھوڑے دے رہا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔ بچ کے کہاں جائے گا۔ محلہ تو چھوڑنے سے رہا۔‘‘ وہ بولا۔ پھر سیٹی بجاتا ہوا دو سری طرف چلا گیا۔
میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے مل گئی تھی مگر مجھے اس کا کوئی مستقل حل سوچنا تھا۔ شاہی سپاری لے کر گھر پہنچا تو آپا ذکیہ نے دو چار باتیں اور سنادیں۔
میں سمجھا تھا کہ مصیبت ختم ہوگئی اور اب میں سکون سے سو سکوں گا لیکن توبہ کیجیے۔ ذکیہ آپا سے فرصت ملی تو فرزانہ باجی نے آواز دی: ’’اے نکھٹو بھیا! ہماری بھی سن لے۔‘‘
’’ہاں کی فرماؤ۔‘‘ میں نے کہا۔
’’فرمانا ورمانا کیا۔ میں خوشامد کر رہی ہوں کہ میرا سر دبادے۔ درد سے پھٹا جارہا ہے۔‘‘
’’ابھی لو جی۔‘‘ میں نے مستعدی سے کہا اور ان کے نزدیک جاکر ان کا سر دبانے لگا۔ باقی بہنیں یا شیطان کی خالائیں آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مستانہ اول تو ان کے ہاتھ نہیں آتا ہو گا اور اگر آتا بھی ہوگا تو ان کا حکم اتنی آسانی سے نہیں مانتا ہوگا۔ ؎ میں تو اس کا پارٹ ادا کر رہا تھا اس لیے ڈر رہا تھا۔ پرویز نے مجھے اپنے بارے میں سب ہی کچھ بتادیا تھا، لیکن وقت پر تمام باتیں کہاں یاد آتی ہیں۔ میں تو اپنی ذہانت سے پرویز بنا ہوا تھا اورکسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔
وہ دو کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ باورچی خانہ وغیرہ بھی تھا۔ دو کمروں میں سے ایک میں اماں ابا اور دوسرے میں سب بہنیں رہتی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور سب سونے کی تیاری کر رہی تھیں اس لیے سکون تھا، مگر میں جانتا تھا کہ صبح سورج نکلنے کے بعد یہ سکون غارت ہو جائے گا اور جب وہ سب مل کر دھما چوکڑی مچائیں گی تو زلزلہ آجائے گا۔
’’ارے ذکیہ! یہ کس کی آواز ہے؟ کیا پرویز آگیا؟ ‘‘دوسرے کمرے سے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی۔
’’ہاں ابا! تمھارا شہزادہ آگیا۔‘‘ آپا نے بیزاری سے کہا۔
’’ذری دیر کے لیے اسے میرے پاس بھیج دے۔ آج میری ٹانگوں میں بہت درد ہورہا ہے۔‘‘ ابا کی آواز آئی۔
یہ سنتے ہی میری تو روح فنا ہوگئی۔ کیا اب میں ساری رات ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں دباتا اور سر کی مالش کرتا رہوں گا؟ مسلسل سفر سے میرا جسم خود بھی ہر جگہ سے دکھ رہا تھا۔ میں کس سے دبوا تا؟ گرتا پڑتا نیند میں مدہوش دوسرے کمرے میں گیا تو میں نے انھیں ایک چوکی پر لیٹے دیکھا۔ وہ تن درست اور توانا تھے، لیکن بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں اور فکروں کا جال۔ ان کا چہرہ عام لوگوں کی طرح تھا۔ شاید سب غریبوں کے چہرے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فکریں، پریشانیاں اور مصیبتیں۔ غم، دکھ سکھ سب ہی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں ان کی چوکی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف سے آواز آئی: ’’بیٹا مستانے!آگیا؟‘‘
’’ہاں۔۔۔ ہاں اماں۔‘‘ میں نے آہستہ سے کہا۔
وہ ماں بھی عام ماؤں جیسی تھیں۔ شفیق اور مہربان۔ انھیں دیکھ کر مجھے اپنی اماں یاد آگئیں۔ معلوم نہیں کس حال میں ہوں گی؟ پرویز جب ان سے ملا ہوگا تو معلوم نہیں انھوں نے کیا سوچا ہوگا۔ ان کی یاد آئی تو میرا دل رونے لگا۔
’’میرے پاس آ میرے بچے۔‘‘ انھوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔
وہ پھول دار سوتی کپڑے پہنے تھیں اور سر پر سفید دوپٹا تھا۔ میں قریب گیا تو انھوں نے مجھے لپٹا لیا جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ تھا۔ ’’تونے کھانا کھالیا میرے لعل؟‘‘ انھوں نے میرا چہرہ تھپ تھپا کر پوچھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا بلب روشن تھا جس کی ہلکی روشنی وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً اس لیے انھیں مجھ پر شبہ نہیں ہوا اور انھوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح قبول کرلیا۔
کہنے کو میری سات بہنیں تھیں مگر مجھے دیکھتے ہی سب کے ہاتھوں پیروں میں درد شروع ہو گیا تھا اور کسی نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں نے کیا کھایا اور کیا پیا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سر سے پاؤں تک محبت۔
میں نے کہا: ’’ہاں کھالیا ماں، جب ٹھیلا ختم کیا تھا تو ایک بند کباب میں نے بھی کھالیا تھا۔ تم فکر نہ کرو۔‘‘
’’میں فکر نہ کروں تو پھر اور کون فکر کرے گا۔‘‘
’’ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔‘‘ میں نے کہا اور ابا کی ٹانگیں دبانے لگا۔
’’ آج کتنے کی بکری ہوئی مستانے؟‘‘ انھوں نے سوال کیا۔
’’ ڈیڑھ سو کی۔‘‘ میں نے کہا اور جیب سے رپے نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ رقم مجھے پرویز مستانہ نے لاہور جانے سے پہلے دی تھی کہ میں اسے ابا کے حوالے کردوں۔
’’اللہ تجھے جیتا رکھے۔‘‘ انھوں نے رپے جیب میں رکھتے ہوئے دعا دی:
’’ہماری امیدوں کا چراغ تو ہی ہے مستانہ۔ تیرے ہی دم سے اس گھر میں روشنی ہے۔ مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا۔۔۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔‘‘
میں نے حیرت ظاہر کی: ’’تم کیسی باتیں کر رہے ہو ابا! اچھے بچے بھی کہیں ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔‘‘
انھوں نے اٹھ کر مجھے بھینچ لیا: ’’ہاں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بس کبھی کبھی بہک جاتا ہوں۔ سچ بتا ہم تجھے کیسے لگتے۔۔۔‘‘
’’اے میں کہتی ہوں کیا باؤلے پن کی باتیں کر رہے ہو؟‘‘ اماں نے دوسرے گوشے سے ڈانٹ کر کہا: ’’دن بھر ٹھیلا لگا کر تھکا ماندہ آیا ہے اور اب تم دیوانے پن کی باتیں کر کے اس کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ اب چپ چاپ سوجاؤ۔‘‘ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولیں: ’’ جا میرے بچے! تو بھی سوجا اب جا کر۔ ان کی ٹانگوں میں تو ہر روز ہی درد اٹھتا رہتا ہے۔‘‘
ان کا اشارہ پاکر میں وہاں سے کھسک لیا اور دوسرے کمرے میں جاکر لیٹ گیا۔ لاہور میں جب میں اپنی حویلی کی خواب گاہ میں لیٹا کرتا تھا تو سونے سے پہلے ٹیپ ریکارڈ پر مائیکل جیکسن کا کوئی ٹیپ لگا دیتا تھا مگر یہاں یہ سب کہاں میسر تھا۔ لیٹتے ہی مجھے مچھروں کی خوف ناک بھن بھناہٹ سنائی دی اور چند لمحوں کے بعد احساس ہوا کہ نالے کی طرف سے ناگوار بو آرہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں سو نہیں سکوں گا اور یہ رات آنکھوں میں کٹے گی لیکن خیال غلط ثابت ہوا اور تھوڑی دیر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔
صبح آپا ذکیہ نے مجھے ٹہوکا دے کر جگایا اور حکم دیا کہ میں منہ ہاتھ دھو کر حلوا پوری لے آوں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد میلے کچیلے اور داغ دار کپڑے پہن کر ورک شاپ کی طرف چل پڑا۔ یہ میرے لیے دوسرا امتحان تھا۔ پہلی امتحان گاہ گھر تھی جہاں مجھ پر کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ورک شاپ میں بھی کوئی میری باتوں اور حرکتوں پر نہ چونکا تو میں سمجھ لوں گا کہ میں مستانے کا کردار صحیح طرح سے ادا کر رہا ہوں۔
میں نے اسپیئر پارٹس والی گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ دائیں طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بھکاری نے آواز لگائی: ’’دیتا جا بچہ! جو دے گا اس کا بھی بھلا جو نہیں دے گا اس کا بھی بھلا۔‘‘
میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دس کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ دس کا نوٹ دیکھ کر وہ بھکاری بہت خوش ہوا: ’’ہا ہا ہا مستانے! آج تو تیرا دل بہت بڑا ہو گیا۔ قسم پروردگار کی قسم تو نے دل خوش کر دیا۔ ادھر آجا۔۔۔ ادھر آجا میرے پاس۔‘‘
میں اس کے پاس چلا گیا۔
بھکاری نے اپنی موٹی گردن ہلا کر کہا: ’’میں بیس سال سے ادھر بیٹھ رہا ہوں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ تو میری بات مانے گا؟‘‘
’’کیا ،بولو۔‘‘ میں نے پوچھا۔ مجھے حیرت ہورہی تھی کہ ایک بھکاری کو مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔
’’ تو ادھر وقار کے پاس مفت میں اپنا ٹائم کھراب کر رہا ہے۔ اس کو چھوڑ دے۔۔۔ یہ تیرا اصلی باپ تو نہیں ہے۔‘‘
’’ہاں ہاں!‘‘ میں نے بے دھیانی میں کہا۔
اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ وقار قریشی میرے اصلی والد نہیں ہیں، مگر مستانہ کے والد تو ہیں۔ میں چوں کہ مستانہ بنا ہوا ہوں اس لیے مجھے ’’ہاں‘‘ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے فوراً کہا:
’’یہ تم کیا کہہ رہے ہو باباجی! قریشی صاحب تو میرے والد ہیں۔‘‘
اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ’’نہیں۔ وہ تیرا والد کیسے ہو سکتا ہے بچہ۔ وہ تو تیرے کو خرید کر لایا تھا۔‘‘ یہ سنتے ہی میرے دل و دماغ میں بھونچال سا آگیا اور میں سلطان احمد وہاں کسی مجسمے کی طرح خاموش کھڑا رہ گیا۔
ایک دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی پرویز مستانہ کی زبانی
ٍ ’’ڈھب۔۔۔ڈھب۔۔۔ڈھب۔۔۔‘‘ میرا دل اتنی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی گونج اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔
میں نے سوچا ماں کی مامتا کو دھوکا دینا بہت مشکل ہے۔ اماں نابینا تھی اور مجھے دیکھ نہیں پارہی تھی، اس کے باوجود اس نے یہ جان لیا تھا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں اسے اطمینان نہ دلا تا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شور مچادیتی اور مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرادی۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے اور سلطان احمد کے بارے میں پوچھتے ،جس کی جگہ میںکراچی سے آیا تھا۔
’’تت۔۔۔تم۔۔۔آآآپ کو۔۔۔ کیسے معلوم ہوگیا اماں؟‘‘ میں نے پوچھا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے میں ہکلانے لگا۔
انھوں نے میرا چہرہ تھپ تھپا کر کہا:’’خوش بو میرے بیٹے ،خوش بو! تجھ میں ایسی خوشبو نہیں آرہی ہے جیسی کہ سلطان کی ہے۔ سچ سچ بتادے وہ کہاں گیا؟‘‘ وہ سرگوشی میں بول رہی تھیں جیسے کہ میرے راز کو راز ہی میں رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسی طرح سے اور اتنی ہی دھیمی آواز میں انھیں پوری کہانی سنادی۔
انھوں نے کہا:’’ ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے دن یہیں رہ میرے پاس۔۔۔ اس گھر میں اور سلطان کے دشمنوں کا پتا لگا۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ مولا اس کی حفاظت کرے۔‘‘
میں ان کے پاس سے بھاری دل کے ساتھ اٹھ آیا۔ معلوم نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگوں۔ مجھے اپنی ماں یاد آرہی تھیں۔ وہ ساتوں بہنوں سے زیادہ مجھے چاہتی تھیں اور رات کو اگر میں باہر سے کھانا کھاکر نہ آیا ہوں تو مجھے خود اپنے ہاتھ سے
کھانا کھلاتی تھیں۔
کمرے سے نکل میں راہ داری میں گیا تو بے دھیانی میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ لمبے قد کی ایک لڑکی تھی جس کے اوپری دانت غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ اس طرح سے ہوا کہ اس کا منھ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ سلطان نے بتایا تھا کہ وہ ماموں زاد بہن راحیلہ ہے۔
اس نے شوخی سے کہا: ’’اللہ بھائی جان! کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ دیکھ کر کیوں نہیں چلتے؟‘‘
’’تم خود ہی کھجور کے درخت کی طرح میرے سامنے آگئیں راحیلہ، ورنہ میں تو ٹھیک جارہا تھا۔‘‘ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی: ’’ راحیلہ؟ کیا آپ کی آنکھیں واقعی بند ہیں! میں تو فوزیہ ہوں فوزیہ۔‘‘
میں گڑ بڑا گیا۔ میری یاد داشت دھوکا کھا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے بھائی بہنوں کے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ سب میرے دماغ میں گڈ مڈ ہو گیا تھا۔
’’ اوہ ہاں، بھئی میرے منہ سے غلط نام نکل گیا۔ تم تو فوزیہ ہو کٹ کھنی مرغی۔‘‘ مجھے یاد آیا کہ سلطان نے اسے یہ خطاب دے رکھا تھا۔
اس بار تیر صحیح نشانے پر لگا۔
’’ اللہ بھائی جان آپ پھر مجھے ستا رہے ہیں۔‘‘ وہ پیچھے ہٹ کر منمنائی۔
’’ اچھا ہٹو میرے راستے ہے۔ ایک طرف ہو جاؤ۔‘‘
اس نے اچانک پوچھا: ’’آپ غائب کہاں ہو گئے تھے؟ سب لوگ پریشان تھے۔‘‘
اغوا برائے تاوان والا بہانہ میں اس کے سامنے نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کے سامنے کیا کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ ماموں گلزار نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ہمارے خاندان کی بدنامی ہے۔ فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سامنے کیا عذر پیش کروں۔
’’مم۔۔ میں۔۔۔پر۔۔۔‘‘
’’کیا بکریوں کی طرح میں میں کر رہے ہیں۔ صاف آواز میں بولئے۔‘‘ اس نے بائیں ہاتھ کے لمبے ناخن میری گردن میں چبھو کر کہا۔
’’مجھے پریاں اٹھا کر لے گئی تھیں۔ میں پرستان گیا ہوا تھا۔‘‘ میں نے جھٹ سے کہا۔
’’ پھر کالے دیو نے آپ کو دھکا دے کر ہماری دنیا میں واپس بھیج دیا۔ ہے نا؟‘‘ وہ لمبے دانت نکال کر کھی کھی کھی کرکے ہنسی: ’’اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں چار پائی کے بانوں میں پھنسے ہوئے تھے یا آپ بستر سے نیچے پڑے ہوں گے۔‘‘
میں اس سے جان چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ لباس بدل لوں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میرا کمرا کہاں ہے اور مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ اس فوزیہ کی بچی نے سب کچھ بھلا دیا تھا!
میں گم سم کھڑا تھا کہ اس نے میری گردن گھما کر مجھے دھکا دیا اور میری مصیبت خود ہی حل کردی۔
’’ جائیے اپنے ہاتھ پیر اور منھ دھوئیے۔ کھانے کا وقت ہورہا ہے۔ اور یہ آپ کے ہاتھ اتنے کالے سے کیوں ہورہے ہیں؟ کیا پرستان میں پریوں نے آپ کو تارکول کے ڈرم میں ڈال دیا تھا؟‘‘ وہ مذاق سے اب بھی باز نہیں آرہی تھی۔
میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر بگٹٹ اس دروازے کی طرف بھاگا جدھر فوزیہ نے مجھے دھکا دیا تھا۔ وہ کمرا سب سے آخر میں تھا۔ میں نے دروازے کے لٹو پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ اندر پہنچ کرمیں نے دروازہ بند کیا اور دائیں جانب لگے ہوئے سوئچ بورڈ پرانگلیاں ماریں تو بہت سی لائٹیں جل اٹھیں اور پنکھے چلنے لگے۔
میں نے سنبھل سنبھل کر سوئچ آف کیے اور دو لائٹیں جلتی رہنے دیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ چھت میں لگا ہوا چھوٹا سا فانوس مجھے بہت اچھا لگا۔ میں دو قدم آگے بڑھا تو نرم و ملائم قالین میں میرے پاؤں دھنسنے لگے۔ بائیں جانب نہایت خوب صورت اور بڑی مسہری تھی اور دائیںجانب لکھنے پڑھنے کی میز۔
واہ مزے آگئے۔ میرا دل چاہا کہ خوب اچھلوں کو دوں اور قالین پر لوٹیں لگاؤں۔ اللہ میاں نے کتنی مہربانی کی اور مجھے کیسی جنت میں بھیج دیا۔ ارادہ تھا کہ میں منہ ہاتھ دھولوں گا مگر پھر میں نے سوچا کہ نہالینا چاہیے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ لباس منتخب کرلینا چاہیے مگر کپڑوں کی الماری کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ دائیں جانب دو دروازے دکھائی دیے۔
میں نے نزدیک جاکر انھیں کھولا تو میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں اوپر سے نیچے تک کپڑے ہی کپڑے بھرے تھے۔ نہایت سلیقے سے تہ کیے ہوئے۔ میری تو عقل چکراگئی کہ کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس وقت کیا پہنا جاتا ہے؟
نائٹ گاؤن!
میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ رات کو لوگ نائٹ گاؤن پہنتے ہیں۔ میں نے فلموں میں دیکھا تھا اور سنا بھی تھا کہ بہت امیر لوگ رات کو یہی لباس پہنتے ہیں۔ میں نے دیوار میں دھنسی ہوئی اس الماری سے نائٹ گاؤن نکال لیا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ وہاں عجیب عجیب چیزیں لگی ہوئی تھیں جنھیں سمجھنے میں کافی دیر لگی۔ بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ بالٹی اور مگ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہاؤں کیسے؟
کراچی میں اپنے مکان پر ہو تا تو نلکے پر مگ اور بالٹی لے جاتا اور نیکر پہنے پہنے وہیں نہا لیتا۔ اللہ اللہ خیر صلا۔
بہر حال نہانا ضرور تھا اور ہاتھوں پیروں کی سیاہی چھڑانی تھی، اس لیے میں نے دیوار میں لگے ہوئے والو گھمانا شروع کردیے۔ ارے بھئی، پھر تو مزہ ہی آگیا۔ پانی فوارے کی طرح میرے جسم پر گرنے لگا۔ میں نے اچھی طرح سے غسل کیا اور خوش بو دار صابن کو اپنے جسم پر رگڑا تومجھے بہت اچھا لگا۔
نہا دھو کر اور تمام نلکے بند کرکے میں نے نائٹ گاؤن پہنا اور غسل خانے میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے جاکر کھڑا ہوگیا۔ اس کے دائیں طرف ایک سوئچ دبایا تو آئینے کے اوپر لگی ہوئی تیز روشنیاں جل اٹھیں اور میرا چہرہ روشن ہوگیا۔ میں نے کنگھا اٹھاکو گیلے بالوں میں کنگھاکیا اور تھوڑی سی کریم چہرے پر ملتا ہوا باہر آگیا۔
بالکل شہزادوں والا حساب کتاب تھا وہاں۔ میرے تو مزے آگئے۔ بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے مسہری کے سرہانے لگی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ نو بجنے والے تھے۔ معلوم نہیں یہ بڑے لوگ کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ رات کو کھاتے بھی ہیں یا نہیں؟ ایسا تونہیں کہ صرف دودھ پی کر سوجاتے ہوں؟
میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹھیک اسی وقت ہلکی آواز میں ایک گھنٹہ بجنے لگا۔ ’’ڈنگ ڈانگ۔۔۔ ڈنگ ڈانگ۔۔۔‘‘ مجھے یاد آیا کہ سلطان احمد نے بتایا تھا کہ کھانے سے پہلے حویلی میں ایسا گھنٹہ ضرور بجتا ہے۔ اور اس کی آواز سن کر سب لوگوں یعنی بچوں اور بڑوں کو کھانے کے کمرے میں پہنچنا ہوتا ہے۔ گلزار ماموں اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھا نا وقت پر کھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے مگر میں کہاں جاؤں؟ کھانے کا کمرا کہاں ہے؟ ہاں یاد آیا شاید نیچے ہے۔ سلطان نے یہی تو بتایا تھا؟
میں ٹہلنے والے انداز میں زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی اتنی خوب صورت تھی کہ ہر ایک چیز کو رک رک کر دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ میں نیچے پہنچ کر ایک طرف ہو گیا۔ سوچا کوئی آواز دے گا یا ہاتھ پکڑ کر کھینچے گا تو اس کے ساتھ ہولوں گا اور اس طرح سے کھانے کے کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔
میں جہاں کھڑا تھا وہ ایک چھوٹا سا ہال تھا۔ سامنے آگے پیچھے بہت سے دروازے تھے۔ یا اللہ کہاں جاؤں! اچانک بائیں طرف کا ایک دروازہ کھلا۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی نکلا جو ٹرالی دھکیل رہا تھا۔ بے ساختہ جی چاہا کہ اس سے پوچھ لوں، بھائی صاحب کھانے کا کمرا کہاں ہے؟ مہربانی ہوگی بتادیجئے۔ لیکن شکر ہے کہ عین وقت پر یاد آگیا کہ میں اس حویلی کا مالک سلطان احمد ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں تھا تو پرویز مستانہ مگر سلطان احمد کی جگہ لیے ہوئے تھا، اس لیے مجھے اسی جیسا بن کر رہنا چاہیے تھا۔
’’بابو سلطان آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟‘‘ اس سفید لباس والے نے پوچھا۔
مجھے یاد آیا کہ ایسے سفید کپڑے والے اونچے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں اور ویٹر کہلاتے ہیں۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟
’’بھئی مجھے کہاں ہونا چاہیے؟‘‘ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔
وہ سادگی سے بولا: ’’ڈائننگ روم میں۔ چلئے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔‘‘
دہ ٹرالی دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یوں میں ڈائننگ روم کے بجائے کچن میں پہنچ گیا۔
’’بابو آپ یہاں کیوں آگئے؟‘‘ اس نے حیرت سے پوچھا ۔
دل چاہ رہا تھا کہ اس کے گال پر طمانچہ مار کر پوچھوں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے اور وہ بتاتا کیوں نہیں کہ ڈائننگ ہال کہاں ہے، مگر میں نے خود پر قابو پالیا۔ اس لیے کہ پھر ڈراما غلط ہوجاتا اور میں پکڑ لیا جاتا۔ میں نے جھٹکے دار آواز میں کہا: ’’میری مرضی۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ ‘‘پھر میں وہاں سے پلٹ گیا۔
میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ویٹر جہاں سے ٹرالی لے کر نکلا تھا ڈائننگ ہال وہی ہوگا۔ اس لیے کہ وہ خالی ٹرالی لے کر نکلا تھا۔ اس نے کچن سے کھانا لے جاکر وہاں رکھا ہوگا۔ اس دروازے پر پہنچ کر میں نے جب اس کا دروازہ کھولا تو چونک کر رہ گیا۔ وہاں ایک لمبی میز تھی جس کے چاروں طرف خاندان کے تمام لوگ بیٹھے تھے۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر ان سب لوگوں نے میری طرف دیکھا۔ چند ایک لڑکے اور لڑکیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ایک لڑکی نے کہا: ’’بھائی جان! آپ نائٹ گاؤن پہن کر کھانا کھانے کیوں چلے آئے؟‘‘
میں نے محسوس کیا کہ معاملہ غلط ہو گیا ہے، مگر صورت حال ایسی تھی کہ میں الٹے پاؤں واپس نہیں جاسکتا تھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوچا پھر بات بنائی:
’’میں۔۔۔ میں فوراً ہی سوجاؤں گا۔ تھکا ہوا ہوں۔‘‘
میرا جواب سن کر وہ اپنی پلیٹوں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بات بن گئی ہے اس لیے میں قدم جما جما کر چلتا ہوا میز کے قریب پہنچا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔
’’آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟‘‘ ایک لڑکے نے کہا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا؟ احمد یا زاہد؟ چچا زاد یاماموں زاد؟
’’کیوں یہاں بیٹھنے میں کیا ہرج ہے؟‘‘ میں نے ناک سکیٹر کر کہا۔
’’کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ کی کرسی تو وہ ہے۔ آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے۔اس نے میز کے آخر میں رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کرسی دوسری کرسیوں کے مقابلے میں خوب صورت تھی اور اس پر مخمل چڑھی ہوئی تھی۔ ایسی کرسیوں پر بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔
میں اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں جاتا تو کھیل بگڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ضدی بچوں کی طرح کیا: ’’نہیں آج میں یہیں بیٹھوں گا۔‘‘
کسی نے کچھ نہیں کہا اور سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔
میں نے سب کی طرف سے نظریں ہٹا کر میز کی طرف دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی۔ وہاں قسم قسم کی نعمتیں سجی ہوئی تھیں۔ ایک سے ایک خوش نما کھانے تھے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک دم سے سب پر ٹوٹ پڑوں اور انھیں اپنے معدے میں اتار لوں مگر میں نے صبر کیا۔
بریانی میری کم زوری ہے۔ وہی سب سے آگے رکھی تھی۔ میں نے اس کی قاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک اسی وقت ایک عجیب سی آواز ابھری۔ جیسے کوئی راہ داری میں چل رہا ہو۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ گھر گھر گھر۔۔۔! وہ کوئی ایسا آدمی تھا جو پاؤں گھسیٹ کر چل رہا تھا۔
میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ جیسے کوئی چیز یاد داشت کی نچلی تہ سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور بریانی اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ نزدیک ہی رائتا رکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہی آواز پھر سنائی دینے لگی۔ اس بار وہ اور صاف تھی۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ گھر گھر گھر۔
یکا یک مجھے یاد آیا کہ ایسی آواز کے بارے میں مجھے سلطان احمد نے بتایا تھا۔۔۔ کہ۔۔۔ کہ۔۔۔ اسے تین دن پہلے رات کو کوئی لنگڑا قتل کرنے آیا تھا اور اس کے قدموں سے ایسی ہی آواز نکل رہی تھی۔ تو کیا وہی قاتل یہاں پھر آگیا ہے اور اب مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟
میرا جسم کانپنے لگا اور مجھے خوف کی ایک لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
پھر دروازہ کھلا اور ایک ہیبت ناک آدمی ڈائننگ ہال میں آگیا۔ وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس وقت میں ڈر گیا اور میرے ہاتھ میں دبا ہوا رائتے کا ڈونگا میرے ہاتھ سے پھسل کر میز پر گر گیا پھر لڑھک کر میری گود میں چلا گیا۔ میں رائے میں لتھڑ گیا۔ میں نے اس خوف ناک آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کانپتی آواز میں کہا: ’’اس۔۔۔ سے۔۔۔ سے۔۔۔ گگ۔۔۔گرفتار کرلو۔۔۔یہ۔۔۔یہ۔۔۔قق قاتل ہے۔‘‘
کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے سب لوگ چونک کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔
سلطان احمد کی زبانی
میں سلطان احمد اس طرح بت بنا ہوا کھڑا تھا جیسے مجھے کسی نے پتھر کا بنادیا ہو! یہ انکشاف میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا کہ پرویز مستانہ یعنی میرا ہم شکل جو اس وقت میری جگہ پر لاہور میں ،میری حویلی پر ہے اپنے والدین کا اصلی بیٹا نہیں ہے اور یہ لوگ اسے کہیں سے لائے ہیں۔ بھکاری نے کہا:
’’جا چلا جا ادھر ہے۔ ان لوگوں کی خدمت کر کے اپنا وقت کیوں برباد کرتا ہے۔ میں ٹھیک کہتا ہوں۔ یہ لوگ تجھے برباد کردیں گے۔ تو ادھر سے جا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر۔‘‘
میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ میرے قدم زمین پر صحیح نہیں پڑ رہے تھے اور میں لڑکھڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے آپ پر قابو پالیا اور قدم جما کر چلتا ہوا ورک شاپ میں پہنچ گیا۔ وہاں استاد برکت کام میں مصروف تھا۔
جتنی تیزی سے اس کے ہاتھ چل رہے تھے، اتنی ہی تیزی سے اس کی زبان بھی۔ ایک روز پہلے کسی نے ہنڈا ففٹی موٹر سائیکل لاکر وہاں کھڑی کی تھی جس کے ٹائر اور ٹیوب تبدیل کرنے تھے۔ برکت کے ساتھ ایک لڑکا اور تھا جس کا نام فیقہ تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ایک روز پہلے ٹھیلے پر بھی آیا تھا اور اسے دیکھ کر میں ٹھیلے کے نیچے چھپ گیا تھا۔
’’مستانے، بڑی دیر لگادی تونے۔‘‘ فیقہ بولا۔
’’ ابا کی ٹانگوں میں درد تھا۔ ٹھیلا میں نے ہی تیار کر کے دیا ہے۔‘‘ میں نے بات بنائی۔
’’ہاں یہ بیماریاں بڑی مصیبت ہوتی ہیں میرے بھائی۔ میرے ابا بھی بیمار ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں پر ساری ذمے داری ہے اور تیری تو سات بہنیں ہیں۔ تیرا کنبہ تو بہت بڑا ہے۔ اس نے افسوس کے ساتھ کہا۔
’’ کنبہ بڑا ہے، لیکن مجھے فکر کسی بات کی نہیں ہے۔‘‘ میں نے ہاتھ ہلا کر پرویز مستانہ کے انداز میں کہا۔
’’تیری اسی عادت کی وجہ سے تولوگ تجھے مستانہ کہتے ہیں۔ تو ہروقت مست رہتا ہے، اپنی کھال میں خوش۔‘‘ فیقہ نے کہا۔
میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچانک سڑک کی طرف سے آواز آئی:’’ او مستانے! کیا آج کام نہیں کرے گا؟ چار نمبر کا پانا لے کر آجا اور یہ نٹ تو ڈھیلے کر دے۔‘‘
یہ استاد رحمت کی آواز تھی اور مجھے اس کی مدد کرنی تھی مگر میں چار نمبر کا پانا کہاں تلاش کرتا۔ میں سوالیہ نظروں سے فیقہ کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے حیرت سے کہا: ’’تجھے کیا ہو گیا ہے مستانے؟ پانا ٹول بکس میں ہوگا ۔میری صورت کیا تک رہا ہے؟ ایک روز کی چھٹی میں سب کچھ بھول گیا؟ پرسوں تونے جہاں رکھا تھا، وہیں ہو گا۔‘‘
ٹول بکس کے بارے میں سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ عموماً چھوٹے موٹے ورک شاپوں میں اوزار لکڑی کے بکس میں بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دکان کے ایک کونے میں ایک کالا سا صندوق رکھا دکھائی دیا۔ میں نے جاکر اسے کھولا تو اندر بہت سے اوزار نظر آئے۔ مختلف سائز کے پانے، اسکریو ڈرائیور،ہتھوڑیاں اور پلاس وغیرہ۔
اگر صرف پانا اٹھانا ہوتا تو میں فوراً اٹھا لیتا، لیکن چار نمبر کا پانا کیسا ہوتا ہے یہ میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور میرا دل اندر ہی اندرکانپنے لگا کہ کہیں یہ راز نہ کھل جائے کہ میں نے مستانے کی جگہ لے رکھی ہے۔
فیقہ لوہے کی ایک سلاخ کو ہتھوڑی مارکر سیدھا کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر کہا: ’’چار نمبر کا پانا تو یہاں ہے ہی نہیں۔‘‘
’’ کمال ہے، یہاں سے کس نے نکالا؟‘‘ اس نے حیرت سے کہا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر صندوق کے قریب آیا اور اس نے ہاتھ ڈال کر سب اوزار الٹے پلٹے۔ پھر میری طرف ایک بڑا سا پانا بڑھاتا ہوا بولا: ’’یہ کیا ہے؟ کیا تیری آنکھوں میں فتور پیدا ہو گیا ہے؟‘‘
’’معلوم نہیں کیا بات ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا تھا۔‘‘ میں نے سر جھٹک کر کہا۔
’’مجھے تو تو آج کچھ بجھا بجھا سا اور بیمار لگ رہا ہے۔ رات زیادہ تو نہیں کھالیا تھا؟‘‘ اس نے طنزیہ کہا۔
’’بہت کہاں ہماری قسمت میں تو کم بھی نہیں ہے۔‘‘ میں نے کہا اور پانا لے جاکر استاد کو دے دیا۔ اس نے نٹ ڈھیلے کر کے نکالنے کا حکم دیا تو مجھے پسینا آگیا کیوں کہ میں نے زندگی میںاس سے پہلے یہ کام کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ دوسروں کی طرح دو ہاتھ پیر اور آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھیں، سمجھ بوجھ بھی عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں ایک دن میں موٹر سائیکل مکینک نہیں بن سکتا تھا۔ مستانہ نے بھی یہ ہنر برسوں میں سیکھا ہوگا۔
ایک چیز ہوتی ہے کامن سینس یعنی جو چیز سامنے ہے اسے کیوں اور کیسے کے اصولوں پر حل کیا جائے۔ میں نے اس اصول کو سامنے رکھ کر نٹ کھولنے شروع کیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ شروع میں مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ ہاتھ پیر گریس اور موبل آئل میں گندے ہوئے جارہے تھے۔ اس سے الجھن ہورہی تھی۔۔۔ پھر نٹ بولٹ ڈھیلے کرنے اور کسنے میں طاقت لگتی ہے جب کہ میں نے محنت اور مشقت کے کام اب تک نہیں کیے تھے۔ یہ بات نہیں کہ میںاس سے جی چراتا تھا بلکہ میرا اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔
میں کار ڈرائیونگ سے لے کر موٹر سائیکل ڈرائیونگ تک سب کچھ جانتا تھا مگر اس کے کل پرزوں سے نمٹنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حویلی میں مجھے کوئی ڈرائیونگ نہیں کرنے دیتا تھا۔ ماموں جان اور چچا جان کا سختی سے حکم تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں ڈرائیور کو ساتھ رکھوں۔
موٹر سائیکل چلانے کا شوق مجھے اسکول میں پیدا ہوا تو میں نے ایک دوست لڑکے سے موٹر سائیکل لے کر سیکھ لی۔ آج اتفاق سے یہ کام آرہا تھا، اس لیے کہ استاد نے موٹر سائیکل کے ٹائر اور ٹیوب تبدیل کرنے کے بعد مجھے حکم دیا کہ میں اس پر ایک راؤنڈ لگا کر آؤں۔ میں دیکھ چکا تھا کہ مستری لڑکے موٹر سائیکل پر ایم اے جناح روڈ اور اس کے اطراف میں راؤنڈ لگاتے پھرتے اور موٹر سائیکلوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔
میں نے دو راؤنڈ لے کر گاڑی گاہک کے حوالے کردی اور استاد کی طرف دیکھ کر سر ہلایا کہ گاڑی ٹھیک چل رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد دو پہر تک اسی طرح ہاتھ کالے کرنے کا کام ہوتا رہا۔ اس دوران مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئیں مگر میں ہوشیاری سے انھیں چھپاتا رہا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اناڑی ہوں۔
دوپہر کا کھانا سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہماری دکان کے مستریوں کے علاوہ اس میں دوسرے لڑکے بھی آکر شامل ہو جاتے تھے، لیکن مستانہ نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ٹھیلے پر جاکر کھاتا تھا یا پھر اپنے گھر چلا جاتا، اس لیے مجھے بھی ان دونوں جگہوں میں سے کہیں جانا تھا۔
بن کباب کھانے سے مجھے کوئی دل چسپی نہیں تھی ، لہٰذا میں گھر چلا گیا۔ اماں نے خاص طور پر میرے لیے نہاری بنائی تھی۔ فرش پر دسترخوان لگا تو سب نے کھانا شروع کیا۔ نہاری کھانے کا مجھے بہت شوق تھا اس لیے کہ لاہور میں وہ نصیب نہیں تھی۔ میں نے گرم گرم روٹی کے دو بڑے نوالے حلق سے اتارے تو اس وقت کچھ نہیں ہوا مگر تیسرے پر ہچکیاں بندھ گئیں۔ میری ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔
’’ لیجئے بھائی جان! پانی پی لیجئے۔‘‘ درخشاں نے مجھے ٹھنڈے پانی کا نقشین کلاس پیش کیا۔ میں نے غٹاغت کر کے گلاس خالی کردیا۔ چند لمحوں بعد کچھ سکون ہوا تو میں نے اٹھ کر تولیے سے ناک پونچھی:
’’اماں! آج نہاری میں چینی ڈالنا بھول گئیں۔‘‘ درخشاں نے شوخی سے کہا۔
’’بکواس بند کر بھینس کی خالہ۔ میرے لیے کوئی اور چیز لے کر آ۔‘‘ میں نے ناک سکیٹر کر زور سے کہا۔
دوسرے کمرے سے اماں کی آواز آئی:’’ کیوں؟ کیا نہاری نہیں کھائے گا ؟تجھے تو بہت شوق ہے ایسی چیزوں کا۔ باہر تو تو نہاری، حلیم اور پائے ٹھونس کر آتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟‘‘
میری سٹی گم ہوگئی اور کوئی بہانہ نہیں سوجھا ،مجبوراً میں نے اسی نہاری کو روٹی سے لگا لگا کر کھایا۔
’’شہزادے! آج تو بہت تکلف سے کھارہا ہے۔اسے اپنا گھر سمجھ کر کھا۔‘‘ ذکیہ آپا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
’’ ابھی اس لیے کم کھارہے ہیں کہ شام کو ہماری دعوت کریں گے بھائی جان۔‘‘ نگہت آرا نے شوشہ چھوڑا۔
میں نے منھ بناکر کہا:’’چپ رہ سوکھی ککڑی۔ تیری زبان بہت چلتی ہے۔ نگہت آرا کے بجائے تیرا نام نگہت آری ہونا چاہے تھا۔‘‘
’’بھئی دعوت کس چیز کی ہے؟‘‘ شائستہ بانو نے اچھل کر پوچھا۔
’’بروٹ۔۔۔ کیا کہتے ہیں، آج بھائی جان بروٹ کھلائیں گے۔نگہت نے کہا۔
’’بروسٹ کہتے ہیں احمق۔‘‘ فرزانہ نے اسے چپت رسید کی۔
’’ ہاں بروسٹ ٹھیک رہے گا۔ میں انار کلی سے جاکر لے آؤں گا۔‘‘ میں نے بے دھیانی میں کہا۔
آپا ذکیہ چونک گئیں: ’’انار کلی! بروسٹ لینے تم لاہور جاؤ گے؟ میں نے سنا ہے کہ انار کلی لاہور میں ہے؟‘‘
مجھے اچانک یاد آیا کہ میں کراچی میں کھڑا ہوں۔ میری دنیا اور میرا ماحول بدل چکا ہے۔ اب میں سلطان احمد کے بجائے پرویز مستانہ ہوں اور میرے سر پر ایک خاندان کا بوجھ ہے۔
’’ نہیں اتنی دور کیسے جاؤں گا؟‘‘ میں نے کہا۔ میری آواز بھرا گئی اس لیے کہ مجھے اماں یاد آنے لگی تھی۔ ان سے جدا ہوئے مجھے کافی دن ہوگئے تھے۔
’’میں اتنی دور نہیں جاسکتا۔ وہاں تک کا تو میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔‘‘
اس سے پہلے کہ حویلی کی یادیں اور اماں کی خوش بو مجھے پریشان کرتی اور میری آنکھیں بھیگ جاتیں، میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ دکان پر پہنچا تو میں نے لڑکوں کو خوش گپیاں کرتے دیکھا۔ کھانے کا وقفہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے وہ بات مسلسل پریشان کر رہی تھی جو صبح بھکاری بابا نے کی تھی۔ میں نے فیقہ کو ایک طرف لے جا کر کہا: ’’بھائی رفیق! ایک بات بتانا۔ تم مجھے اس دکان پر کب سے دیکھ رہے ہو؟‘‘
اس نے حیرت سے کہا: ’’پانچ سال سے! کیوں؟ کیا تیری یادداشت میں کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے؟‘‘
میں نے کہا: ’’ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کہاںتھا؟‘‘
اس نے سوچ کر کہا: ’’اپنے گھر میں ہو گا اور کہاں ہو سکتا ہے۔ ہم سب اپنے گھروں سے آتے ہیں۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے آج؟‘‘
’’ اپنے گھروں سے آتے ہیں، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہ میرا گھر نہیں ہے۔ وقار قریشی میرے ابا نہیں ہیں۔ وہ مجھے کہیں سے لائے ہیں۔‘‘
اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا:’’یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے! میں تو تجھے بہت پہلے سے یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات تجھے کس نے بتائی؟‘‘
میں نے سر ہلا کر کہا: ’’کسی نے بھی بتائی ہو مگر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔‘‘
’’اس کے بارے میں۔۔۔ اس کے بارے میں تو تجھے بوا ر حیمن ہی صحیح بتاسکتی ہیں۔ وہ بہت عمر کی ہیں اور اس علاقے کی پوری معلومات رکھتی ہیں۔ تمام گھروں کا کچا چٹھا انہی کو معلوم ہے۔‘‘
میں نے بے ساختہ پوچھا: ’’وہ کہاں رہتی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔‘‘
’’ کل۔۔۔ کل نہیں پرسوں میں تجھے ان کے ہاں لے چلوں گا۔‘‘ فیقہ نے وعدہ کیا۔
میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔
شام کو کام ختم کرکے میں نالے کی طرف واپس آرہا تھا کہ مجھے اچانک چار پانچ لڑکوں نے گھیرلیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھوٹے بڑے ڈنڈے تھے اور ان کے تیور خطرناک نظر آتے تھے۔ سب سے آگے قاسم دادا تھا۔ اس نے کہا:’’ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تو نے تین روز پہلے ٹرانزسٹر غائب کیا تھا۔ اب سیدھی طرح سے میرا کمیشن نکال دے ورنہ۔۔۔‘‘
اس نے دھمکی آمیز انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خود کو اتنے لڑکوں میں گھرے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہوگئے۔ میں نے تو آج تک چڑیا کا بچہ تک نہیں مارا تھا۔ میں ان مسٹنڈوں کا مقابلہ کیسے کرتا؟ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔
اب پرویز مستانہ کی زبانی سنیے
میں رائتے میں لت پت تھا اور میری زبان سے نکل رہا تھا: ’’اسے۔۔۔ اسے۔۔۔ پکڑ لو۔۔۔یہ۔۔۔ قاتل ہے۔‘‘
کھانے کی میز پر جتنے لوگ موجود تھے وہ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ شاید میں کرسی سے اٹھ جاتا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن میرے برابر بیٹھے ہوئے لڑکے نے کہا:
’’بھائی جان! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اپنا مالی ہے ،دینو۔ کھانے کے وقت پھول لاکر گل دان میں سجادیتا ہے۔ اس وقت بھی پھول لے کر ہی آیا ہے۔‘‘
ا ب جو میں نے دیکھا تو واقعی وہ پھول لے کر آیا تھا۔ میں حقیقت میں اس لیے ڈر گیا تھا کہ اس نے سلطان احمد پر حملہ کیا تھا یا شاید اس کے کمرے میں خنجر لے کر گھس آیا تھا اور سلطان کو اس کی وجہ سے بھاگ کر کراچی جانا اور مجھے اس کی جگہ لاہور آنا پڑا مگر یہ بات تو سلطان کو یا پھر مجھے معلوم تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں ایک انکشاف کردیا تھا اور خود پر قابونہیں رکھ سکا تھا۔
فوزیہ نے شوخی سے پوچھا: ’’آپ نے اسے قاتل کیسے کہہ دیا بھائی جان؟ میں بے چارہ تو مکھی بھی نہیں مار سکتا۔‘‘
میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا:’’شاید میں ابھی تک خواب دیکھ رہا ہوں اور پرستان سے واپس نہیں آیا۔‘‘
ماموں گلزار چونکے: ’’پرستان؟ یہ پرستان کا کیا قصہ ہے؟‘‘
میں نے بات بنائی: ’’تین روز سے میں وہیں تھا ماموں جان اور میں نے اس مالی کے بچے کو وہاں مکھیوں کا قتل عام کرتے دیکھا تھا۔ یہ ڈیڑھ لاکھ مکھیوں کا قاتل ہے۔‘‘
’’ا فوہ! آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا بھائی جان!‘‘ راحیلہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس کے بال لڑکوں جیسے تھے اور سلطان نے اس کی یہی شناخت بتائی تھی۔ ’’آپ نے تو رائتے کا برتن ہاتھ سے گرا کر ایسی اداکاری کی کہ میں تو دینو بابا کو واقعی قاتل سمجھ بیٹھی تھی۔‘‘
سب لوگ پھر اپنی اپنی پلیٹوں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ایک ملازم نے صاف کپڑے سے میرا شب خوابی کا لبادہ صاف کردیا۔ مالی نے گل دان میں پھول سجائے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا اور اپنا ایک پاؤں گھسیٹتا ہوا وہاں سے لان کی طرف چلا گیا۔ معلوم نہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میری بات پر یقین آیا تھا یا نہیں۔ میری تو آنتیں قل ھو اللہ پڑھ رہی تھیں، اس لیے میں بریانی پر ٹوٹ پڑا۔ جب پیٹ کا ایک کونا اچھی طرح سے بھر گیا تو میں نے دوسری چیزوں کی طرف توجہ کی۔ مرغ روسٹ، چٹنی، دہی، کباب اور میٹھے میں زردہ، فیرنی سب ہی کچھ تو وہاں موجود تھا جسے میں اپنے معدے میں اتارنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سب میری طرف دیکھ رہے اور میری تمام حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے، اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا ورنہ اس وقت میز صاف کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ سلطان نے بتایا تھا کہ وہ موٹا ہونے سے ڈرتا تھا اس لیے کم کھاتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مہینوں بعد ایسی نعمتیں میرے سامنے ڈھیر کردی تھیں، میں انہیں کیسے چھوڑ دیتا۔ کھانے کے بعد میں نے پانی پی کر ایک لمبی سی ڈکار لی اور پھر فیرنی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک پلیٹ تو چکھنے میں ختم ہوگئی۔ دوسری پر ذائقے کا صحیح اندازہ ہوا۔ تیسری میں نے مزہ لے لے کر کھائی۔
’’بھائی جان! فیرنی آپ کو آج کچھ زیادہ ہی پسند آگئی۔ ‘‘سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا۔ اس نے بالوں میں بہت سا تیل چپڑ رکھا تھا۔ بیچ سے مانگ نکال کر چٹیا باندھی ہوئی تھی اور موٹے شیشوں والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔مجھے یاد آگیا وہ چچا زاد بہن ثوبیہ تھی!
’’کیا میرے فیرنی کھانے پر کوئی پابندی ہے ثوبیہ؟‘‘ میں نے چوتھی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا: ’’مجھے کھاتا دیکھ کر تمھیں خوشی نہیں ہو رہی ہے؟‘‘
’’نن۔۔۔ نہیں تو۔۔۔‘‘ ثوبیہ ہکلائی اور جھینپ سی گئی۔
’’اسے حیرت یوں ہورہی ہے کہ میٹھا تو آپ دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔‘‘ فوزیہ نے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا۔
’’اچھا ہاں، مگر کبھی کبھی دوسروں کا حصہ بھی کھانے کو دل چاہتا ہے۔‘‘ میں نے کہا۔
کھانے کے دوران دل چسپ باتوں کا سلسلہ جاری رہا مگر ماموں جان اور چچا جان سنجیدگی اور خاموشی سے مجھے گھورتے رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس موقع پر ذرا بھی کم زوری دکھائی تو میرا راز کھل جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا اس لیے مجھے اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کھانے کے بعد تمام کام گردن اکڑا کر با رعب طریقے سے کیے۔ کھانے کے کمرے میں واش بیسن لگا تھا جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کے نلکے لگے تھے۔ میں حیران تھا کہ نلکے میں سے مسلسل گرم پانی کیسے گر رہا ہے؟ اس پانی کو کون گرم کر رہا ہے؟ کراچی میں، میں حمام میں نہا چکا تھا مگر وہاں تو حمام والا بالٹی میں گرم پانی لا کر ڈال دیتا تھا۔ یہاں تو سب چیزوں کی بہت آسانی تھی!
اس رات میں نے اتنا کھالیا تھا کہ مجھ سے چلا نہیں جارہا تھا۔ میں زینے چڑھ کر اوپر جانے لگا فوزیہ اور راحیلہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کیے۔ پھر فوزیہ نے مجھ سے کہا: ’’بھائی جان آج کھیلئے گا نہیں؟‘‘
میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا کہ سلطان احمد کھانے کے بعد کیا کھیلتا ہو گا؟ کیرم، لوڈو، شطرنج؟ میں نے سوچا کہ فوراً ہی کوئی جواب نہیں دینا چاہے ورنہ پول کھل جائے گی۔
’’ ایک سیٹ کھیل لیجیے ۔ کھانا ہضم ہو جائے گا۔‘‘ وہ بولی۔
میرا ذہن اور چکراگیا۔ سیٹ کھیل لیجئے، مگر کس چیز کا؟ میں زیادہ دیر تک وہاں ہونقوں کی طرح منہ کھولے کھڑا رہتا تو اس صورت میں بھی وہ شبہے میں مبتلا ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا: ’’ہاں آؤ ایک سیٹ کھیل لیتے ہیں۔‘‘
میں مڑا اور زینہ اترنے لگا۔ فوزیہ نے پھر حیرت کا اظہار کیا، بولی: ’’کیا نائٹ گاؤن میں بیڈ منٹن کھیلیں گے؟‘‘
’’ بیڈ منٹن!‘‘ یہ لفظ سن کر میں نے خود کو شاباش دی کہ اس ترکیب سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت کیا کھیلنا چاہتی ہے۔ ’’اوہ ہاں، اچھا ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔‘‘ میں نے کہا ۔پھر مڑ کر زینہ چڑھا اور راہ داری طے کرکے اپنے سونے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ فوزیہ پلٹ کر نیچے چلی گئی۔
میں نے کمرے میں جاکر کپڑوں کی الماری کھولی تو انتخاب پھر دشوار ہو گیا۔ ذہن نے سوال کیا کہ اس وقت کیا پہننا مناسب رہے گا؟ میں خوب صورت سا پتلون اور جیکٹ پہننے والا تھا کہ اچانک میری نظر بائیں طرف گئی۔ وہاں سلطان احمد کی فریم شدہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ سفیدپٹی دار پتلون اور آدھی آستین والی سفید قمیص پہنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیڈ منٹن کاریکٹ تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔
بالکل میری شکل، ہو بہو میرا عکس معلوم ہوتا تھا جیسے میں تصویر نہیں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا: ’’ہاں ٹھیرو، آ رہا ہوں۔‘‘
میں نے غسل خانے میں جاکر کپڑے بدلے اور سفید کرمچ کے جوتے پہن کر باہر آگیا۔ دروازے پر احمد کھڑا تھا۔ میری طرح کا لباس پہنے اور ہاتھ میں ریکٹ لیے ہوئے۔ خیال آیا کہ میں نے ریکٹ تو لیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بار اور کمرے میں جانا پڑا۔
احمد اپنی دونوں بہنوں راحیلہ اور فوزیہ سے چھوٹا تھا اور اس کی رنگت گندی تھی۔ اس کی دائیں بھوں پر زخم کا ایک ترچھا نشان تھا۔ شکل و صورت سے وہ نرم طبیعت کا اور ذہین لگتا تھا۔ جب ہم راہ داری کو طے کر رہے تھے تو اس نے کہا:
’’ بھائی جان! میں کچھ عجیب سی بات محسوس کر رہا ہوں۔‘‘
’’وہ کیا؟‘‘ میں نے ریکٹ ہلاتے ہوئے پوچھا۔
’’ آپ جب سے پرستان سے واپس آئے ہیں کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ ہیں تو آپ سلطان بھائی، مگر اس کے باوجود سلطان نہیں کچھ اور لگ رہے ہیں۔‘‘
میں نے سنجیدگی سے کہا: ’’پرستان والی بات تو مذاق ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اور انھوں نے مجھ پر تشدد کیا تھا تاکہ ماموں سے بھاری تاوان وصول کرسکیں۔ میں ان لوگوں کے پاس سے کسی نہ کسی طرح سے بھاگ آیا۔ جب سے میری یادداشت کچھ چوپٹ ہوگئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھول گیا ہوں۔‘‘
’’ اوہ! آپ نے پہلے کیوں نہیں۔۔۔‘‘اس نے بے چین ہو کر کہنا چاہا۔
لیکن میں نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا: ’’یہ ایک راز ہے جو میں نے تم کو بتادیا ہے اس لیے کہ میں تمیں اپنا سمجھتا ہوں۔ اسے اپنے تک رکھنا۔‘‘
’’وہ۔۔۔وہ۔۔۔لیکن۔۔۔‘‘ اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا ہو رہے تھے۔
’’بس میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔‘‘ میں نے ڈپٹ کر کہا۔
میری ڈانٹ کھا کر وہ خاموش ہوگیا۔
شکر ہے کہ وہ اس وقت ساتھ تھا ورنہ حویلی کا لان اور پھر بیڈ منٹن کورٹ تلاش کرنے میں وقت لگتا اور اس میں کوئی گڑبڑ بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ جس جگہ بیڈ منٹن کھیلی جاتی تھی وہ پختہ جگہ تھی اور فرش پر سفید لکیریں پڑی تھیں۔ بیچ میں جال تنا ہوا تھا اور دو طرف کھمبوں پرتختے لگے تھے جن پر بہت سے بلب لگے تھے۔ ان بلبوں سے دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی اورفرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔
دائیں طرف کچھ فاصلے پر گردے کی شکل کا ایک سوئمنگ پول تھا جہاں سے شڑپ شڑپ کی ہلکی آوازیں آرہی تھیں جیسے کوئی تیر رہا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون تیر رہا ہے؟ حیرت صرف اس بات پر نہیں بلکہ وہاں ہر بات پر حیرت ہورہی تھی۔ بڑا شان دار اور فلمی سا ماحول تھا۔ ہر چیز جگمگاتی ہوئی۔ مجھے تو وہاں قدم رکھتے اور کسی چیز کو چھوتے ہوئے یہ اندیشہ رہتا تھا کہ میلی نہ ہو جائے۔
بہرحال کھیل شروع ہوا۔ بیڈ منٹن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھیلا تھا، اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیسی پریشانی سے دوچار تھا۔ زاہد، ثوبیہ ایک طرف تھے یعنی ہمارے مخالف اور دوسری طرف میں اور فوزیہ۔
ایک تو میں کھیل نہیں جانتا تھا دوسرے یہ کہ میں نے کھانا خوب ڈٹ کر کھایا تھا، اس لیے ہاتھ پاؤں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے شاٹ مارا مگر ریکٹ سے شٹل کاک کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس پر خوب قہقہے بلند ہوئے۔ فوزیہ جھنجلا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں سلطان احمد جو کہ ایک بہترین کھلاڑی تھا آج ٹھیک طرح سے شاٹ کیوں نہیں لگا رہا ہوں اور میں نے اپنے مخالفوں کے اتنے پوائنٹ کیوں بنوادیے؟ اس بے چاری کو کیا معلوم کہ سلطان احمد تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جگہ اس کے ہم شکل پرویز مستانہ نے لے رکھی ہے۔
ایک بار جو چڑیا (شٹل کاک) پر شاٹ لگانے کے لیے میں نے ریکٹ چلایا تو وہ شائیں سے فوزیہ کے سرپر سے گھوم گیا۔ فوزیہ نے بچنے کے لیے جھکنا چاہا تو مجھ سے ٹکراگئی جب کہ چڑیا اس کی ناک پر گری۔ دھکا لگنے سے میں بھی گر گیا۔ پھر فوزیہ کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں سنبھل کر اٹھا اور میں نے سہارا دے کر فوزیہ کو بھی اٹھایا۔
’’یہ آپ کیسے ہاتھ چلا رہے ہیں؟ اگر میں جھک نہ جاتی تو میری کھوپڑی ہی اڑ جاتی۔ جائیے میں نہیں کھیلتی آپ کے ساتھ۔‘‘ فوزیہ چنچنائی۔
’’بکواس نہ کرو۔ میں خود بھی تمھارے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا۔‘‘ میں نے مصنوعی غصے سے کیا اور ریکٹ ہلا تا ہوا سو ئمنگ پول کی طرف چلا گیا۔ سارے بہن بھائی مجھے آوازیں دیتے رہ گئے۔
تیراکی کے تالاب میں چچا رحمت تیر رہے تھے بلکہ تیر چکے تھے۔ وہ تالاب سے باہر نکل آئے تھے اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔
’’ ر یگی۔۔۔ریگی۔۔۔ تولیا دینا۔‘‘ انھوں نے بلند آواز سے کہا۔
میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی ملازم کو حکم دے رہے ہیں مگر اس وقت میری روح فنا ہوگئی جب میں نے ایک کتے کی غراہٹ سنی۔ پھر جب وہ نظر آیا تو حقیقت میں میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ کتا اپنے منھ میں تولیا دبائے ہوئے تھا اور ملازموں کے کوارٹروں کی طرف سے آرہا تھا۔ اس کتے کے بارے میں سلطان احمد نے بتایا تھا کہ وہ مرچکا ہے، حال آنکہ وہ زندہ تھا۔ وہ اچھلتا کودتا تالاب کے قریب آیا تو اتفاق سے میری طرف سے آیا۔ اس طرح سے میں اس کے راستے میں آگیا۔ کتا ایک لمحے کو ٹھٹکا ،پھر اس نے تولیا منھ سے گرادیا اور غراتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگادی۔ میں دھکا کھا کر گھاس پر گر گیا اور وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔
’’ غاؤں۔۔۔غاؤں۔‘‘ وہ غرایا۔ اس کے دانت نوک دار اور پنجے دھار دار تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر اس نے مجھے کاٹ لیا تو میرے پیٹ میں چودہ لمبے انجکشن لگیں گے۔
میں خوف سے کانپنے لگا اور میں نے اپنی آنکھیں بند کرلیں۔
اب سلطان احمد کا حال سنئے۔
میری زندگی ایک بار پھر آزمائش سے دو چار تھی!
میں یہ سوچ کر لاہور سے کراچی آیا تھا کہ یہاں مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا اور میں سکون سے زندگی گزاروں گا مگر یہاں تو جان پر بن آئی تھی۔ قاسم دادا اور رمضانی کے علاوہ وہ تعداد میں تین تھے جنھوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ قاسم دادا اور رمضانی اس طرح ایک طرف کھڑے تھے جیسے لڑائی بھڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہوں۔
پرویز مستانہ ایک نڈر اور بے خوف لڑکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں جھیلی تھیں جب کہ میں نے ابھی تک زندگی کا ایک رخ دیکھا تھا اور عیش میں وقت گزارا تھا۔ میں بھلا ان لڑکوں کا مقابلہ کیسے کرتا؟
پیچھے ہٹنا اور انھیں پیٹھ دکھانا بزدلی تھی۔ میرے ہم شکل پرویز مستانہ نے اس علاقے میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ اگر میں کم زوری دکھاتا تو وہاں کے لڑکے شیر ہو جاتے اور بات بات پر مجھے آنکھیں دکھاتے لہٰذا بہتر یہی تھا کہ میں ان سے مقابلہ کرتا اور انھیں ایسا سبق دیتا کہ وہ آئندہ میرے مقابلے پر آنے کی کوشش نہ کرتے۔
وہ سب چوکنے تھے! میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ قریب ہی کیلے کا ایک چھلکا پڑا تھا۔ کسی نے کیلا کھا کر بد تمیزی سے چھلکا سڑک پر پھینک دیا تھا۔
پہلا لڑکا جوں ہی ڈنڈا گھماتا حلق سے خوف ناک آوازیں نکالتا ہوا میری طرف بڑھا، میں نے تیزی سے کیلے کا وہ چھلکا سڑک سے اٹھا کر اس کے پاؤں کے سامنے پھینک دیا۔ اس کا پاؤں چھلکے پر پڑا اور وہ بری طرح پھسل گیا۔
بس پھر ایک ایسی آواز آئی: ’’ار۔۔رڑ۔۔۔دھم۔۔۔بچاؤ۔۔۔بچاؤ۔۔۔مرگیا۔‘‘
وہ دھم سے سڑک پر گرا تھا اور’’ بچاؤ بچاؤ مرگیا‘‘ اس کے حلق سے نکلا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کی پیٹھ اور کولھوں میں چوٹ لگی ہے۔
دوسرا لڑکا یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا ،مگر دادا قاسم کے جوش دلانے پر آگے بڑھا تو میں پھرتی سے قریبی دکان کی طرف چلا گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس طرف آیا اور اس نے اپنا ڈنڈا گھما کر میرے سر پر مارنا چاہا تو میں نے دکان میں رکھے کھلے ڈبے میں سے ایک مٹھی پسی ہوئی مرچ اٹھالی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں جھونک دی۔
’’ آئے ہائے مار ڈالا مستانہ کے بچے‘‘ اس نے حلق سے بلبلاتی آواز نکالی اور وہ ڈنڈا ایک طرف پھینک کر اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ آنکھیں ملنے سے مرچ اور تیز لگی، اس لیے وہ تیز آواز میں چیخنے چلانے لگا اور مجھے کوسنے لگا۔
تیسرا لڑکا کسی بھینسے کی طرح فوں فوں کرتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے میری ٹھوڑی پرمکا مارنا چاہا مگر بالکل آخری لمحے میں، میں ایک طرف ہوگیا اور میں نے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا دی اور وہ آواز کے ساتھ دکان میں رکھے مٹی کے تیل کے ڈرم میں گر گیا۔ڈرم کھلا ہوا تھا اور تیل اوپر تک بھرا ہوا تھا اس لیے وہ اس میں غوطہ کھا گیا۔
وہ سنبھل کر ڈرم سے نکلا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس کی آنکھ، منھ اور ناک میں مٹی کاتیل گھس گیا تھا اور وہ تیل کی کلیاں کر رہا تھا۔
دکان والے نے جو اپنا تیل ضائع ہوتے دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے لنگی سنبھالتا ہوا اٹھا اور اس نے کرخت آواز میں کہا: ’’بھاگو یہاں سے کم بختو، کیا اودھم مچا رکھا ہے؟ شرفو! یہ تو مٹی کے تیل میں کیوں نہا رہا ہے؟ اگر کسی نے ماچس کی تیلی جلا کر تجھ پر پھینک دی تو جل بھن کر
کباب بن جائے گا۔‘‘
وہ لڑکا شرفو یہ سن کر گھبرا گیا اور وہاں سے ’’اوع۔۔۔ اوع‘‘ کرتا ہوا بھاگ گیا۔ مٹی کا تیل منہ میں چلے جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت متلا رہی تھی۔
اب رہ گئے تھے دادا قاسم اور رمضانی، رمضانی وہی لڑکا تھا جس نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ میری جگہ مستانہ ہوتا تو جھٹ اس کا گریبان پکڑ لیتا اور گال پر دو طمانچے مار کر پوچھتا کہ بتا تو نے مجھے چوری کرتے کب دیکھا ہے؟ لیکن میں صاف ستھرے ماحول میں رہا تھا اور میں نے اب تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے میں جھجک گیا۔ پھر بھی میں نے بے خوفی دکھاتے ہوئے اس کے سر کے بال پکڑ لیے اور اس کے سر کو جھٹکا دے کر گونج دار آواز میں کہا: ’’کیوں، تجھ سے کس نے کہا تھا کہ میں نے ریڈیو چوری کیا ہے؟‘‘
’’مجھ سے تو فیاض کہہ رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا اس لیے میں نے دادا کو بتاد یا۔‘‘ اس نے مری مری سی آواز میں کہا۔
’’ دادا! اب تم کیا کہتے ہو؟‘‘ میں نے قاسم کی طرف مڑ کر کہا جو ایک خالی ٹھیلے سے ٹیک لگائے گھاس کا ایک تنکا چبا رہا تھا۔
’’ میں کیا کہوں، میں تو رمضانی کے بہکاوے میں آگیا تھا۔ بہر حال چلو معاملہ ختم کرو!‘‘ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔
’’تم نے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیا نا؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’ہاں۔‘‘ اس نے سر ہلا کر کہا، پھر رمضانی کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا:’’ چلو بھاگو یہاں سے خواہ مخواہ ہنگامہ کرادیا تم نے۔‘‘
رمضانی مردہ دلی سے ایک طرف اور دادا دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگر میں بزدلی دکھاتا تو وہ سب میرا پیچھا کر رہے ہوتے۔
میں اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ پرویز مستانہ کس کا بیٹا ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اپنی جھگی کی طرف جارہا تھا کہ دائیں جانب سے ایک اول جلول قسم کا آدمی اچانک میرے سامنے آگیا۔ وہ اس طرح سے سامنے آکھڑا ہوا تھا کہ راستہ رک گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنائیت سے میرا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا:
’’ تم۔۔۔تم۔۔۔مستانہ۔۔ پرویز مستانہ ہو نا؟‘‘
’’ہاں، لیکن تم کون ہو اور میرے آگے آکر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟‘‘ میں نے پوچھا۔
اس آدمی کی عمر پچاس سال ہوگی۔ وہ پستہ قد اور بھاری بھر کم تھا۔ اس کے بائیں کان کی لو میں ایک بالا پڑا ہوا تھا اور ناک توتے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت چمکیلی سیاہ تھی اور آنکھیں بالکل سفید۔ اگر میں اسے رات کو دیکھ لیتا تو یقینا ڈر جاتا۔
’’ڈیوڈ مسیح۔‘‘ اس نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا:
’’میرا نام ڈیوڈ مسیح ہے۔ تو مجھے نہیں جانتا مگر میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔‘‘
میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔
کیا اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔
’’ تیرا باپ بہت بڑا آدمی تھا مگر اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا تو میں نے اس کے بیٹے کو اس سے چھین لیا۔ اس نے جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ بس تو پھر۔۔۔‘‘وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی گردن سہلانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی سے ڈرا ہوا ہے۔
میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے مستانہ کے والد قریشی صاحب آتے دکھائی دیے۔ قریب اگر انھوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا پھر ٹٹول کر دیکھا اور پریشانی سے پوچھا:
’’ مستانہ! تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ گل بدن بتا رہی تھی کہ تیرا تین چار لڑکوں سے زبر دست جھگڑا ہو گیا تھا؟‘‘
’’مجھے کچھ نہیں ہوا با۔‘‘ میں نے انھیں اطمینان دلایا۔
’’یہ۔۔۔ یہ کون ہے؟‘‘ وہ چونک کر ڈیوڈ مسیح کی طرف مڑے۔ اسے دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے۔ پھر انھوں نے آنکھیں مسل کر غیر یقینی سے کہا:
’’کک۔۔۔ کیا۔۔ تم ڈیوڈ ہو، مگر تم تو جیل میں تھے۔ تمھیں تو سزا ہوگئی تھی؟‘‘
’’ ہاں پورے چودہ سال کی قید کاٹ کر آیا ہوں۔‘‘ اس نے اطمینان سے کہا اور اپنی سفید جھالر دار مونچھوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ پھر وہ بولا:
’’اب میرا بیٹا مجھے واپس کر دے قریشی۔ میں کب سے اس کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔‘‘
’’نن۔۔۔نن۔۔۔ نہیں۔۔۔چلا جا یہاں سے۔۔۔چلا جا۔‘‘ ابا نے کانپتی آواز میں کہا اور مجھے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔
میں حیرت سے سوچنے لگا کہ ڈیوڈ مسیح کا بیٹا قریشی صاحب نے کیوں لے لیا اور اب مجھے اتنی زور سے کیوں بھینچ رہے ہیں؟
اب پر ویز مستانہ کی کہانی اسی کی زبانی سنئے۔
ریگی صاحب کے دانت نوکیلے اور پنجے دھار دار تھے۔ ان کی لمبی زبان لپلپا رہی تھی اور وہ پینترا بدل کر مجھ پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ چچا نے ڈانٹ کر کہا:
’’ اے ریگی !ہٹو کیا بد تمیزی ہے۔ احمق کہیں کے تم سلطان احمد کو بھی نہیں پہچان رہے ہو۔‘‘
حویلی کے لوگ دھوکا کھا چکے تھے کہ میں سلطان احمد ہوں مگر یہ دھوکا ریگی نے نہیں کھایا تھا۔ وہ جانور تھا اور دوست دشمن کی پہچان رکھتا تھا، اس لیے اس نے مجھے دبوچ لیا تھا۔
دوسری طرف سلطان احمد کے جو بھائی بہن بیڈ منٹن کھیل رہے تھے جب انھوں نے ریگی کو بے تحاشا بھونکتے اور میری خاطر تواضع کرتے دیکھا تو وہ شور غل مچاتے ہوئے وہاں آگئے۔ سب نے دھکا دے کر ریگی کو میرے اوپر سے ہٹایا۔ فوزیہ تو اس معاملے میں ریگی سے اتنی ناراض ہوگئی تھی کہ اپنے ریکٹ سے ریگی کی دھنائی کرنے والی تھی مگر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا:
’’جانے دو فوزیہ! جانور ہے! بے چارہ نا سمجھ ہے۔ پھر دو روز پہلے تو ہسپتال سے آیا ہے۔‘‘
’’ ہسپتال سے! وہ کیوں؟‘‘ میں نے چونک کر پوچھا۔ سلطان احمد نے تو مجھے بتایا تھا کہ کسی شخص نے اس کے کتے ریگی کو کوئی زہریلی چیز کھلا کر مار ڈالا ہے۔
’’ ریگی نے کوئی خراب چیز کھا لی تھی۔ شاید باسی کلیجی وغیرہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگئی تھی، اس لیے اسے ہسپتال لے جانا پڑا تھا ۔ کلیجی کھانے سے اس کا منھ سرخ ہوگیا تھا۔ پہلے ہم لوگ یہ سمجھے کہ اس کے پیٹ سے خون نکل رہا ہے اور یہ بچ نہیں سکے گا، لیکن ہسپتال لے جانے پر معلوم ہوا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ‘‘زاہد نے وضاحت کی۔
میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا:
’’ اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوگئی ہے۔ اس کے دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے اور یہ مجھے بھی نہیں پہچان رہا ہے۔‘‘
ریگی عف عف کرتا ایک طرف چلا گیا تو زاہد نے کہا:
’’بھائی جان! آپ نے ہی اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اسے ناشتے میں خالص دودھ اور کھانے میں دو کلو قیمہ کھلاتے ہیں۔ کل سے اسے بھوسی ٹکڑے کھلائیں گے تو خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے آجائے گا۔ عمدہ اور روغنی کھانے کھا کر اس کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے۔‘‘
’’ٹھیک ہے میں کوئی ترکیب سوچوں گا۔‘‘ میں نے سر جھٹک کر کہا۔
یہ بات میں نے ایسے ہی کہہ دی تھی۔ ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس خوں خوار کتے کو اپنا دوست بنانے کی کوئی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ رات سونے سے پہلے میں اماںکے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔
وہ تھوڑی دیر پہلے عشا کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں اور اب تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میرے قدموں کی چاپ سے انھوں نے سر اٹھایا اور گہرا سانس لینے کے بعد بولیں:
’’ اچھا تو ہے۔ بیٹا آجا۔۔۔ آجا میرے لعل۔‘‘
میں سیدھا ان کے قریب پہنچا تو انھوں نے مجھے آغوش میں لے لیا پھر میری پیشانی کا بوسہ لے کر بولیں:
’’اللہ میاں بھی بعض وقت بڑے دل چسپ امتحان لیتا ہے۔ اب دیکھو کہ پہلا نظروں کے سامنے تھا تو دوسرے کے لیے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ دوسرے کو قدرت نے ملا دیا تو پہلے کو غائب کر دیا۔ اب اس کی یاد سے دل بے چین ہے۔ مالک کے کھیل بھی نرالے ہیں۔‘‘
’’میں سمجھا نہیں اماں! آپ کیا کہہ رہی ہیں؟‘‘
’’ کسی اور وقت سمجھا دوں گی۔ ابھی تو میں خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی ہوں۔‘‘ انھوں نے ٹالنے والے انداز سے کہا:’’ تو بتا کیسے آگیا اس وقت، کیا کوئی الجھن اور دشواری پیش آگئی ہے؟‘‘
’’ہاں۔ وہ کتا ہے گیگی۔۔۔ نہیں وہ بیگی۔۔۔ کیا نام ہے اس کا۔۔۔‘‘ میں اٹکنے اور دماغ پر زورڈالنے لگا۔
’’ ریگی۔‘‘ انھوں نے یاد دلایا۔
’’ ہاں، ریگی میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔‘‘ میں نے اماں کے کان میں کہا۔
انھوں نے سرہلایا: ’’ہوں! اس جانور کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ اس نے حقیقت جان لی ہے ،مگر فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انھوں نے میرے کان میں کہا:
’’سلطان ایک خاص قسم کی خوش بو لگا کر اس کے قریب جاتا تھا۔ وہ خوش بوریگی کو بہت پسند ہے۔ اگر تو بھی وہ خوش بو لگانا شروع کر دے تو وہ تجھ سے قریب ہو جائے گا۔ پھر جب تو اسے تینوں وقت اپنے ہاتھ سے کھانا دے گا تو وہ چند ہی دنوں میں تیرے سامنے دم ہلانے لگے گا۔‘‘
میں نے سر ہلایا: ’’اچھا ٹھیک ہے مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔‘‘
وہ حیرت سے بولیں:’’ ڈر لگتا ہے! میں تو سمجھی تھی کہ تو بہت بہادر ہے، نڈر ہے اور۔۔۔‘‘
’’ہاں بہادر تو میں ہوں اماں۔‘‘ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا اور انھیں جملہ مکمل نہیں کرنے دیا :’’میں نے محلے میں اپنا سکہ جمایا ہوا ہے۔‘‘
میں شیخی میں معلوم نہیں اور کیا کیا باتیں کرتا رہا، نیند میرے دماغ کو جکڑ رہی تھی۔
’’ میرے بچے! تجھے نیند آرہی ہے۔‘‘ انھوں نے میرا سر سہلا کر کہا: ’’جا اپنے کمرے میں جا کر سوجا۔ صبح تجھے اسکول بھی جانا ہے۔‘‘
میں اماں کے کمرے سے نکل آیا اور لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو یہ خیال پریشان کر رہا تھا بلکہ ہیجان میں مبتلا کر رہا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان احمد پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اگر میں چوکنا نہیں رہوں گا تو صبح حویلی والوں کو میری لاش ملے گی۔
میں نے دروازہ اور کھڑکیاں اچھی طرح سے بند کر لیں تو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس وقت یاد آیا کہ وہ کمرا ائیر کنڈیشنڈ ہے۔ میں نے اسے چالو کر دیا۔ سلطان احمد نے بتایا تھا کہ اگر مجھے نیند نہ آئے تو میں گھنٹی بجا کر ملازم کو بلاؤں اور اپنے لیے گرم دودھ منگوا لوں یا پھر سرہانے رکھے ہوئے ٹیپ رکارڈر پر موسیقی کا ٹیپ لگا دوں، مگر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور مجھے خوف اور دہشت کے باوجود نیند آگئی۔
صبح سویرے آنکھ کھلی تو میں نہایا اور شلوار قمیص پہن کر تیار ہوگیا۔ اس وقت یاد آیا کہ اماں نے ہدایت دی تھی کہ ریگی صاحب کو اپنے ہاتھ سے ناشتا کرانا ہے تاکہ ان سے دوستی ہو سکے۔۔۔ اور ہاں اماں نے ہدایت دی تھی کہ میں ریگی کی پسندیدہ خوش بو بھی لگا لوں۔
میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جاکر پرفیوم کی شیشی اٹھانا چاہی تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہاں دس بارہ قسم کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی تھیں۔ دماغ چکرا کر رہ گیا کہ اس میں ریگی کو کون سی پسند ہے۔
جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ایک شیشی اٹھائی اور کرتے پر اس کا اسپرے کر لیا۔ میرے جسم سے گلاب کی بھینی بھینی اور مسحور کن خوش بو آنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ ریگی میاں بھی مست ہو جائیں گے۔
میں نے سوچا کہ ریگی کے سامنے یوں اکیلے جانا مناسب نہیں رہے گا۔ بہتر ہو گا کہ میں کسی بھائی بہن کو ساتھ لے لوں۔ میں فوزیہ کے کمرے کی طرف جانے لگا تو راہ داری میں ثوبیہ سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس کی ناک پر ٹکی ہوئی موٹے شیشوں کی عینک کی وجہ سے وہ لڑکی کم اور پروفیسر زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ اس کتاب کی جلد اتنی سخت تھی کہ اگر کتاب کسی کے سر پر مار دی جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا۔ میں نے سوچا ثوبیہ ہی کو ساتھ لے جانا مناسب رہے گا۔ وہ کتاب کو بہ طور ہتھیار استعمال کرلے گی اور ریگی میاں چوں نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اس کے قریب جاکر پوچھا:
’’تم اس وقت کیا پڑھ رہی ہو ثوبیہ؟ کیا تمھارا آج ٹیسٹ ہے؟‘‘
’’ نہیں بھائی جان، میں کیٹس کی نظمیں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے مطالعے سے دماغ تازہ ہو جاتا ہے اور نئے نئے خیالات اس طرح ذہن میں آنے۔۔۔‘‘
’’لان تک چلنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صبح کی تازہ ہوا اور گھاس پر چہل قدمی سے بھی تمھارا دماغ جگمگانے لگے گا۔‘‘میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔
’’ہاں ٹھیک ہے۔‘‘ اس نے رضا مندی ظاہر کی اور میرے ساتھ ہوگئی۔ جب وہ میرے ساتھ اوپری منزل سے نیچے گئی تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا:’’ آپ ریگی کو ناشتا نہیں دیں گے؟‘‘
’’دیں گے کیوں نہیں۔‘‘
’’ تو آئیے، اس طرف چلئے۔‘‘ اس نے میرا ہاتھ تھام کر باورچی خانے کی طرف کھینچا۔ میں نے اپنے کمرے سے باورچی خانے تک کا راستہ بھی یاد کر لیا۔ باورچی خانے میں جب باورچی سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ رات والے سے مختلف تھا۔ وہاں شاید رات اور دن میں الگ الگ ڈیوٹیاں تھیں۔ اس باورچی نے بھی سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اونچی سفید ٹوپی لگائے ہوئے تھا۔ اس کا نام جہاں زیب تھا مگر ثوبیہ نے اسے زیب کہہ کر مخاطب کیا:
’’ریگی کا ناشتا لے چلو زیب۔‘‘ ثوبیہ نے حکم دیا۔
زیب نے ریگی کا جو ناشتا تیار کر رکھا تھا اسے دیکھ مجھے ریگی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ خاص قسم کی غذا کھاتا تھا جو امریکا سے آتی تھی اور یہاں کی خاص دکانوں پر ملتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو کچھ کھاتا تھا وہ ہم جیسے غریبوں کو مہینوں میسر نہیں ہو تا۔
ثوبیہ ایک باتونی لڑکی تھی جو موقع بے موقع فلسفہ بگھارتی رہتی تھی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ ریگی کی پسندیدہ غذا ہے۔ زیب نے ایک تسلے میں اس قسم کا چارا گھول رکھا تھا جیسے کہ ہم اپنی مرغیوں کے لیے تیار کرتے تھے۔ چارے سے بہت ناگوار بو اٹھ رہی تھی جو یقینا ریگی کے لیے خوش بو ہوگی۔
ریگی لوہے کے جنگلے میں بند تھا۔ رات کو اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ زیب نے جنگلے کا دروازہ کھولا اور تسلا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے نہایت خود اعتمادی کے ساتھ تسلا اس کے ہاتھ سے لیا اور جنگلے میں گھس گیا۔ تسلا میں نے فرش پر رکھ دیا، مگر ریگی نے اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ایک خوف ناک غراہٹ کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا۔
وہ شدید غصے میں تھا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ میں خوف زدہ ہونے کے ساتھ حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو خوش بو بھی لگا رکھی ہے پھر وہ مجھے پسند کیوں نہیں کر رہا ہے۔
’’ریگی۔۔۔ ریگی۔۔۔ ہٹو۔۔ احمق۔۔بے وقوف۔‘‘ ثوبیہ نے چیخ کر کہا اور جنگلے میں داخل ہو کر اس کے سر پر اپنی کتاب دے ماری۔ ریگی فوراً ایک طرف ہٹ گیا اور کوں کوں کرنے لگا۔
میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ پھر ثوبیہ نے بھی باہر آکر جنگلے کا دروازہ بند کر دیا۔ ریگی چند لمحوں تک اچھل کو د مچاتا رہا، پھر ثوبیہ کے ڈانٹنے پر کھانے میں لگ گیا۔
’’ مجھے حیرت ہے کہ یہ آپ کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟‘‘ ثوبیہ نے تعجب سے کہا۔’’ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور سوں سوں کرنے لگی جیسے کچھ سونگھ رہی ہو۔
’’یہ آپ نے کون سا پرفیوم لگا رکھا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ۔۔۔‘‘
’’ کک۔ کیا؟‘‘ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ معلوم نہیں کیوں میں ہکلا گیا تھا۔
’’گلاب کی خوش بو ریگی کو سخت ناپسند ہے اور آپ نے اسے غصہ دلانے کے لیے یہی خوش بو لگا لی، حال آں کہ اس سے پہلے جوائل لگا کر آتے تھے۔‘‘
میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا:’’میں نے جلدی میں غلط پرفیوم لگا لیا ہے۔‘‘
’’ غلطی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں بہت بھیانک ہے۔ ان کو غور سے دیکھئے! کیا یہاں گلاب کی کوئی کیاری نظر آرہی ہے؟ دینو یہاں جب بھی گلاب کا کوئی پودا لگاتا ہے، وہ ریگی رات کو کھود کر پھینک دیتا ہے، مگر آپ تو ایسے سن رہے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔‘‘
میں نے کہا: ’’ہاں معلوم کیوں نہیں ہے۔ تم کمنٹری کیوں کر رہی ہو؟‘‘
ثوبیہ جھینپ کر خاموش ہوگئی۔
ریگی خود ہی کھانے میں مصروف ہو گیا اور میں اس کے قریب ہونے کے بجائے اس سے کچھ اور دور ہو گیا تھا تاکہ اس کی ناپسندیدہ خوش ہو اس کی ناک میں نہ پہنچے۔
لان کی طرف واپس آکر میں نے سب کے ساتھ ناشتا کیا۔ ناشتے میں بہت اچھی اچھی چیزیں تھیں۔ میں تھوڑی سی کھا پایا۔ جی چاہ رہا تھا کہ جو کچھ بچ گیا ہے اسے جیب میں رکھ لوں۔ خاص طور پر فروٹ جیلی تو اتنی لذیذ تھی کہ پوری شیشی چٹ کرنے کو دل چاہ رہا تھا مگر میں نے اس خیال سے ہاتھ روک لیا کہ انھیں مجھ پر شک نہ ہو جائے۔
میں اپنے کمرے کی طرف جارہا تھا تو میری نگاہ میں گیند بلا گھوم رہا تھا جو میں نے لکڑی کی الماری میں رکھا دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمام بھائی بہنوں کی ٹیم بنا کر لان میں کرکٹ کھیلوں، لیکن حمیدے نے پیچھے سے آکر کہا: ’’صاحب جی! گاڑی تیار ہے۔‘‘
’’ کہاں جانا ہے؟‘‘
’’اسکول اور کہاں؟ کیا اسکول نہیں جائیں گے؟‘‘
’’ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔‘‘ میں نے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ انکار کر دوں، اس لیے نہیں کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا بلکہ اسکول میں سو طرح کے لڑکے ملیں گے اور نئی نئی باتیں کریں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خیر دیکھا جائے گا۔ جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موسل سے کیا ڈرنا؟
میں اسکول کی یونی فارم پہن کر باہر آگیا۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ کتابیں نہیں مل رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اپنی کتابوں کے بارے میں کس سے پوچھوں۔ میں راہ داری میں گیا تو دوسری طرف سے فوزیہ آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سی کتابیں تھیں۔
’’جلدی چلئے بھائی جان! دیر ہو رہی ہے۔ آپ کی کتابیں میں نے گاڑی میں پہنچا دی ہیں۔‘‘
’’شکریہ۔‘‘ میں نے آہستہ سے کہا۔ اسکول میں میرے ساتھ جو انوکھی باتیں پیش آنے والی تھیں ان کے بارے میں سوچ کر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فوزیہ اچھلتی کودتی میرے قریب آرہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ لڑا کر دہری ہوگئی اور اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی کتابیں فرش پر گر پڑیں۔ میں لپک کر آگے بڑھا اور میں نے اسے سہارا دیا۔
’’ کیسے چلتی ہو تم؟‘‘ میں نے اسے ڈانٹا۔ پھر اس کی کتابیں سمیٹنے لگا۔ اس کی کتابوں میں ایک البم بھی تھا، جس میں کیمرے سے کھنچی ہوئی بہت سی رنگین اور سیاہ و سفید تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ فرش پر گرنے سے البم کھل گیا تھا۔ ایک صفحہ میرے سامنے آگیا تھا۔ میں اسے بند کر کے اٹھانے ہی والا تھا کہ میری نظر اس میں لگی ہوئی تصویروں پر پڑی۔
ان تصویروں میں دو بچے تھے، جن کی عمر تین یا چار سال ہوں گی۔ دونوں کے قد ایک جیسے تھے، لباس بھی انھوں ایک جیسا ہی پہن رکھا تھا۔ دل چسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان دونوں کی شکل و صورت بھی ایک جیسی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہوں۔
’’لائیے چھوڑ یے۔۔۔یہ آپ کیا دیکھنے لگے۔‘‘ فوزیہ نے مجھ سے وہ اہم جھپٹ لیا۔
’’ یہ کیسا البم ہے؟‘‘ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔
’’ہمارا خاندانی البم ہے۔ اس میں سب خاندان والوں کی تصویر یں ہیں۔ امی نے بڑی مشکل سے دیا ہے۔ میں اپنی ایک سہیلی کو یہ تصویریں دکھانا چاہتی ہوں۔‘‘
’’ لیکن یہ دو بچے کون ہیں۔۔۔بالکل ایک جیسے۔‘‘
’’آپ اسکول چلئے۔ بہت دیر ہو رہی ہے۔ اب تو تلاوت شروع ہو گئی ہوگی۔‘‘ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہ گیا۔
سلطان احمد کی زبانی
وہ نا معقول سا آدمی ڈیوڈ مسیح وہاں سے چلا گیا ،مگر جاتے جاتے دھمکی دے گیا کہ وہ پھر گھرپر آئے گا۔ ابا مجھے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ حال آں کہ میں کلنٹن جانا اور سمندر دیکھنا چاہتا تھا۔ سمندر کے بارے میں، میں نے ابھی تک کہانی قصوں میں پڑھا تھا یا پھر فلموں میں دیکھاتھا۔ کراچی آیا تو سمندر دیکھنے کی خواہش دل میں مچلنے لگی۔
’’میں کلفٹن جاؤں گا ابا۔‘‘ میں اپنی خواہش زبان پر لے آیا۔
وہ حیرت سے بولے: ’’اس وقت رات کے وقت سمندر جاکر کیا کرے گا؟‘‘
’’ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے نا۔‘‘ میں نے بے دھیانی سے کہا۔
’’مستانے! تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی دو دن پہلے تو تو وہاں گیا تھا۔‘‘
مجھے خیال آیا کہ میں سلطان احمد نہیں بلکہ پرویز مستانہ بنا ہوا ہوں۔ وہ کراچی کا رہنے والا تھا۔ سیکڑوں بار کلفٹن اور منوڑا گیا ہوگا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ آزادانہ زندگی گزار رہا تھا اور ایک میں ہوں کہ در بہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اور میرے اپنے لوگ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔
’’اوہ ہاں، آج پھر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ چلو بعد میں چلا جاؤں گا، مگر یہ پہلوان بچہ ڈیوڈ مسیح کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟‘‘ ’’وہــــــ۔۔۔ وہ خراب آدمی تھا۔‘‘ انھوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا: ’’پھر کبھی دکھائی دے تو اس کے پاس نہ جانا۔ ڈانٹ کر کہہ دینا کہ میاں چلتے بنو ہم ایسے ویسے نہیں ہیں۔ ہماری بھی کوئی عزت ہے۔‘‘
’’اچھا ابا! اب دکھائی دیا تو میں راستہ کاٹ کر دوسری طرف چلا جاؤں گا۔‘‘
’’شاباش میرے بچے!‘‘ انھوں نے میری پیٹھ ٹھونکی۔
اس وقت بات ٹل گئی اور میں بہ ظاہر مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے رہ رہ کر خیال آرہا تھا کہ وہ کون سا چودھری تھا جس نے ڈیوڈ مسیح کا بیٹا مار دیا تھا اور اس نے انتقاماً ان کے بیٹے پرویز کو اغواکر لیا تھا؟ پھر یہ پرویز قریشی صاحب کے پاس کیسے آگیا؟
مجھے خیال آیا کہ پرویز آزادی سے تو زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کا ماضی کتنا پر اسرار اور الجھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ انہی تاریک گلیوں میں پلا بڑھا اور یہی اس کا ٹھکانا ہے، لیکن اب انکشاف ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کہیں اور سے شروع ہوئی تھی۔ وہ کسی امیر آدمی کا چشم و چراغ تھا۔
میں ابا کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو درخشاں نے چینی کے پیالے میں گڑ کی چائے دی۔ پتی بہت تیز تھی۔ چاے حلق سے اترتے ہی میرے تو کان بجنے لگے۔ میں نے اس وقت ضبط سے کام لیا ورنہ سارا راز کھل جاتا۔ مستانہ تو ایسی چائے کا عادی ہو گا اور اسے خوب مزے لے کر پیتا ہوگا۔
میں پیالا ایک طرف پھینک کر جھگی کے باہر جانے ہی والا تھا کہ صحن میں چار پائی پر بیٹھی ہوئی اماں نے کہا:
’’اے کہاں جارہا ہے مستانے؟ ٹنکی، مٹکے سب خالی پڑے ہیں ،نلکے سے پانی تو بھر کر لے آمیرے لعل؟‘‘
’’اچھا ابھی لو۔‘‘ میں نے مستعدی سے کہا اور آنگن کے دائیں طرف مڑا جہاں گھڑونچی پر مٹکے رکھے تھے اور ان کے قریب ہی بالٹیاں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دو تین بالٹیاں پانی لا کر رکھنا ہوگا، مگر جب آپا ذکیہ نے آدھے درجن مٹکے اور بالٹیاں مجھے تھما دیں تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ میں ان برتنوں کو نلکے سے بھر کر کیسے لاؤں گا؟
میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا:’’ مٹکوں کو یہیں رہنے دو۔ میں بالٹی سے پانی لا کر سب بر تن بھر دوں گا۔‘‘
’’نمبر کافی دیر میں آئے گا۔ ایک ہی بار بھر کر لے آ۔‘‘
میں نے دو چھوٹی بالٹیاں اٹھائیں اور وہاں سے باہر آگیا۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ کارپوریشن کا نل کہاں ہے، اس لیے میں سیدھا اس طرف چلا گیا۔ پانی ابھی آیا نہیں تھا اس لیے مٹکوں اور بالٹیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی آدھی فرلانگ لمبی لائن ضرور ہو گی۔ میں جب سب سے آخر میں اپنی دو ننھی بالٹیاں رکھوں گا تو میرا نمبر کب آئے گا؟ یقینا رات کو دس گیارہ بجے۔
اس کے بعد مجھے گھر کے سب برتن بھرنے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سب کب بھریں گے؟ آپا ذکیہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ مجھے سب برتن نل پر لے آنے چاہیے تھے۔ میں نے وہ دو بالٹیاں تو وہاں سب سے آخر میں رکھ دیں اور دوبارہ اور پھر تیسری بار گھر گیا اور وہاں سے سب برتن لے آیا تاکہ ایک ہی بار میں تمام جھگڑا نمٹ جائے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دو آدمی، ایک عورت اور چار لڑکے کھڑے تھے مگر جب میں سب برتن لے آیا تو اس وقت نل پر سناٹا ہو گیا اور وہاں صرف ایک لڑکا دکھائی دیا۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ ہم بڑے لوگ تو اپنے گھر میں والو گھما کر نہا دھو لیتے ہیں اور بالٹی میں پانی جمع کر لیتے ہیں، یہاں غریبوں کو ایک بالٹی پانی لینے کے لیے اتنا لمبی لائن لگانی پڑتی ہے۔
میری حویلی میں تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ پانی کا کیا شاید کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے سوئمنگ پول میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہفتے تک اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔
وہ لڑکا ٹہلتا ہوا میرے نزدیک آگیا اور بولا: ’’آج تو بہت شرافت دکھا رہا ہے مستانے! کیا بات ہے۔ کیا تیرے نٹ بولٹ ڈھیلے پڑ گئے ہیں؟‘‘ اس نے بے تکلفی سے کہا۔
میں نے ناگواری سے کہا: ’’پیچھے ہٹو، مجھے ایسی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ تمھیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔‘‘
’’ ایں! یہ تو کیا کہہ رہا ہے مستانے؟‘‘ اس نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے کہا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔’’ کل تک تو ہم تیرے قریبی دوست تھے اور تیری بالٹی آگے لگا دیتے تھے تو تو ہمیں کھانے کی چیزوں میں پتی دیتا تھا، آج ہمارے سامنے شریف بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی ،دنیا بدل رہی ہے، اس لیے تم بھی بدل رہے ہو۔‘‘
مجھے ایک لمحے میں ہوش آگیا۔ میں بے دھیانی میں خود کو سلطان احمد سمجھ بیٹھا تھا اور میں نے اس جیسی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ تم پرویز مستانہ کی جگہ ہو اور تمہیں اب اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ لڑکا یقینا مستانے کا قریبی اور گہرا دوست ہو گا اور نل سے پانی بھرتے وقت بالٹیاں آگے لگانے میں اس کی مدد کرتا ہوگا۔ مستانہ تو تیزطرار لڑکا ہے۔ محلے پڑوس والوں کو کب خاطر میں لاتا ہوگا؟ تو پھر؟ میرے دماغ نے سوال کیا۔ پھر کیا ،اس کی دوستی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے اپنے دماغ کو جواب دیا۔
’’ناراض کیوں ہو رہا ہے میرے دوست۔‘‘ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا:
’’ میں تو مسخرا پن کر رہا تھا۔‘‘
اس نے مسکرا کر کہا:’’ تو تو نرا مسخرا ہے۔ معلوم نہیں کیسے تیرے ساتھ دل مل گیا ہے۔اچھا چھوڑ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں آگے کے برتن دور کرتا ہوں تو اپنے برتن سیٹ کردے۔‘‘
اس نے آگے کے برتن تھوڑے سے پیچھے کر دیے اور میرے لیے جگہ بنا دی تو میں نے اپنے برتن وہاں لے جا کر رکھ دیے۔ میں ڈر رہا تھا کہ اس دوران کوئی بڑا لڑکا نہ آجائے ورنہ لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔
پھر جب ایک گھنٹے کے بعد پانی آیا تو ایک ایک کر کے میں سب برتن گھر لے آیا۔ وزن اٹھانے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے اب تک اتنی وزنی چیز کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ پھر وہ تو پانی تھا، مٹکے میں بھرا ہوا جو میرے کپڑوں اور جسم پر چھلک رہا تھا۔ میں پانی کیا بھر رہا تھا نہا رہا تھا۔
ایک نئے جوش اور جذبے سے میں نے یہ نیک کام کر ڈالا جس سے مجھے روحانی خوشی حاصل ہوئی مگر اس کے ساتھ ہی کمر میں چک آگئی۔ جب میں پانی بھر کر بستر پر گرا تو میرے منھ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ آپا ذکیہ نے ناک سکیٹر کر کہا:
’’اے کیا ہو گیا شہزادے! تو نے تو لڑکیوں کو مات کر دیا۔ کیا کمر میں چک آگئی ہے؟‘‘
’’نہیں پاؤں میں پتھر لگ گیا تھا۔‘‘ میں نے بات بنائی۔ میں کمر والی بات بتا کر اپنی کم زوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
رات کے کھانے سے پہلے میں نے گلی کا ایک چکر لگایا اور پھر ایک سنسان جگہ پر وہ ورزش کی جو اسکول میں کیا کرتا تھا۔ اس سے رگ اور پٹھوں کو اپنی جگہ پر آنے میں کافی مدد ملی۔ میں نے بہت سکون محسوس کیا۔ کمر کی تکلیف بڑی حد تک کم ہو گئی۔
رات کے کھانے میں مسور کی دال اور چپاتیاں تھیں۔ اس کے علاوہ رائتہ۔ مجھے یہ سادہ کھانا ذائقے دار اور لذیز معلوم ہوا۔ روغنی اور پر تکلف غذائیں کھاتے کھاتے طبیعت بھر گئی تھی۔ ان نئے ذائقوں نے زبان کو ایک نیا لطف عطا کیا۔
کھانے کے بعد ٹہلنے کا عادی ہوں۔ سونے سے پہلے بیڈ منٹن کا بھی ایک آدھ سیٹ کھیل لیتا ہوں، اس لیے میں نے باہر نکلنے کے ارادے سے چپل پہنی اور اماں کو بتا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت آواز آئی:
’’ قریشی صاحب۔۔۔ قریشی صاحب!‘‘
میں نے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا تو انھوں نے کہا:
’’اندر بلا لا۔ انصاری صاحب ہیں۔ منھ پھاڑے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ کیا انھیں پہچانتا نہیں ہے؟‘‘
’’ہاں ہاں اچھا۔‘‘ میں نے سر ہلا کر کہا اور باہر گیا۔ باہر قمیص شلوار میں ایک بزرگ کھڑے تھے، جن کی عمر تقریباً پچاس برس ہوگی۔ چہرے پر نوارنی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ وہ بزرگ بولے:
’’عشا کی نماز پڑھ کر نکلا تھا۔ سوچا تم لوگوں سے ملتا چلوں۔ خیریت تو ہے نا میاں پرویز؟‘‘
میں نے ادب سے کہا: ’’جی اللہ کا کرم ہے۔ اندر آجائے۔‘‘
وہ اندر آگئے تو ابا کمرے سے نکل آئے۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ ایک دوسرے کی خیریت پوچھی اور رسمی باتیں ہوئیں۔ پھر اماں نے کہا:
’’ارے ہاں بھائی صاحب! آپ کی بیسی نکلی ہے اس بار۔ پیسے لیتے جائیے۔‘‘
’’ارے جلدی کیا ہے بہن! پیسے آجائیں گے۔‘‘
’’نہیں، جب جمع ہوگئے ہیں تو لیتے جائیے۔ پرسوں ہی پرویز نے تمام گھروں سے پیسے جمع کرلیے تھے۔‘‘ پھر انھوں نے میری طرف مڑ کر کہا:
’’پرویز! اپنے ٹرنک میں سے پیسے نکال کر لے آ۔ پورے دو ہزار ہیں۔ گن لینا۔‘‘ میں نے کمرے میں جا کر پرویز مستانہ کا ٹین کا بکس کھولا اور اس میں رکھے ہوئے کپڑے الٹے پلٹے مگر دو ہزار رپے کہیں نہیں لے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ معلوم نہیں پرویز نے
رقم اپنے بکس میں رکھی تھی یا ساتھ ہی لاہور لے گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر رقم نہ ملی تو کہاں سے لاؤں گا۔ اتنی جلدی دو ہزار کہاں سے آئیں گے؟
دل نے سمجھایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہو سکتا ہے رقم بکس ہی میں ہو اور تم نے اچھی طرح دیکھا نہ ہو۔ میں نے بکس میں سے تمام کپڑے نکال کر دوبارہ ایک ایک کر کے دیکھے اور اس کا ایک ایک کونا چھان مارا۔ دو ہزار رپے کسی کونے میں نہیں تھے۔
باہرسے اماں کی آواز آئی:
’’ ارے کہاں مر گیا مستانے ،جلدی سے پیسے لے آ، بھائی صاحب جانے کو کہہ رہے ہیں۔‘‘
میرا دماغ بھک سے اڑ گیا اور آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔
آنگن میں بیٹھی اماں سے ضبط نہیں ہوا تو وہ خود چپلیں گھسٹتی ہوئی میری طرف آنے لگیں۔
اب ذرا پرویز مستانے کی زبانی سنئے!
’’آئیے بھائی جان! آپ کو کیا ہوگیا ہے؟‘‘ فوزیہ نے حیرت سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا۔ اس بار اس نے اتنی قوت سے کھینچا کہ میں کھنچتا چلا گیا۔
پور ٹیکو میں ہنڈا اکارڈ کار کھڑی تھی اور اس کے قریب حمیدے موجود تھا۔ اس نے ہم دونوں کو آتے دیکھا تو مودبانہ انداز میں پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر کار چل پڑی۔
وہ نئے ماڈل کی قیمتی کار تھی۔ اس طرح سڑک پر چل رہی تھی جیسے پانی پر تیر رہی ہو۔ مجھے تو ابھی تک دھچکے کھانے والی بسوں میں سوار ہونے کا موقع ملا تھا اور کراچی میں جہاں میں رہتا تھا وہ جگہ گاڑیوں کے دھویں سے کہر آلود سی رہتی تھی۔
اب جو کار گلبرگ سے نکل رہی تھی تو مجھے دنیا کی ہر چیز حسین اور دل کش معلوم ہو رہی تھی۔ ستھری ستھری اور صاف شفاف۔
میرا خیال ہے کہ ہر قیمتی کار کی کھڑکی سے دنیا ایسی ہی دل کش اور حسین لگتی ہے۔ فوزیہ میرے برابر میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ الجھن پیدا ہونے لگی کہ وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہے یا کسی دوسری جگہ؟ میں نے تھوڑی دیر بعد اس الجھن کو دماغ سے جھٹک دیا کہ جو کچھ ہوگا وہ سامنے آجائے گا۔
یہی ہوا۔ حمیدے نے فوزیہ کو وحدت کالونی کے ایک اسکول کے گیٹ پر اتار دیا جو لڑکیوں کے لیے مخصوص تھا۔ پھر وہ مجھے ایک اسکول پر لے گیا۔ جب میں کار سے اترا تو اس نے میری کتابیں مجھے تھما دیں۔
سلطان احمد نے بتا دیا تھا کہ وہ نویں جماعت کا طالب علم ہے۔ لہٰذا میں اس جماعت میں چلا گیا۔ ہر کمرے کے باہر تختی لگی تھی جس پر کلاس نمبر پڑا تھا۔ میں نے وہاں جا کر ایک ڈیسک کے اندر کتابیں رکھ دیں۔ کلاس میں دو چار لڑکے موجود تھے۔ انھوں نے مجھے ہیلو کہا تو میںنے بھی مسکرا کر انھیں جواب دیا۔
پھر میں برآمدے میں چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھنٹی بجنے پر سب لڑ کے میدان میں جمع ہوں گے اور پھر تلاوت ہوگی۔ میں برآمدے کے زینوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک دائیں طرف سے آواز آئی:
’’ہیلو سلطان! کہاں غائب ہو گئے تھے۔‘‘
’’ بس ایسے ہی ذرا گھومنے نکل گیا تھا۔‘‘ میں نے گول مول سا جواب دیا۔
’’ کہاں؟‘‘ اس لڑکے نے پوچھا۔
میں سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو جواب دوں یا نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ میری ہی جماعت کا کوئی لڑکا ہوگا مگر وہ سلطان کا قریبی دوست تھا یا سلطان سے اس کی محض ہلکی دوستی تھی؟ غلط اندازہ لگانے کی صورت میں گردن پھنس سکتی تھی۔
’’ہونولولو جانے کا پروگرام بنایا تھا مگر غلط بس میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹمبکٹو پہنچ گیا۔‘‘ میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔
’’ٹمبکٹو!‘‘ اس نے پلکیں جھپکا کر کہا: ’’بڑی دل چسپ جگہ ہے۔ میں ٹرینی ڈاڈ تک جا چکاہوں۔ وہاں میرے خالو کے چچا زاد بھائی کا تمباکو کا کھیت ہے۔ بھئی بڑی دل چسپ جگہ ہے وہ بھی۔‘‘
معلوم نہیں وہ کون لڑکا تھا جو ایسی بے پر کی ہانک رہا تھا۔ مجھے اس کی کائیں کائیں بہت ناگوار گزری۔ میں نے ڈپٹ کر کہا:
’’چپ بے ورنہ لگاؤں کا ایک ہاتھ۔‘‘
’’ایں سلطان؟۔۔۔ تم۔۔۔ تم؟‘‘ وہ حیرت سے ہکلانے سا لگا۔
مجھے فوراً احساس ہوا کہ اس طرح کرخنداری لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلطان احمد ایک پڑھا لکھا اور مہذب لڑکا ہے اور اعلا گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے سنجیدہ ہے اس لیے مجھے بھی وہی انداز اختیار کرتے ہوئے شائستہ رہنا چاہیے۔
میں نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنے سے دور رہنے کا اشارہ کیا اور میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہلے سے سب دعا کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ٹھیک آٹھ بجے گھنٹی بجی اور سب لڑکے قطاروں میں کھڑے ہوگئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نویں جماعت کی قطار کون سی ہو سکتی ہے۔ پھر میں ان میں شامل ہو گیا۔
ایک لڑکے نے نہایت خوش الحانی سے تلاوت کی۔ اس کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ مجھے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ پھر اس سورت کا ترجمہ پیش کیا گیا:
’’اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔۔۔‘‘
میں نے سوچا کہ معلوم نہیں وہ کیسے اور کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مجھے تو اس نے جن نعمتوں سے نوازا تھا ان کا شکر تو میںزندگی بھر ادا نہیں کر سکتا تھا۔
تھوڑی دیر بعد سب لڑکے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف جانے لگے۔ میری والی قطار جب آٹھویں کلاس کی طرف جانے لگی تو میں پلٹ کر اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ شکر ہے کہ اس غلطی کو کسی نے محسوس نہیں کیا۔ میں جب کلاس میں دوسری بار داخل ہوا تو بلیک بورڈ کے
اوپر ارسطو کا یہ قول خوش نما لفظوں میں لکھا دکھائی دیا:
’’ایک عالم لاکھوں جاہلوں سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے۔‘‘
میں اس عبارت کو جلدی میں پہلے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں جب اپنی جگہ پر بیٹھا تو احساس ہوا کہ ارسطو کا یہ قول کتنا درست ہے، آدمی کو اپنی زندگی میں بلندی، سرفرازی اور مرتبہ اس وقت ملتا ہے جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ بہت سا علم۔ میں چار جماعتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا تھا۔ اب جو ایک دم نویں کلاس میں بیٹھ گیا تو عجیب سا معلوم ہونے لگا۔
پہلا گھنٹہ اردو کا تھا۔ استاد کے آنے سے پہلے بہت سے لڑکوں نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ میں اب تک کہاں تھا؟ میں نے اشاروں میں جواب دیا کہ میں بہت دور گیا ہوا تھا۔پ کنک منانے۔
اردو کے استاد بہت ذہین اور قابل لگ رہے تھے۔ انھوں نے جب بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے حالات بتانے شروع کیے اور پھر شعروں کے مطلب بیان کیے تو میں کھو سا گیا۔ اس زمانے کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔
اردو کے بعد انگریزی کا گھنٹہ تھا۔ اس کے استاد بالکل انگریز معلوم ہوتے تھے۔ فرفر انگریزی بول رہے تھے۔ میری سمجھ میں ان کی گٹ پٹ نہیں آئی۔ سبق پڑھانے کے بعد انھوں نے لڑکوں سے سوال کرنے شروع کر دیے اور انھوں نے انگریزی میں ہی ان کے جوابات دینے شروع کر دیے۔ میں چور بنا بیٹھا رہا۔
اس لیے کہ میرے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا تھا۔ یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ استاد مجھ سے کچھ نہ پوچھ لیں۔
اس کے بعد جغرافیہ اور تاریخ پڑھائی گئی۔ وہ بھی انگریزی میں۔ میں گم صم بیٹھا رہا۔ خیر پڑھائی ختم ہوئی اور آدھی چھٹی ہوگئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔
لنچ بکس کتابوں کے ساتھ ہی حمیدے نے دے دیا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو طبیعت خوش ہوگئی۔ اس میں کبابوں کے سینڈوچ تھے۔ میں نے مزہ لے لے کر خوب کھایا۔ اس دوران کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ تقریباً سب ہی لڑکے کہیں نہ کہیں کھڑے لنچ کر رہے تھے۔ جب میں پانی پینے کے لیے باہر نکلنے لگا تو دائیں طرف سے ایک خوب صورت سا لڑکامیرے قریب آگیا:
’’کہاں غائب تھے سلطان؟‘‘ اس نے اپنائیت سے پوچھا۔
’’بس ذرا گھومنے نکل گیا تھا۔‘‘
’’میں نے ٹیلے فون کیا تھا۔ فوزیہ نے بتایا کہ کسی کو بتائے بغیر چار دن سے غائب ہو۔ سب تشویش میں مبتلا ہیں۔‘‘
’’ایسے ہی گھر والوں سے ذرا مذاق کر رہا تھا۔‘‘
اس نے کہا: ’’مجھے تو تم بہت پر اسرار لگ رہے ہو۔ اس روز فجر کے وقت تم میرے پاس آئے تھے تو نائٹ گاؤن پہنے تھے اور تم نے میرے کپڑے مانگے تھے ،کیوں؟‘‘
ایک لمحے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ سلطان احمد کا گہرا اور قریبی دوست وحید ہے۔ اس کا ذکر سلطان نے تفصیل سے کیا تھا۔
’’وحید، میرے دوست میں سب کچھ بتا دوں گا۔تم صبر سے کام لو۔‘‘ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔
وہ بولا: ’’تمھاری ہر بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ انگریزی کے پیریڈ میں تم خاموش بیٹھے رہے حال آنکہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر پر جوش انداز میں اسحاق صاحب کے سوالوں کے خوب جواب دیتے ہو۔ آج کیا ہوا تھا؟‘‘
میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے برآمدے کی طرف چلنے لگا تو اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
’’ ایسے ہی طبیعت ذرا بوجھل ہے آج۔ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔‘‘ میں نے بے زاری سے کہا۔
اچانک سامنے شور اور ہلڑ بازی ہونے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کچھ لڑکے ایک فارم پر دوسرے لڑکوں سے دستخط کرا رہے تھے۔ ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا:
’’ارے سلطان کو تو بھولے جارہے ہیں ہم لوگ۔‘‘
’’ نہیں، بھولے کیوں ہیں، اس سے بھی دستخط کراتے ہیں۔‘‘ اس لڑکے نے کہا جس کے ہاتھ میں فارم تھا۔ پھر وہ سب میرے نزدیک آگئے۔ ان میں سے ایک نے وہ فارم میری طرف بڑھا دیا۔
’’ یہ کیا ہے؟‘‘ میں نے پوچھا۔
’’اسکول ٹیم میں شامل ہونے کا فارم۔ اس پر دستخط کرو۔‘‘ ایک لڑکا بولا۔
’’ داخلہ فیس ایک ہزار رپے ہے۔‘‘ دوسرے نے کہا۔
’’یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا لکھ پتی تھے۔ اب یہ کروڑ پتی ہیں۔‘‘
میں نے فارم ہاتھ میں لیا۔ اس میں تین خانے بنے تھے۔ خانوں کے اوپر کھلاڑیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کرکٹ ،دوسرا ہاکی اور تیرا فٹ بال کھیل رہا تھا۔
نیچے بہت سے دستخط تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جو لڑکا جس کھیل میں دل چسپی رکھتا ہے اس نے اسی خانے میں دستخط کیے ہیں۔
مجھے فٹ بال سے دل چسپی تھی۔ میں نے جیب سے اپنا شیفرز قلم نکالا اور اس خانے میںاپنے دستخط کر دیے۔ میں نے اپنے نام پرویز مستانہ کی اچھی طرح سے اردو میں مشق کر رکھی تھی، اس لیے روانی میں وہی دستخط کر دیے۔
میرے پیچھے کھڑے ہوئے وحید بٹ نے اس لڑکے کے ہاتھ سے فارم جھپٹ لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے حیرت سے کہا:
’’پرویز مستانہ! یہ پرویز مستانہ کون ہے؟‘‘
اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں پرویز مستانہ ہوں مگر سلطان احمد بنا ہوا ہوں لہٰذا مجھے اس کے دستخط کرنے چاہیے تھے مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟
وحید بٹ مجھے جھنجھوڑ کر اپنا سوال دہرا رہا تھا اور مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی معلوم ہو رہی تھی۔
سلطان احمد کی زبانی
اماں پاؤں گھسیٹی اور جوتیاں گھسیٹتی ہوئی کمرے کی طرف آرہی تھیں اور مجھے اس تھوڑی سی دیر میں کوئی اچھا سا بہانہ سوچنا تھا۔ ایسا بہانہ جو وہ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کر لیں۔
’’ پرویز! اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہا ہے؟ انصاری صاحب کب تلک بیٹھے رہیں گے؟ ‘‘
’’وہ جو دو ہزار رپے تھے نااماں، وہ میں نے کسی کو دے دیے۔‘‘
وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئیں۔ ’’ارے نہیں، کسے دے دیے نگو ڑ مارے؟‘‘
میں نے کہا: ’’استاد کو۔۔۔ورک شاپ والے استاد کو۔ کہہ رہے تھے کہ دکان کے لیے نئے پرزوں کا سیٹ خریدنا ہے اور گاڑیوں کی ڈیکوریشن کا سامان بھی ،تین دن بعد واپس کر دیں گے۔ اس لیے میں نے دے دیے۔‘‘
’’ا وہ اچھا ۔‘‘اماں نے گز بھر لمبا سانس لیا۔ پھر اسی طرح جوتیاں گھسیٹتی اور ہانپتی کانپتی آنگن میں گئیں اور انھوں نے انصاری صاحب کو یہ بات بتا دی۔
’’ اچھا، اچھا۔ کوئی بات نہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جلدی نہیں ہے۔ پیسے آجائیں گے۔ میں تو یونہی ملاقات کرنے آگیا تھا۔‘‘ وہ بولے۔
وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے اور رجسٹری کے کاؤنٹر پر بیٹھتے تھے۔ ان کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ رٹائر ہونے والے ہیں۔ دو لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں اور ان کے بیاہ کی فکر ہے۔
ان کے دکھ درد سن کر میں بہت رنجیدہ ہوا۔ میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ میاں نے دنیا میں اتنی اونچ نیچ کیوں رکھی ہے؟ کہیں تو دولت کی اتنی زیادتی ہے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہیں پر اتنی کمی ہے کہ ہر قدم ہر ایک مسئلہ ہے ،بلکہ مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر لاہور جاؤں اور ڈھیر ساری رقم لا کر ان سب لوگوں میںتقسیم کر دوں۔ ان کے سب مسئلے ایک بار حل کر دوں۔
انصاری صاحب کے انکار کے باوجود ابا نے نگہت آرا سے چائے بنوا کر انھیں پیش کی۔ وہ چائے پی کر رخصت ہوگئے۔
تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے کا رخ کیا۔ آپا ذکیہ جیسے میرے قدم اٹھانے کی منتظرتھیں۔ انھوں نے اپنی منمناتی ہوئی آواز میں کہا:
’’شہزادے! پان مسالے کا ایک پیکٹ لیتے آنا۔‘‘ ان کو یہ بری عادت پڑی ہوئی تھی۔
’’اچھا بی۔۔۔ابھی لو۔‘‘ میں نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔
ان دنوں شارجہ میں پڑوسی ملک کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔میاں داد نے چھکا لگا کر اپنی ٹیم کو جتوا دیا تھا اور میں یہ منظر دیکھ کر بے تاب ہو گیا تھا۔ ورک شاپ پرمیں نے صرف کمنٹری سنی تھی۔ کرکٹ کا میں شیدائی ہوں۔ اب یہاں ٹیلے وژن نہیں تھا کہ میں اس پر میچ دیکھ لیتا۔ اس کے علاوہ مجھے رات کی خبریں دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ اس سے ساری دنیا کی معلومات مل جاتی تھیں۔
دو دن پہلے مستانہ نے بتایا تھا کہ ٹیلے وژن ایک جھگی ہوٹل میں ہے جہاں ایک چائے کی پیالی پینے کے بعد ایک گھنٹے تک ٹیلے وژن دیکھا جاسکتا ہے۔ میں اس جھگی کی طرف چل پڑا جس کا نام ’’کیفے ذائقہ‘‘ تھا۔
کیفے ذائقہ کا نام اگر کیفے بے ذائقہ ہوتا تو اچھا تھا، اس لیے کہ وہاں کی ہر ایک چیز بے ذائقہ اور بے بو تھی۔ میں نے ٹیلے وژن دیکھنے کے دوران چائے منگوالی تھی جو بہت کڑک اور دماغ کو جھن جھنانے والی ثابت ہوئی۔ مجبوراً ایک کریم رول منگوایا تاکہ چائے کا کڑوا پن زبان سے دور ہو سکے۔ کریم رول میں رول تو مل گیا مگر کریم غائب تھی۔ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملی۔ بہر حال میں نے صبر شکر کر کے اسے بھی حلق سے اتار لیا۔
ٹیلے وژن پر میچ کی جھلکیاں دیکھ کر طبیعت خوش ہوگئی۔ ہمارے کھلاڑیوں نے پڑوسی ٹیم کا بے جگر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور پھر میاں داد نے جس طرح کھیل کو سنبھالا تھا اس کا جواب نہیں۔ کیفے ذائقہ میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں کچھ ہار جیت کی باتیں کر رہے تھے۔ دو اور پانچ نیچے۔ ایک کے پانچ۔۔۔پانچ کے دس۔۔۔میرے اتنے ہوئے، تمھارے اتنے۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں سمجھ لیا کہ وہاں سٹہ ہوتا ہے یعنی لوگ آپس میں آنے والے واقعات کے بارے میں شرطیں لگاتے ہیں۔
جن لوگوں نے شارجہ میچ کے بارے میں شرط لگائی تھی کہ پاکستان جیت جائے گا انھیں بھاری رقم مل رہی تھی جب کہ پڑوسی ملک کی ٹیم کے جیتنے پر جن لوگوں نے شرطیں لگائی تھیںان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔
اچانک ایک گندا سا لڑکا جھگی ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کی پتلون پر بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ انسان کے بجائے وہ ریچھ کا بچہ معلوم ہوتا تھا۔پان چبا رہا تھا اور اس کی انگلیوں میں سگرٹ دبا ہوا تھا۔
میرے برابر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا: ’’چارلی آگیا بے۔۔۔ چارلی۔ تیرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا تو نہیں ہے۔‘‘
میں نے انکار میں گردن ہلائی:’’ میں تو اسے جان بھی نہیں ہوں۔‘‘
وہ اول جلول سا لڑکا سیدھا میری طرف آیا۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہی میری سمجھ میں آگیا کہ اسے چارلی کیوں کہتے ہیں۔ وہ بے حد دبلا پتلا تھا اور اس کے اوپری ہونٹ پر بالکل بیچ میں مونچھ بھی تھی۔ بہت چھوٹی سی جگہ پر جیسے دو کھیاں چپکی ہوئی ہوں۔ ایسی مونچھیں میں نے تصویر میں ہٹلر کی بھی دیکھی تھیں۔
’’مستانے! کیا حال چال ہیں؟‘‘ اس نے اپنے پان میں رچے ہوئے لال دا نتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا۔
ایک لمحے کے لیے مجھے کراہیت محسوس ہوئی۔ جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر دور بھگا دوں، مگر اس خیال سے ایسا نہیں کر سکا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ میں سلطان احمد تھا، مگر اس وقت پرویز مستانہ بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے مستانہ کہہ کر بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا۔ اس سے پتا چلتا تھاکہ وہ آپس میں دوست ہیں۔
’’ حال سے بے حال ہیں اور چال بگڑی ہوئی ہے۔‘‘ نزدیک بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے خواہ مخواہ دخل دیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے ضبط کیا۔ میں بات بڑھانا اور جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر مستانہ میری جگہ ہوتا تو وہ اس بے ہودہ لڑکے کو سبق دیے بغیر نہیں رہتا۔
’’حال چال تو ٹھیک ہیں، مگر ذرا آج کا موسم خراب ہے۔‘‘ کونے سے کسی نے کہا۔
’’آج کے میچ کے بارے میں تو تمھیں معلوم ہو گیا ہو گا؟‘‘ چارلی نے کہا۔
’’ہوں، ہم لوگ جیت گئے ہیں۔‘‘
’’جیتے تو ہم لوگ ہیں ہے۔ تم ہار گئے ہو مستانہ۔‘‘ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔
پھر اس نے کہا: ’’مال نکالو یا پھر اپنے وعدے کے مطابق نہاری والے کے ہاں چلو۔‘‘
’’ وہ کیوں؟‘‘ میں نے صبر و سکون سے کہا۔
’’ کیا اب یہ بھی یاد دلانا پڑے گا کہ تم نے شارجہ میچ پر شرط لگائی تھی۔‘‘ وہ ناگواری سے جھٹکے دار آواز میں بولا۔
’’شرط؟‘‘ میں نے حیرت سے کہا۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے مستانہ نے شرط لگائی ہو۔
’’ اوہ! اچھا، اچھا پھر؟‘‘
’’یہ شرط لگی تھی کہ اگر شارجہ میں ہندستان جیتے گا تو ہم تمھیں اور اگر پاکستان جیتے گا تو تم ہم سب یعنی بیس دوستوں کو مغز نہاری کھلاؤ گے۔ اب اٹھو اور ہوٹل چلو۔‘‘
میں چکراتے ہوئے دماغ کے ساتھ یہ سوچنے لگا کہ مستانے کا بچہ مجھے اور نہ معلوم کتنی مصیبتوں میں پھنسائے گا۔ ابھی میں انصاری صاحب کے دو ہزار رپوں کے لیے پریشان تھا کہ ایک نئی مصیبت گلے میں آگئی۔
’’ ٹھیرو۔‘‘ اچانک بائیں طرف سے آواز آئی۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ ڈیوڈ مسیح تھا جو ایک کرسی سے اٹھ کر میری طرف آرہا تھا۔
۔۔۔۔۔
اب ذرا پرویز مستانہ کی طرف چلتے ہیں۔
’’ایک لڑکا ہے بڑا دل چسپ اور انوکھا۔‘‘ میں نے گڑ بڑا کر کہا۔ ان سب ہم جماعتوں کی موجودگی میں یہ راز کھلا جارہا تھا کہ میں سلطان احمد نہیں بلکہ پرویز مستانہ ہوں۔ میں جلد ہی سنبھل گیا اور میں نے اپنی بد حواسی دور کی۔
’’مگر تم نے اس کے نام کے دستخط کیوں کر دیے؟‘‘ وحید بٹ نے سوال کیا۔
’’ چند روز پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میرے دل و دماغ پر اس نے قبضہ کر لیا، اس لیے میں روانی میں اس کا نام لکھ بیٹھا۔ بہر حال تم مجھے فٹ بال ٹیم میں شامل سمجھو۔‘‘
وحید نے چونک کر کہا: ’’فٹ بال؟ مگر کل تک تو تم کرکٹ کھیلتے تھے؟‘‘
میں نے سر کھجا کر کہا :’’اوہ ہاں، میرے ذہن پر وہی لڑاکا جما ہوا ہے۔ دراصل یہ سب عبد الشکور۔۔۔عبد الشعور۔۔۔نہ۔۔۔نہیں لاشعور کی کارستانی ہے۔‘‘
’’کیا تمھارے لاشعور میں گڑ بڑ پیدا ہو گئی ہے؟‘‘ وحید بٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کیا۔
’’ہاں، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔‘‘
’’ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔‘‘ وحید نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے چھٹکارا پانا دشوار ہے، اس لیے کہ وہ سلطان احمد کا بے تکلف اور عزیز دوست ہے۔ اسے میری باتوں پر شبہ تھا مگر بہر حال وہ مجھے سلطان سمجھ رہا تھا۔
’’تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟‘‘
اس نے جواب دیا: ’’ہم کرکٹ کھیلنے جارہے ہیں۔ بھول گئے آدھی چھٹی کے وقت نویں اور دسویں جماعت کا ون ڈے میچ ہوتا ہے۔‘‘
’’مم۔۔۔ مگ۔۔۔مگر۔۔۔‘‘ میں بے بسی سے ہکلایا۔ میں اس سے ہی نہیں کرکٹ سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں کرکٹ میں کورا تھا اور صحیح طریقے سے بیٹ پکڑنا تک نہیںجانتا تھا۔
میں بہر حال وحید بٹ کے ساتھ کھنچا چلا گیا۔ اس سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ اسکول کا میدان بہت کشادہ تھا اور وہاں مختلف کھیل ہو رہے تھے۔ ایک طرف وکٹیں لگی تھیں اور کھلاڑی یوں کھڑے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔
مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا راز کھلنے والا ہے۔ لڑکے میرے کھیل کو دیکھ کر سمجھ جائیںگے کہ میں کوئی اناڑی ہوں۔ مجھے کھیلنے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔
مجھے دیکھتے ہی سب نے شور مچا دیا:’’ ہرے! کیپٹن صاحب آگئے۔‘‘
یہ سن کر تو میری روح فنا ہوگئی: ’’کیا مجھے کیپٹن بننا پڑے گا؟‘‘
تھوڑی دیر میں دونوں ٹیمیں بن گئیں اور مجھے دسویں کلاس کے کیپٹن کے سامنے سکہ اچھال کر فیصلہ کرنا پڑا کہ پہلے کون کھیلے گا۔ میں نے سکہ اچھالا۔ مخالف ٹیم کے کیپٹن نے چاند تارا مانگا تھا، وہی زمین پر گرا۔ وہ ٹیم جیت گئی تھی اور انھوں نے پہلے کھیلنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ دس دس اوورز کا میچ تھا۔ آدھے گھنٹے میں ایک ٹیم کو دس اوورز کھیلنے تھے۔
میں نے کھلاڑیوں کو میدان میں ترتیب دیا اور اس کے بعد دور جاکر ایسی جگہ پر کھڑا ہوگیا جہاں تک وہ منحوس گیند نہ پہنچ سکے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس احمقانہ کھیل میں کئی کھلاڑیوں کی جان بھی جاچکی ہے۔ ایک کھلاڑی تو پاکستان میں کھیل کے دوران مرا بھی تھا۔
میں آؤٹ فیلڈ پوزیشن پر بر آمدے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس دوران وہاں ایک لڑا آگیااور مجھ سے باتیں کرنے لگے :
’’تمھارے تجربے کا کیا نتیجہ نکلا سلطان؟‘‘ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔
’’کون سا تجربہ؟‘‘ میں نے پوچھا۔
کرکٹ سے مجھے کوئی دل چسپی نہیں تھی ،لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔
’’وہی غائب ہونے والا جو تم اور وحید مل کر کر رہے تھے۔ ایچ جی ویلز کا ناول (غائب آدمی) پڑھ کر۔‘‘
معلوم نہیں، ابھی وہ تجربہ کس مرحلے میں تھا، اس لیے میں نے گول مول سا جواب دیا: ’’ابھی کام یابی نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
’’ والٹن روڈ پر تم جو لیبارٹری قائم کرنے والے تھے اس کا کیا ہوا؟‘‘
میں نے ہنس کر کہا: ’’لیبارٹری؟ وہ تو بڑا منصوبہ ہے بہت بڑا منصوبہ۔‘‘ میں نے بڑائی کی وضاحت کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کہ کوئی چیز ہاتھ میں آگئی۔ ہاتھ میں اچانک چوٹ لگنے سے میں بلبلا کر رہ تھا، مگر میں نے اسے چھوڑا نہیں۔
پھر فوراً زبردست غل غپاڑا مچا اور سب لڑکے دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور شاباشی دینے لگے:
’’ارے واہ! تم نے تو کمال کر دیا! اتنا خوب صورت اور مشکل کیچ لے لیا۔‘‘
’’کیچ؟ اوہ! تو کیا کیچ ہوگیا مگر میں تو۔۔۔‘‘ میں حیرت میں حقیقت کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ میں تو کرکٹ کھیل رہا ہوں۔
’’ تم نے کیپٹن ہونے کا حق ادا کر دیا۔‘‘ دوسرے نے پیٹھ ٹھو نکی۔
’’ ایسا ہی کیچ ایک بار میرے نانا نے بھی لیا تھا۔ وہ قذافی اسٹیڈیم میں انٹر نیشنل الیون کی طرف سے کھیل رہے تھے۔ جب مارشل نے بالنگ کی تو کلائیو لائیڈ نے چھکا مارنے کی کوشش کی ،مگر یا چوں کہ لانگ آن پر کھڑے تھے، اس لیے وہ گیند کی طرف دوڑ پڑے۔‘‘ وہ بکی لڑکا جو تھوڑی دیر پہلے کلاس میں ملا تھا پھر بک بک کرنے لگا:
’’ گیند دائرے سے باہر نکل گئی، مگر انھوں نے باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اچھل کر کیچ پکڑ لیا۔ اس واقعے پر لوگوں نے خوشی سے اتنی تالیاں بجائیں کہ چار بچوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دو مرغابیاں پرواز کے دوران سہم کر زمین پر گر پڑیں۔ اتفاق سے وہ عمران خاں اور للی کے گھٹنوں پر گریں تھیں ،اس لیے ان دونوں کے گھٹنے اور ٹخنے اتر گئے۔ للی نے فوراً اخباری بیان دیا کہ بین الاقوامی سازش کی وجہ سے۔۔۔‘‘
’’چپ رہ۔‘‘ میں نے غصے سے اس لڑکے سر پر زور دار چپت رسید کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا:’’ مینڈک کے بچے! ہر وقت ہی ٹرٹر کر تا رہتا ہے۔‘‘
’’ارے چھوڑو! اس نے جب سے شام کے اخبارات پڑھنے شروع کیے ہیں، اس کی یہ حالت ہوگئی ہے۔‘‘ وحید بٹ نے میرا شانہ تھپ تھپا کر کہا: ’’ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے اسے ٹھیک کریں۔ کوئی اسے مار پیٹ کر خود ہی چپٹا کر دے گا۔‘‘
سب لڑکے ہا ہو مچاتے ہوئے پھر اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ دوسرا کھلاڑی آیا مگرزیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ میں نے اوور شروع ہوتے ہی اپنی پوزیشن تبدیل کر لی اور فائن لیگ پر کھڑا ہوگیا یعنی کھلاڑیوں کے بائیں ہاتھ پر ذرا پیچھے کھڑا ہو گیا۔
جب بالر نے گیند پھینکی تو میں نے وکٹ کی طرف پھرپتھرپھینک دیا۔ بال تو وکٹ کیپر کے ہاتھ میں چلی گئی مگر وکٹ ہلکی آواز کے ساتھ گر گئی۔ پہلے تو وکٹ کیپر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وکٹ کیسے گر گئی۔ پھر وہ کیوں اور کیسے کے چکر میں نہیں پڑا اور اس نے آؤٹ کا نعرہ بلند کیا توامپائر نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے آؤٹ قرار دے دیا۔
کھلاڑی کچھ دیر تو الجھن میں کھڑا رہا مگر پھر پبلک کے بے حد اصرار پر واپس چلا گیا۔ میںنے سوچا کہ فیلڈنگ کرتے وقت میں ایک جگہ کھڑا رہ کر بور کیوں ہو تا رہوں اور ننھی سی گیندکے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنا حلیہ کیوں خراب کروں۔ چلو بالنگ کرائی جائے۔ دو چار کھلاڑیوں کامنھ ٹوٹے گا تب ہی یہ لوگ بیٹنگ سے باز رہیں گے۔
جب دوسرا اور ختم ہوا تو میںنے دوڑ کر گیند خود اٹھا لی۔
’’کیا ارادہ ہے؟‘‘ وحید بٹ نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ ایمپائر بنا ہوا تھا:
’’ شاہد کی وکٹ تو تم نے پھر مار کر گرا دی۔ یقین کرو اگر میں فوراً انگلی نہ اٹھا دیتا تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔‘‘
’’اس تعاون کا شکریہ۔‘‘ میں نے آہستہ سے کہا۔
’’ لیکن یہ جعلی کرکٹ کہاں تک کام یاب ہو گی؟ تم ایک اچھے کھلاڑی ہو کر ایسی گھٹیا حرکت کیوں کر رہے ہو؟‘‘
’’ کبھی کبھار ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا چا ہیے۔‘‘ میں نے کہا۔ میں اس بے چارے کوکیا بتاتاکہ میں کون ہوں اور کس کا روپ اختیار کیے ہوئے ہوں۔
’’ خیال رکھنا۔ یہ لوگ تمھارا گھی نہ نکال لیں۔ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔‘‘
اوور شروع ہوتے ہی میں نے ایک لمبا اسٹارٹ لیا ،اتنا لمبا کہ سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ انھیں حیرت ہونی بھی چاہیے تھی کیوں کہ میں اسکول کی چار دیواری کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے پوری قوت سے دوڑ لگا دی۔ وکٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گیند پوری قوت سے کھلاڑی کی طرف پھینکی۔ جسم کی ساری طاقت کے ساتھ۔ کھلاڑی گھبرا کر ہٹ گیا کیوں کہ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گیند پھینکی تھی، وہ ہٹ گیا اس لیے گیندوکٹوں پر پڑی۔ دو وکٹیں گر گئیں۔
میدان میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ سب دوڑ کر میری طرف آگئے اور مجھے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ بمباٹ کرکٹ کھیل کر اچانک ہی میں ہیرو بن گیا ہوں۔
میری طوفانی بالنگ کے سامنے کوئی کھلاڑی نہ ٹک سکا۔ ایک اوور میں دو تین ہی رن بن سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس اووروں میں بائیس رن بنے جو ہماری ٹیم کے لیے ایک آسان ٹارگٹ تھا۔
میں فٹ بال کھیلتے وقت اتنا کبھی نہیں تھکا تھا جتنا کہ کرکٹ کھیل کر تھک گیا تھا۔ اصل میں بالنگ کراتے وقت میں نے ضرورت سے زیادہ ہی دوڑ لگا لی تھی، اس لیے پسینے میں شرابورہو گیا تھا۔
جب ہماری ٹیم نے کھیل شروع کیا تو انھیں بھی جبڑہ توڑ بالنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالف ٹیم کے بالروں نے بھی شاید قسم کھائی تھی کہ وہ ہمارے دو چار کھلاڑیوں کو اسٹریچرپر واپس بھیجیں گے۔
رن بننے کی رفتار سست رہی اور کھلاڑی ڈرے ڈرے سے رہے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شروع کے تین کھلاڑی آٹھ رن پر ہی آؤٹ ہوگئے اور میری باری آگئی۔ حال آنکہ میری کوشش یہ تھی کہ مجھے بلے بازی نہ کرنی پڑے اور مخالف ٹیم کے جوابی حملوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی؟
میں بلا گھماتا ہوا نہایت شان کے ساتھ وکٹوں پر جا کھڑا ہوا۔ سامنے جو لڑکا کھڑا تھا وہ پڑھاکو اور فلاسفر قسم کا تھا۔ اس نے بالوں میں بہت سا تیل ڈال کر مانگ نکالی ہوئی تھی اور اس کی ناک پر بہت موٹے شیشوں کی عینک ٹکی ہوئی تھی۔
پہلی گیند آئی تو میں نے آگے بڑھ کر بلا گھمایا، مگر بلے اور گیند کی ملاقات نہ ہو سکی اور گیند سیدھی وکٹ کیپر کے ہاتھ میں چلی گئی۔ میں آؤٹ ہوتے ہوتے بچا۔ دوسری دو گیندوں پر اگر میں فوراً ہی بیٹھ نہ جاتا تو گیند میری مزاج پرسی ضرور کرتی اور مجھے اپنے سامنے کے دانت تڑوا کر خون کی کلیاں کرتے ہوئے واپس آنا پڑتا۔
چوتھی گیند پر چوکا لگ گیا۔ کیسے لگ گیا اور اس وقت کیا ہوا تھا مجھے قطعی معلوم نہیں۔ بس یہ بتا سکتا ہوں کہ بلا گھمانے پر کھٹ کی سی آواز آئی اور بال اڑ کر باؤنڈری لائن کی طرف چلی گئی۔ بارہ رن ہوگئے تھے۔ اگلی بال پر دو رن دوڑ کر بنا لیے۔ چودہ رن ہو گئے۔
رن بناتے وقت میرے جوش و خروش میں اتنا اضافہ ہوگیا تھا کہ میں وکٹوں سے کافی آگے نکل جاتا اور مڑ کر واپس آنے میں مجھے کافی دشواری ہوتی۔ اس سے اگلی بال پر میں نے لانگ آن کی طرف ایک شارٹ مارا تو تین رن بن گئے۔ میرے ساتھی کا نام ماجد تھا۔ اس کی ٹانگیں کافی مضبوط تھیں، اس لیے وہ بھی خوب دوڑ رہا تھا۔ وہ کھیل بھی اچھا رہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا چشمہ صاف کرنا پڑتا تھا ،اس لیے کہ پسینے کی وجہ سے اس کے شیشے دھند الا جاتے تھے۔
جب بیس رن بن گئے تو اوور ختم ہو گئے اور صرف دو گیند یں رہ گئیں۔ میں وکٹ کے سامنے تھا۔ بالر نے گیند پھینکی تو میں نے شاٹ مارا اور فیلڈر نے بال پکڑلی اور ایک بھی رن نہ بنا سکا۔ مخالف ٹیم اور تماشائیوں کا جوش و خروش اپنے عروج پر پہنچ گیا۔
آخری گیند پر میرا دل دھڑکنے لگا۔ کہاں تو میں کرکٹ سے دور بھاگتا تھا اور کہاں یہ حال تھا کہ میں یہ میچ جیتنا چاہتا تھا۔ تماشائیوں کے شور و غل کے ساتھ آخری گیند میری طرف آئی اور میں نے شارٹ مار دیا۔ ایک رن بن گیا۔ فیلڈر نے وکٹ کیپر کی طرف گیند پھینکی جو اس کے ہاتھ میں نہ آسکی۔ لہٰذا اوور تھرو پر ہم رن بنانے کے لیے دوڑے۔ اس وقت ماجد کا چشمہ اس کی ناک پر سے پھسل کر زمین پر گر پڑا۔
ماجد بھاگتے بھاگتے رک گیا اور جھک کر زمین ٹٹولنے لگا۔ میں اس دوران اس کی جگہ پر پہنچ چکا تھا، اس لیے تماشائیوں نے اتنا شور مچایا کہ کان بجنے لگے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ،دوڑ کر ماجد کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوسری طرف پہنچا دیا۔ ایک رن ابھی باقی تھا اور گیند کہیں جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی۔ میں پھر ماجد کو پلٹ کر بالرز اینڈ کی طرف لے گیا اوردوڑ کر اپنی جگہ پر آگیا۔ ہم میچ جیت گئے۔
گیند پھر بھی نہ ملی۔ ملتی بھی کیسے؟ آخری شاٹ پر گیند اتفاق سے وحید بٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے ٹانگ سے اسے روکا۔ پھر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں کی زمین نرم تھی۔ جب اس نے زور ڈالا تو گیند زمین میں دھنس گئی۔ پھر کبھی نہیں ملی۔
پہلے دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے فورا ًبعد ہی سو گیا۔ شام کو مغرب سے کچھ پہلے اٹھا تو معلوم ہوا کہ سب لوگ مطالعہ گاہ میں ہیں۔
میں نے اس بارے میں کسی سے پوچھا نہیں۔ تلاش کر کے خود ہی پہنچ گیا۔ مطالعہ گاہ کیا یہ تو لائبریری تھی۔ چاروں طرف لکڑی کی خوب صورت شیلفوں میں کتابیں سجی تھیں۔ اس کشادہ کمرے کے بیچ میں ایک بڑی سے بیضوی میز تھی جس کے گرد کرسیاں تھیں اور خاندان کے تقریباً سب ہی لوگ وہاں موجود تھے، سوائے اماں ،ماموں اور چچا کے۔ میز پر انگریزی اور اردو کے اخبارات تھے۔ چینی اور ممانی اخبار پڑھ رہی تھیں اور میرے بھائی بہن کورس کی کتا بیں، کہانیوں کی کتابیں پڑھ رہے تھے یا پھر لکھنے میں مصروف تھے۔
دائیں طرف دیوار پر کسی فلسفی کی بڑی سی پینٹنگ لگی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا: ’’علم ،دل کو اس طرح زندہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔‘‘ (ارسطو)
یہ قول مجھ پر اتنا اثر انداز ہوا کہ آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا۔ وہاں خاموشی تھی اور کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اس لیے میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اخبار کے صفحے پلٹنے لگا۔
’’یہ ممدو اب تک چائے کیوں نہیں لایا؟‘‘ احمد نے اچانک سر اٹھا کر کہا۔
’’گھنٹی بجا دو۔‘‘ ممانی بولیں۔
فوزیہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سوئچ بورڈ پر لگا ہوا بٹن دبایا تو باورچی خانے میں گھنٹی بجی اور ممدو تھوڑی دیر میں ٹرالی دھکیلتا ہوا آگیا۔ چائے کے ساتھ گرم سموسے اور چاکلیٹ کیک تھا۔ چائے پینے کے دوران فوزیہ نے اچانک پوچھا:
’’بھائی جان! آپ کل صبح جو گنگ کے لیے جائیں گے نا؟‘‘
’’ نہیں۔۔۔ ہاں۔۔۔ جونگ؟‘‘ میں نے گڑ بڑا کر کہا۔ پتا نہیں تھا کہ جو گنگ کیا ہوتی ہے۔
وہ بولی: ’’میں بھی آپ کے ساتھ دوڑنے جاؤں گی۔ آپ کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو کار پورچ میں تیار ملوں گی۔ آپ پانچ بجے جاتے ہیں نا؟‘‘
’’اوں! ہوں؟‘‘ میں نے سر ہلایا۔
تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ سلطان اٹھ کر دوڑ لگا تا اور ہلکی ورزش کرتا ہے، لیکن میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اگر مجھے سلطان بن کر وہاں رہنا تھا تو صبح اٹھ کر نماز پڑھنی تھی اور دوڑ لگانے کے لیے بھی جانا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے تو بہر حال مجھے خوشی ہوتی، اللہ کے آگے جھکنا کسے پسند نہیں مگر صبح اٹھ کر دوڑنا میرے لیے ایک مسئلہ تھا۔
’’ٹھیک ہے۔ تم بھی چلنا۔‘‘ میں نے کہا۔
اس رات میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے گھڑی میں پانچ بجے کا الارم لگا دیا۔ رات کو بھر پور نیند آئی۔ میں الارم کی آواز سے اٹھ گیا۔ پھر منھ ہاتھ دھو کر اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکلا۔ راہ داری میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری نگرانی کی جارہی ہو۔ میں تیز تیز قدم رکھتا ہوا زینے تک پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے پہلے زینے پر پاؤں رکھا میرا پاؤں پھسل گیا اور میں لڑھکتا ہوا نیچے جانے لگا۔ خوف و دہشت کے اس عالم میں بھی مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے زینے پر تیل یا گریس مل دی ہے جس سے میرا پاؤں پھسلا ہے۔
سلطان احمد کی زبانی
میری جیب میں اس وقت کچھ نہیں تھا مگر چارلی ضد کر رہا تھا کہ میں اس کی اور اس کے دوستوں کی نہاری کی دعوت کروں۔ میرے انکار کرنے پر یقینا وہ میری بے عزتی کرتا اور ممکن ہے ہاتھا پائی پر اتر آتا، لیکن ٹھیک اسی وقت ڈیوڈ مسیح اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور اس نے کہا:’’ٹھیرو، کیا بات ہے چارلی؟‘‘
چارلی نے اسے بات بتائی۔
ڈیوڈ مسیح نے پوچھا:
’’تمھیں نہاری کھانے کے لیے پیسے چاہئیں نا، چاہے کوئی بھی دے دے؟‘‘
’’شرط یہ ہارا ہے، اس لیے اسے ہی دینے چاہئیں۔ اس کے سوا اور کون دے گا؟ یہاںاس کے کون مامے چاچے بیٹھے ہیں؟‘‘
’’اگر میں دے دوں تو؟‘‘
’’ چلو ٹھیک ہے، تم ہی نکالو۔‘‘ دوسرے لڑکے نے کہا۔ اس کا سر صاف تھا اور روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے گلے میں رومال باندھ رکھا تھا اور بکریوں کی طرح منھ چلا چلا کر پان کھا رہا تھا۔
ڈیوڈ مسیح نے یہ سن کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سو رپے کا نوٹ نکال کر چارلی کی طرف بڑھادیا جسے گنجے لڑکے نے جھپٹ لیا اور ہاتھ اونچا لہرا کر بولا:
’’آہا، آج تو مزے آگئے۔ نلی والی نہاری ہوگی استاد۔‘‘
’’میاں داد زندہ باد۔‘‘ تیسرے نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا۔
وہ سب چارلی کے ساتھ شور و غل مچاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تو میں نے حیرت سے ڈیوڈ مسیح کی طرف دیکھا اور پلکیں جھپکانے لگا۔ اس نے ایسے نازک موقعے پر مہربانی کی تھی کہ میں اسے منع نہیں کر سکا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟
’’میں قریب ہی رہتا ہوں چاکی واڑے میں۔‘‘ وہ بولا۔
میں اس سے کچھ پوچھنے والا ہی تھا کہ اچانک خیال آیا کہ قریشی صاحب نے اس سے گفت گو کرنے سے منع کیا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ میں اسے دیکھ کر دھتکار دوں اور قریب نہ آنے دوں۔ یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی کہ انھوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟
’’ تم نے اس وقت مجھے ایک بڑی پریشانی سے بچالیا، تمہارا شکریہ ڈیوڈ۔ میں سو رپے تمہیں دو تین دن میں ادا کردوں گا ، مگر یہ تو بتائو کہ تم نے آج مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی ہے؟‘‘ میں نے سوال کیا۔
’’اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے مستانے۔‘‘ اس نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔
’’ مگر میرے ابا تو قریشی صاحب ہیں۔‘‘ میں نے بھویں سکیڑ کر کہا اور ناگواری ظاہر کی۔
’’جب مجھے سزا ہوئی تھی تو اس وقت تو بہت چھوٹا تھا اس لیے میں نے تجھے قریشی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ قریشی تیرا حقیقی باپ نہیں ہے۔‘‘
’’ حقیقی تو تم بھی نہیں معلوم ہوتے اس لیے کہ تم ڈیوڈ مسیح ہو اور میں پرویز مستانہ ہوں۔ میں تمھارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟‘‘ میں نے جرح کی۔
’’ناموں کے چکر میں نہ پڑ مستانے ، تو میرا بیٹا ہے بس۔ اگر تجھے اپنا نام اچھا نہیں لگتا تو میں تیرا نام بدل دوں گا۔‘‘ وہ بات بدل کر بولا۔
’’پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ پر اپنی محبت کیوں نچھاور کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمھاری کہانی کیا ہے؟ تمھیں کس بات پر سزا ہوئی تھی؟‘‘ اس نے میرے شانے پر دباؤ ڈال کر مجھے لکڑی کی بینچ پر بٹھادیا۔ پھر بیرے کو بلا کر دو گلاس بالائی والی چائے لانے کا آرڈر دیا اور بولنے لگا:
’’ میری کہانی کوئی خاص نہیں ہے۔ میں پہلے لاہور میں رہتا تھا۔ ایک بڑے آدمی کی حویلی میں۔ اس بڑے آدمی نے جب میرے بیٹے کو مار دیا تو میرا غم سے برا حال ہوگیا۔ میں انتقام کی آگ میں دہکنے لگا۔ میں بدلا لینے کے جوش میں اندھا ہو گیا اور میں نے اپنے بھائی کے بہکائے میں آکر اس بڑے آدمی کا بچہ اٹھالیا اور اسے اپنے ساتھ لاہور سے کراچی لے آیا۔ اس آدمی نے مجھے ایک مقدمے میں پھنسا کر سزا کرادی تو میں نے اس بچے کو قریشی کے حوالے کردیا۔ اب میں جیل سے واپس آگیا ہوں۔ سزا پوری کرکے تو۔۔۔ تو۔۔۔‘‘
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خاموش ہوگیا کیوں کہ بیرا بالائی والی چائے لے آیا تھا۔
اس کے انکشاف سے میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔
’’وہ یقینا پرویز مستانہ کو لاہور سے کراچی لایا تھا اور مجھے پرویز سمجھ کر یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پرویز بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھامگر قسمت نے اسے کہاں لا پھینکا تھا۔ اس احمق آدمی کی وجہ سے وہ کیسی مصیبت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ معلوم نہیں اب اس کے والدین کہاں ہوں گے اور اپنے بیٹے کے بچھڑ جانے پر پتا نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا! اس کی صورت شکل مجھ سے ملتی جلتی تھی، لیکن قسمت کتنی مختلف تھی!
میں نے بالائی والی چائے کا ایک گھونٹ لیا تو وہ مجھے مزے دار معلوم ہوئی۔ میں حویلی میں دار جلنگ سے آئی ہوئی خاص قسم کی چائے پیتا تھا جس کا مزہ میں کبھی بھول نہیں سکتا، لیکن اس وقت گڑ کی وہ چائے بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا:
’’ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے لاہور سے اغوا کر کے لائے ہو اور تم نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کر دیا ہے؟ تمھیں ایسا کرتے شرم نہیں آئی؟‘‘
اس نے گھگھیا کر کہا: ’’مجھے معاف کردو مستانے! میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا۔ جہاں تک سچی بات بتانے کا تعلق ہے تو یہ بات کسی نہ کسی روز تمھیں معلوم ہی ہو جاتی، اس لیے میں نے ابھی سے بتا دی۔ اب میرے ساتھ چلو۔‘‘
تم نے جو کہانی سنائی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے مجھے انتقام لینے اور میرے باپ کو سزا دینے کے لیے اغوا کیا تھا۔ تمھیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تم سے اچھے تو قریشی صاحب ہیں جنھوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب وہ مجھے اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور یہ ایک طریقے سے غلط بھی نہیں ہے۔ میں ان کے پاس کیوں نہ رہوں۔‘‘ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔
’’میرے ساتھ چل مستانے!میرے بچے!اس کی آواز بھرانے لگی۔‘‘
’’ایک شرط پر۔‘‘ میں بولا۔
’’ وہ کیا؟‘‘ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں پھر سے چمکنے لگیں۔
’’یہ بتاؤ کہ اس بڑے آدمی کا نام کیا ہے جس کا میں بچہ ہوں؟‘‘
’’ وہ۔۔۔وہ۔۔۔مم۔۔۔ میں۔۔۔ نہیں بتا سکتا۔‘‘اس نے ہکلا کر کہا۔
’’کیوں؟‘‘ میں نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔
’’ یہ میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ کسی نے مجھے قسم دے رکھی ہے۔‘‘ اس نے بے چارگی سے کہا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔
اور اب پرویز مستانہ کی طرف چلتے ہیں
میں جس تیز رفتاری سے زینے سے لڑھک رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جب میں نیچے تک پہنچوں گا تو میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ میں اس وقت بدحواس ہورہا تھا، مگر میں نے خود پر قابو پایا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دائیں طرف والی ریلنگ کی فولادی اور چوکور سلاخ میرے ہاتھ میں آگئی جو ریلنگ میں آرائشی طور پر لگی ہوئی تھی۔ اس سلاخ کے ہاتھ میں آتے ہی میرے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور میں لڑھکتے لڑھکتے رک گیا۔ چند لمحوں تک یوں ہی خاموش پڑا رہا۔ پھر جب حواس ٹھکانے آگئے تو میں نے زینے پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے جوتے اتارے اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا نیچے اترا۔
اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور حلق بالکل خشک تھا۔ مجھے رہ رہ کر یاد آرہا تھا کہ سلطان احمد یہاں سے بھاگ کر اسی لیے کراچی گیا ہے اور اس نے میرے گھر میں پناہ لی ہے کہ یہاں کوئی اس کا دشمن پیدا ہو گیا ہے جو اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ مجھے سلطان سمجھ کر اب وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔
اب میرے لیے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ میں خاموش رہوں اور آئندہ قدم پھونک پھونک کر اٹھاؤں۔ موقعے کا منتظر رہوں اور اس شخص کو پکڑلوں جو سلطان کی جان کا دشمن ہے۔ دوسرے یہ کہ غل مچاؤں اور گھر کے سب لوگوں کو جمع کرکے یہ قصہ سناؤں اور دیکھوں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ یقینا جو گھبرایا ہوا سا ہو گا وہی مجرم ہو گا۔
سب کو جمع کرنے اور غل مچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں پور ٹیکو میں جاکر فوزیہ کو یہ بات بتادوں جو میرے ساتھ جوگنگ کرنے کے لیے باہر جانے والی تھی اور کار کے پاس میرا انتظار کر رہی تھی۔
زینوں پر رگڑ لگنے سے میرے جسم پر خراشیں پڑ گئی تھیں مگر کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔میں اپنی خراشوں کو سہلاتا ہوا پور ٹیکو میں چلا گیا۔ دائیں طرف نیلے رنگ کی وہ کار کھڑی تھی جس پر میں صبح اسکول گیا تھا جب کہ بائیں طرف فوزیہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے تابی سے میری طرف لپکی اور اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولی:
’’ آپ نے بہت دیر کردی بھائی جان!‘‘ پھر اس کی نگاہ اچانک ہی میرے پاؤں پر پڑی تو اس نے چونک کر کہا:
’’ارے آپ کے جوتے کہاں گئے؟‘‘
’’وہ میں نے ابھی ابھی اتار دیے ہیں، کیوں کہ۔۔۔‘‘ میں نے منھ بناکر کہا: میں زینے سے گر گیا تھا ،اس لیے کہ۔۔۔‘‘
اس نے پھر میری بات کاٹ دی:’’ تو کیا اب کبھی جوتے نہیں پہنیں گے؟‘‘
’’اگر تم سنجیدگی سے میری بات نہیں سنو گی تو میں تمھاری پٹائی کردوں گا۔‘‘ میں نے اس کا کان کھینچ کر کہا۔
’’ہائے اللہ! اچھا اچھا ،بتائیے۔‘‘ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔
میں نے اسے مختصر لفظوں میں جب یہ بتایا کہ کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور زینے پر کوئی چکنی چیز مل دی ہے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور گھبرا کر بولی:
’’پھر تو آپ کے بہت چوٹیں آئی ہوں گی۔‘‘
’’نہیں اللہ کا شکر ہے کہ بچ گیا، چند معمولی خراشیں آئی ہیں۔‘‘
’’آئیے اندر چلتے ہیں۔ ایسی حالت میں جوگنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کہیں پھر کچھ ہوگیاتو۔۔۔‘‘ اس نے اندیشہ ظاہر کیا۔
میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا تو وہ تھوڑی دیر میں سب لوگوں کو جگا کر لے آئی۔ ماموں، ممانی اور چا چی تو پہلے ہی جاگ چکے تھے اور نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ البتہ اس کے بھائی بہن جو جلدی اٹھنے کے عادی نہیں تھے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ لوگ جو اوپری کمروں سے آرہے تھے۔ فوزیہ انھیں ہدایت دے رہی تھی کہ وہ زینے کے شروع کے دو قد مچوں پر پاؤںنہ رکھیں۔
ماموں گزار نے اس سے سوال کیا:’’کیا ہوگیا۔ آخر بات کیا ہے بیٹی! ان دو قد مچوں کو کیا ہوگیا ہے؟‘‘
’’اس پر کسی نے گریس یا تیل لگایا ہے ابو!‘‘
’’ہائیں!‘‘ بہت سی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ پھر میرے سب بھائی بہن اور چچا جان لپک کر اوپر پہنچے اور انھوں نے قدمچوں کے پاس بیٹھ کر انھیں غور سے دیکھا۔ پھر میرے جوتوں کے تلے دیکھے گئے۔ چچی جان نے کہا:
’’ہاں، گریس ہے، مگر یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔‘‘
چچا رحمت نے کہا: ’’وہ بعد میں معلوم کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمھیں چوٹ تو نہیںلگی؟‘‘ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤںٹٹولے۔
احمد نے سوچ کر کہا:’’ گریس تو مشینی کل پرزوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ڈرائیور نے یہ حرکت کی ہو!‘‘
’’ٹھیک ہے، اسے بلاؤ۔‘‘ ماموں نے کہا۔
حمیدے ڈرائیور کو بلایا گیا۔ وہ دہاڑیں مار مار کر رونے لگا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ویسے بھی حمیدے نے سلطان کو گود میں کھلایا تھا اس لیے اس پر شبہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کے بعد باری باری سب کو بلایا گیا مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
جب سب لوگ چلے گئے تو مجھے خیال آیا کہ دینو مالی کو تو بلایا ہی نہیں گیا۔ میں فوزیہ سے یہ بات کہنے والا تھا کہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ میں اس سے خود پوچھوں گا۔ سب نے مجھے ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔
جوگنگ کے لیے اب جانا نہیں تھا، اس لیے میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسکول جانے میں کافی دیر تھی اس لیے میں بستر پر لیٹ کر دوبارہ سو گیا۔
اس روز ناشتا کرنے کے بعد جب میں کار میں بیٹھ کر اسکول گیا تو سب سے پہلے اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی جو بہت زیادہ گپیں ہانکتا تھا۔
’’ تم نے کل کا میچ جتوادیا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میرے ماموں زاد بھائی ایک مرتبہ اسٹار الیون کی طرف سے کھیل رہے تھے تو انھیں آخری اوور میں۔۔۔‘‘
میں نے منھ بنا کر کہا: ’’ہٹ بے ایک طرف کو۔ پتا نہیں کہاں کی ہانکتا رہتا ہے۔‘‘
وہ لڑکا جھجک کر پیچھے ہٹ گیا اور مردہ لہجے میں بولا:
’’یہ تم کیسے بات کر رہے ہو، لینگویج پلیز۔‘‘
’’ہٹ پرے کو، ہر وقت کی چیں چیں اچھی نہیں لگتی۔‘‘ میں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور اس کے دائیں پہلو سے کترا کر کلاس روم کی طرف چلاگیا۔
پہلا پیریڈ اردو اور دوسرا انگریزی اور پھر علم کیمیا کا تھا۔ سب طالب علم سائنسی تجربہ گاہ کی طرف چل دیے۔ اسکول کی تجربہ گاہ اوپری منزل پر تھی اور دیکھنے میں بے حد شان دار۔ اس میں کیا کچھ رکھا ہوا تھا اور اس کی کیا قدر و قیمت تھی ،میں اس سے لاعلم تھا۔
تجربہ گاہ میں ایک لمبی اور وزنی سی میز تھی جس پر ایک سرے سے دو سرے سرے تک لکڑی کے شیلف تھے اور ان شیلفوں میں چھوٹی بڑی بوتلیں سجی تھیں۔ بوتلوں میں لال،نیلا، پیلا پانی اور کچھ میں کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے تھے۔ کیکڑے، چھپکلیاں ،لال بیگ اور مردہ مچھلیاں وغیرہ۔ چند بڑی بوتلوں میں مجھے آبی پودے بھی رکھے دکھائی دیے۔
سب سے پہلے استاد صاحب نے اوکسیجن کی تیاری پر لیکچر دیا اور تختہ سیاہ پر لکھ کر کچھ سمجھایا۔ دوسرے طالب علم یقینا سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میرے تو سر پر سے گزر گئی۔ چند چیزیں یاد رہ گئیں مثلا مینگنیز، جست کے ٹکڑے وغیرہ۔ اسے نلکی میں بھرو، پھر گرم کرو تو اوکسیجن علاحدہ ہو کر شیشے کی نلکیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف پہنچ جائے گی۔ پانی کے تسلے میں شیشے کے اوندھے جار رکھو اور جب وہ اوکسیجن سے بھر جائیں تو انھیں الگ رکھتے جاؤ۔ پھراو کسیجن پر تجربے کرو۔
انھوں نے سب کچھ سمجھانے کے بعد سب کو اشارہ کیا کہ وہ تجربہ گاہ کی میز کی طرف چلے جائیں۔ میں بھی ان میں شامل ہو کر چلا گیا۔ دل الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔
کاش کہ وحید بٹ قریب ہوتا تو مشکل آسان ہوجاتی لیکن وہ کافی دور دو سری میز پر تھا اور اس وقت بوتلوں کی آڑ میں تھا اس لیے صاف طرح سے نظر بھی نہیں آرہا تھا۔
استاد فیض الرحمان یہ بھی سمجھا چکے تھے کہ اسپرٹ لیمپ جلا کر شیشے کی نلکیاں کیسے موڑی جائیں گی۔ تجربہ گاہ کے ملازم نے دائیں طرف کی الماریوں کو کھول کر سائنسی ساز و سامان نکالا اور سب طالب علموں کے سامنے میز پر سجادیا۔
میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے اسپرٹ لیمپ جلائے ہیں اور شیشے کی نلکیاں موڑ رہے ہیں۔ میں نے جھٹ سے ایک نلکی اٹھالی اور اس کا درمیانی حصہ لیپ کی لو پر رکھا تو نلکی تھوڑی سی دیر میں ملائم ہو گئی مگر جب میں نے اسے پینتالیس درجے پر موڑنا چاہا تو چٹ کی زور دار آواز آئی اور وہ بیچ سے ٹوٹ گئی۔ میں نے گھبرا کر دونوںٹکڑے میز پر رکھ دیے۔
وہاں دو نلکیاں اور پڑی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک اٹھاکر پھر موڑی مگر پھر ’’چٹ‘‘ کی آواز آئی اور اس کے بھی دونوں ٹکڑے ہاتھ میں آگئے۔ میں نے سوچا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے اور اس طرح سے میں ماسٹر صاحب کی نگاہ میں آجاؤں گا۔
میں نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے والے اوپری شیلف کی ایک بوتل میں مردہ چھپکلی پڑی تھی۔ میں نے اسے بوتل میں سے نکالا اور چاروں طرف دیکھا۔ دائیں طرف سے تیسرے طالب علم نے دو نلکیاں مطلوبہ زاویے پر موڑ دی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے چھپکلی اس کی طرف اچھال دی۔ وہ اس کے سر پر جاپڑی۔ اس نے اپنے سر پر جو ہاتھ پھیرا تو مردہ چھپکلی اس کے ہاتھ میں آگئی۔
’’آئے۔۔۔ آئے۔۔۔۔امی۔‘‘ وہ گھبرا کر چیخا پھر دوڑتا ہوا اس پارٹیشن کی طرف جانے لگا جہاں استاد فیض الرحمان بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر یوں ہی حلق سے دو تین بے معنی سی آوازیں نکالیں اور گھبرا کر پوچھا:
’’کیا ہوا؟ کیا ہوا؟‘‘
اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں سمجھا تھا کہ اب وہ ماسٹر صاحب سے میری شکایت کرے گا اس لیے میں نے پھرتی سے وہ مردہ چھپکلی اٹھا کر اسی بوتل میں ڈال دی اور اس کی مڑی ہوئی شیشے کی نلکیاں اٹھاکر اپنے سامنے اور اپنی ٹوٹی ہوئی نلکیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ بھاری جسم والا وہ لڑکا جو بہت زیادہ بولتا اور بے پر کی ہانکتا تھا، مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے دیدے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔
ماسٹر صاحب آئے مگر انھیں ایسی کوئی غیر معمولی بات دکھائی نہیں دی کہ وہ کسی طالب علم سے پوچھ گچھ کرتے۔
’’معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں تو کوئی چھپکلی وغیرہ نظر نہیں آرہی ہے۔ تمھیں وہم ہوا ہوگا۔۔۔ چلو اپنا کام کرو۔‘‘ انھوں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔
اس لڑکے نے اپنی نلکیاں اٹھا کر قیف میں پھنسانی چاہیں تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ نلکیاں کیسے ٹوٹ گئیں۔
میں سر جھکائے تمام چیزوں کو سیٹ کرنے میں اس طرح مصروف تھا جیسے مجھے کسی چیز کا کچھ پتا نہ ہو۔
میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ بولنے والا لڑکا جس کا نام شاید باقر تھا، کچھ کہنے کے لیے بے تاب تھا اور اس کی زبان کھجلارہی ہے۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے اس لیے میں نے اسے سرگوشی میں آواز دی:
’’اے شش۔۔۔باقر۔۔۔‘‘ اس نے میری طرف نہیں دیکھا اور اسی طرح اس لڑکے کی طرف گردن گھمائے رہا جس کی نلکیاں میں نے اٹھائی تھیں۔
’’اے باقر۔۔۔ باقر۔۔۔ میری طرف دیکھ بھائی۔‘‘
اس نے تو میری طرف نہیں دیکھا البتہ شیلف کے دوسری طرف کھڑے ہوئے لڑکے ضرور پریشان ہو گئے اور ایڑیاں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں سر جھکا کر پھر اپنے کام میں مصروف ہوگیا مگر تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوگیا کہ چالاکی سے کسی کی نلکیاں اٹھالینا تو آسان ہے، لیکن انھیں ترتیب دے کر او کسیجن بنانا بہت دشوار ہے۔ اس کے لیے علم اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تعلیم کے بغیر گزار دیا تھا۔ یہ کتنا بڑا نقصان تھا۔
جب وہ لڑکا باقر میری طرف متوجہ نہیں ہوا تو مجھے جھنجلا ہٹ ہونے لگی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ اس لڑکے سے یا ماسٹر صاحب سے میری شکایت نہ کردے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے شیلف میں رکھی ایک بوتل میں مجھے پتھر کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا۔ شاید وہ سنگ مرمر تھا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پانی میں کیوں رکھا ہے۔
میں نے شیشی اٹھا کر اس کا پانی اپنی ناند میں گرادیا اور سفید پتھر کو چٹکی میں دبا لیا۔ اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے اس میں سے دھواں نکلتے دیکھا۔ چلو ہوگا۔ میں نے سوچا اور تاک کر اسے باقر کی کھوپڑی پر مارا۔ پتھر ہوا میں تیرتا ہوا اس کی کھوپڑی پر پڑا تو اس میں آگ لگ گئی۔
باقراچھل کر مڑا، اس نے میری طرف اور پھر فرش پر پڑے پتھر کی طرف دیکھا۔ پتھر دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور اس میں سے سفید گاڑھا دھواں نکل رہا تھا۔
’’ہائے۔۔۔ بچاؤ ۔۔۔آگ ۔۔۔آگ۔۔۔‘‘ اس نے بے ساختہ کہا۔ پھر یوں اچھلنے کودنے لگا جیسے اسے کسی نے شعلوں میں دھکیل دیاہو!
میں دوڑ کر اس کی طرف گیا اور میں نے جلتے پتھر پر اپنا جو تا رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ سا گیا مگر جب میں نے اس پر سے جو تا ہٹایا تو وہ پھر بھڑک کر چلنے لگا۔ اب تو میں بھی گھبرایا اور اس پر پاؤں مارنے لگا۔ اس دوران میں دوچار لڑکے اور آگئے۔ ان میں سے ایک نے حیرت سے کہا:
’’ارے! یہ تو فاسفورس ہے، اسے کس نے نکالا ہے؟‘‘
’’ فاسفورس، یہ کیا ہوتا ہے؟‘‘ میں حیرت سے سوچنے لگا۔
اس لڑکے نے کہا: ’’ فاسفورس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہوا میں جلنے لگتا ہے، اس لیے اسے پانی میں رکھتے ہیں۔ اسے مذاق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔‘‘
باقر نے کہا: ’’کسی نے میرے سر پر مارا تھا۔ میں ماسٹر صاحب سے شکایت کروں گا۔‘‘
اسے ماسٹر صاحب تک جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیوں کہ وہ آوازیں سن کر خود ہی اس طرف آگئے تھے۔ انھوں نے گہرا سانس لے کر کہا: ’’یہ فاسفورس شیشی سے کس نے نکالا ہے؟‘‘
کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
’’ہوں۔ میں خود معلوم کرلوں گا۔‘‘ انھوں نے سر ہلا کر گونج دار آواز میں کہا:
’’تم لوگ اپنا کام جلد ختم کرو۔۔۔ اور ہاں جوزف کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ یہاں پونچھا مار کر صفائی کرے۔‘‘
سب لڑکے اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے اور ایک لڑکا تجربہ گاہ سے باہر چلا گیا۔ جوزف یقینا جمعدار کا نام ہوگا جسے بلانے وہ باہر گیا تھا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ فاسفورس کے جلنے سے سب کی توجہ ادھر ہو گئی اور باقر اس بات کو بھول گیا کہ میں نے دوسرے لڑکے کی میزسے نلکیاں اٹھائی تھیں۔
’’ باقر! تمھارے کپڑے تو نہیں جلے؟‘‘ میں نے اس سے ہم دردی جتاتے ہوئے پوچھا۔
’’ نہیں تو۔‘‘ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر اور جسم کو تھپ تھپا کر کہا: ’’مگر یہ تم مجھے باقر کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا نام باقر کب ہے میں تو رشید ہوں۔‘‘
’’ اوہ ہاں سلمان!‘‘ میں نے گڑ بڑا کر کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ آواز دینے پر میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا تھا۔
دوسرے لڑکوں کی طرح میں نے بھی اسپرٹ لیمپ روشن کردیا اور اسے امتحانی نلکی کے نیچے حرکت دینے لگا تاکہ اوکسیجن نکل کر دوسری طرف جار میں جمع ہو جائے۔ میں نے سوچا آج بہرحال کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا۔ اوکسیجن نہ سہی نائٹروجن یا کاربن ڈائی اوکسائڈ ہی سی۔ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو میں اوکسیجن کے دو تین جار اٹھالوں گا۔
وہ لڑکا جو جمعدار کو بلانے گیا تھا تھوڑی دیر بعد واپس آکر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھ سے ہی نہیں دوسرے لڑکوں سے بھی نلکیاں ٹوٹ گئی تھیں جنھیں انھوں نے نیچے رکھی ہوئی پلاسٹک کی ٹوکریوں میں ڈال دیا تھا تاکہ جمعدار آکر سب کو سمیٹ لے۔
دس منٹ بعد تجربے گاہ میں ایک ٹرالی داخل ہوئی اور ایک لمبا سا آدمی اسے دھکیلتا ہوا اندر آگیا۔
’’کھٹ ۔۔۔کھٹ۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔‘‘
اس کے قدموں سے عجیب سی آواز پیدا ہورہی تھی۔
وہ پہلی قطار میں جاکر پلاسٹک کی نوکریاں ٹرالی میں الٹنے لگا۔
’’کھٹ ۔۔۔کھٹ۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔‘‘ وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ سلطان احمد پر بھی تو کسی ایسے ہی آدمی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔
وہ پہلی قطار کی صفائی کرکے میری طرف آیا۔ میں اس کی طرف مڑا مگر یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ اس نے اپنے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ سلطان احمد نے یہ بتایا تھا کہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ہیں جنھیں وہ راجپوتوں کی طرح اٹھائے رہتا ہے اور دائیں رخسار پر زخم کا ایک لمبا سا نشان ہے۔ اس کی ایک ٹانگ غالبا ًلکڑی کی تھی!
مونچھیں تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھیں اور گال ۔۔۔گال صاف تھے۔۔۔اوہ نہیں۔۔۔ زخم کا نشان بائیں یا دائیں کلائی پر تھا۔ لیکن اس کی کلائیاں بھی میں نہیں دیکھ سکتا تھا ،اس لیے کہ وہ قمیص کی آستینو ں میں چھپی ہوئی تھیں۔ میرا دل دھک ۔۔۔دھک ۔۔۔کر رہا تھا۔
’’ یہ۔۔۔ یہ کون ہے؟‘‘ میں نے رشید کے نزدیک جاکر پوچھا۔
’’جمعدار ہے، کیوں؟‘‘
’’اس کا نام کیا ہے؟‘‘ میں نے اضطراب سے پوچھا۔
’’جوزف مسیح۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اسے پہچان کیوں نہیں پارہے ہو۔ سلطان! یہ تمھاری حویلی پر بھی تو کام کرتا ہے؟‘‘ اس نے کہا۔
یہ سن کر میرا جسم جھن جھنانے لگا۔
سلطان احمد کی زبانی
میں ڈیوڈ مسیح کو روتا ہوا چھوڑ آیا۔ اس نے پرویز مستانہ کو اس کے والدین سے الگ کیا تھا اس لیے مجھے اس سے کوئی ہم دردی نہیں تھی۔ رات میں بستر پر لیٹا تو مجھے خوب گہری نیند آئی، اس لیے کہ میں نے چالیس پچاس بالٹی پانی بھرا تھا اور میرے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا۔ خواب میں دیر تک مجھے اپنی امی اور بھائی بہن نظر آتے رہے۔
صبح جب حلوا پوری کا ناشتا کرنے بیٹھا تو آپا ذکیہ نے پان مسالا چباتے ہوئے کہا:
’’ اے مستانے ! تو ہم سب کو بھنگوڑہ کب لے چلے گا؟‘‘
’’بھنگوڑہ؟ وہ کیا ہے؟‘‘ میں نے حیرت سے کہا۔
’’ وہی سمندر میں ایک جزیرہ ہے، کیماڑی کے بعد۔‘‘ انھوں نے ایسے کہا جیسے میری معلومات میں اضافہ کر رہی ہوں۔
’’آپا منوڑے کا ذکر کر رہی ہیں۔‘‘ درخشاں نے اپنا بستہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔
’’اچھا منوڑا ،مگر کیا تم سب جاؤ گی میرے ساتھ؟‘‘ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں کیماڑی اور منوڑا خود بھی دیکھنا چاہتا تھا بلکہ پہلے روز سے جب کہ میں کراچی آیا تھا یہ خواہش میرے دل میں مچل رہی تھی، لیکن اپنی سات بہنوں کو وہاں لے جانا اور سلامتی کے ساتھ واپس لانا مجھے ابھی سے بہت دشوار معلوم ہوا۔
’’ پچھلے ہفتے آپ نے وعدہ کیا تھا بھائی جان۔‘‘ نگہت آرا نے باورچی خانے کے دروازے سے کہا۔ وہ چائے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔
’’مجھے تو یاد نہیں ہے۔‘‘ میں نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مستانے، نے ان لوگوں سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہو، لیکن اس کی جگہ تو اب میں آچکا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ چلنا مصیبت معلوم ہو رہا تھا۔
’’ یاد کیسے نہیں ہے، آپ کو چلنا پڑے گا۔‘‘ عصمت آر ااور نگہت آرا نے یک زبان ہو کرکہا۔ پھر میرے قریب آئیں اور مجھے جھنجھوڑنے لگیں۔ یہ اپنائیت اور محبت کا عجیب انداز تھا۔مجھے ان پر پیار آگیا۔ میں نے ہنس کر کہا: ’’اچھا اچھا چلوں کا شیطان کی خالائو! چلوں گا۔‘‘
’’کب۔‘‘ انھوں نے اشتیاق سے پوچھا۔
’’آج ہی شام کو۔‘‘ میں نے جواب دیا۔
’’شام کو دیر ہو جائے گی بھائی جان۔ دوپہر کو چلیں گے، شام تک لوٹ آئیں گے۔‘‘ درخشاں بولی۔
’’ٹھیک ہے، منظور۔‘‘ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس دن کام پر سے میں جلدی لوٹ آیا۔ ساتوں بہنوں نے تیاری شروع کی تو ایک گھنٹہ اس میں لگ گیا۔ ہم تین بجے تک گھر سے نکل پائے۔ میں اپنے ساتھ جو پیسے لایا تھا انھیں تو کسی جیب کترے نے اڑا لیا تھا۔ پرویز بھی کچھ دے دلا کر نہیں گیا بلکہ اس کے ذمے جو قرض تھے وہ میری گردن پر لد گئے تھے۔
میں نے استاد برکت سے پیشگی لے لیا ،مگر ہاتھ میں اب بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی بہنوں کو ٹیکسی میں منوڑے لے جاتا۔ مجبورا ًبس کا سہارا لیا۔ آپا ذکیہ نے بتایا کہ پانچ نمبر کی بس میں سوار ہونا ہے۔ جب اس نمبر کی بس آگئی تو میں نے پہلے بہنوں کو سوار کرایا پھر خود بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کنڈکٹر آیا اور اس نے ٹکٹ کی آواز لگائی تو میں اسے پیسے دینے لگا۔ تب معلوم ہوا کہ یہ بس کیماڑی نہیں جائے گی۔ اسے ٹاور سے لیاقت آباد جاناہے۔ میں گھبرا کر اتر آیا اور تمام لوگوں کو بھی اتار لیا۔ دیکھا تو وہ5C کی بس تھی۔ بڑی مشکل سے کیماڑی کی بس ملی، مگر میں نے اس میں سوار ہونے سے پہلے کنڈکٹر سے بھی تصدیق کرلی۔ مجھے کھڑکی کے پاس جگہ ملی تھی، اس لیے مشہور عمارتوں کو دیکھنے کا اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا موقع مل گیا۔
ابا جی کی وصیت پر عمل کرکے میں ایک سائنس داں بننا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے سمندر سے بھی عشق تھا۔ میں بحری جہازوں میں بیٹھ کر دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے میرین انجینئرنگ کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اگر پاکستان نیوی کے شعبہ انجینئرنگ میں شامل ہو جاتا تو میرے تمام شوق پورے ہو سکتے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک ٹیسٹ بھی دیا تھا اور اپنے کراچی کے ایک دوست رئوف سے بھی رابطہ کیا تھا۔ رؤف نیوی میںلیفٹیننٹ تھا۔
بس کیماڑی پر رکی تو تمام مسافر اتر پڑے۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ اتر کر آگے گیا تو ایک بڑا سا شیڈ دکھائی دیا۔ اس شیڈ سے لکڑی کے زینے نیچے چلے گئے تھے جہاں لانچیں مسافروں کو منوڑے کی طرف لے جارہی تھیں۔ وہ لانچیں عام لوگوں کے لیے تھیں جب کہ کچھ فاصلے پر نیوی سے تعلق رکھے والے جوان چھوٹی لانچوں اور موٹر بوٹوں میں سوار ہوکر آجا رہے تھے۔ سفید براق وردیاں پہنے جوان مجھے بہت اچھے لگے۔
لکڑی کا وہ زینہ جس سے لوگ نیچے جارہے تھے ،مسلسل پانی پڑنے سے کائی زدہ اور پھسلواں ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں پر ریلنگ بھی نہیں تھی کہ سہارا لے کر نیچے جایا جاسکتا۔ چھوٹی بہنیں تو اچکتی پھاندتی ہوئی لانچ میں جاکر بیٹھ گئیں مگر آپا ذکیہ گھبرا گئیں۔ ویسے بھی ان کے پاؤں میں اونچی ایڑی کا چمکیلا سینڈل تھا ،اس لیے پاؤں زمین پر جم کر نہیں پڑ رہا تھا۔
’’مستانے! میں نیچے کیسے جاؤں؟‘‘ انھوں نے گھبرا کر کہا۔
’’ جیسے سب لوگ جارہے ہیں۔‘‘ میں نے اطمینان سے کہا۔
انھوں نے میرے ہاتھ کا سہارا لے کر زینے پر قدم رکھا مگر تین چار قدمچے طے کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ دھم سے زینے پر گر یں اور ان کا چمکیلا سنہرا سینڈل اڑتا ہوا پانی میں چلا گیا۔ انھوں نے سہم کر حلق سے ڈری ڈری آواز نکالی: ’’ہائے اللہ! یہ سمندر اتنا نچا کیوں ہے؟‘‘
’’سمندر اگر اونچا ہو جائے تو پانی ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہو جائے گا۔‘‘ میں نے کہا۔
آپا گھبرائی ہوئی تھیں اور ان میں نیچے جانے کی ہمت نہیں تھی۔
’’میری مانو تو تم لوگ ہو آؤ اور مجھے یہیں چھوڑ دو۔‘‘ انھوں نے کہا۔
’’ کیا کر رہی ہو ئی! اٹھو تو سہی۔ لوگ کیا کہیں گے؟‘‘ میں نے ناگواری سے کہا۔
انھوں نے دوسرا سینڈل اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور میرے سہارے لانچ میں پہنچ گئیں۔ لانچ چلنے والی تھی کہ انھوں نے ’’اے میرا سینڈل‘‘ کہہ کر شور مچادیا۔ ان کا سنہرا سینڈل پانی میں ڈوبا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی ایڑی لکڑی کی تھی۔ وہ لانچ سے تھوڑے فاصلے پر تیر رہا تھا۔ ایک پیراک بچے نے اسے پانی سے نکال کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انھوں نے شکریے کے ساتھ اسے اٹھنی دی۔ ایسے بہت سے بچے وہاں سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ لوگ اٹھنی چونی پانی میں پھینک دیتے تو وہ فوراً پانی میں غوطہ لگا کر اسے تہ میں بیٹھنے سے پہلے پکڑ لیتے اور پھر اوپر آجاتے۔ یہ نظارہ بے حد دل فریب تھا!
سمندر کے نمکین پانی میں پڑے رہنے سے سینڈل کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہرا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر آپا کو رونا آگیا۔ انھوں نے روہانسی آواز میں کہا:
’’ میں اس کم بخت دکان دار سے کل نمٹوں گی۔ تو بھی میرے ساتھ چلیو۔‘‘
’’ اچھا چلوں گا۔ ابھی تو سکون سے بیٹھو۔‘‘ میں نے کہا۔
لانچ منوڑے کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ جی چاہتا تھا کہ کپڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگادوں اور لانچ کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا کہیں دور نکل جاؤں۔ آگے جاکر بڑے جہاز کھڑے دکھائی دیے۔وہ لنگر انداز تھے۔ لہریں خوب شور مچا ری تھیں اور لانچ سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، لہروں کو کاٹتی اور ڈگمگاتی ہوئی۔
شروع میں سمندر پر سکون تھا، اس لیے لانچ روانی سے بہتی رہی، مگر بعد میں جب اونچی لہریں آنے لگیں تو وہ دائیں بائیں ڈگمگانے لگی۔
’’ اے۔۔۔ اے۔۔۔ہے۔۔۔ارررر۔۔۔۔‘‘ آپا ذکیہ کے حلق سے ڈری ڈری سے عجیب آواز نکلی۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے بھی سریلی آواز میں ان کا ساتھ دیا۔
میں پہلے تو لطف اندوز ہو تا رہا مگر ایک آدھ بار میرے حلق سے بھی ڈری ڈری سی آواز نکل گئی۔ حال آنکہ میں اچھا پیراک ہوں اور رواں پانی میں ایک آدھ فرلانگ تیر سکتا ہوں۔
’’ جل تو جلال ،آئی بلا کو ٹال۔‘‘ آپا نے رودینے والی آواز میں کہا اور لانچ کا ایک تختہ زور سے پکڑ لیا۔ وہ ایسی ساکت بیٹھی تھیں جیسے کوئی بت ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ حرکت کریں گی تو لانچ ڈوب جائے گی۔
میں نے ان کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو انھوں نے گھبرا کر کہا:
’’اررر۔۔۔ کک کیا کر رہے ہو بھیا! یہاں جان پر بنی ہے اور تمھیں مذاق کی سوجھی ہے۔‘‘
’’اے۔۔۔ قق۔۔۔قق۔۔۔ققہ۔۔۔‘‘ لانچ والا عجیب انداز سے ہنسا: ’’آپا! آپ لوگ ڈرتاکائے کو اے۔ امارا لانچ ڈوبنے کو نئیں سکتا۔‘‘ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ اس کا جسم مضبوط تھا اور بال چھوٹے گھنگھریالے تھے۔
’’ رہنے دے، تیری بات پر اعتبار نہیں ہے۔‘‘ آپا نے ہونٹ سکیڑ کر کیا: ’’اگر لانچ ڈوب ہی گئی تو تو کیا کرلے گا۔‘‘
’’ اللہ پھر تو ہمارے پیٹ میں بہت سا پانی بھر جائے گا۔‘‘ عصمت آرا نے کانپتی آواز میں کہا، پھر میرا شانہ جھنجھوڑ کر بولی: ’’بھائی جان! منوڑا کب آئے گا؟‘‘
’’ بس آنے ہی والا ہے، ڈرو نہیں احمق!‘‘ میں نے ہنس کر کہا:’’ سمندری سفراسی لیے تو دل چسپ لگتا ہے کہ ہر لمحے جان پر بنی رہتی ہے۔‘‘
درخشاں میرے قریب اگر بیٹھ تھی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی: ’’بھائی جان! میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیجیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔‘‘
’’بھیا! میرا بھی خیال رکھنا۔‘‘ آپا نے دور سے کہا۔
میں نے کہا: ’’مجھے تم سب کا خیال ہے اور اب تم لوگ کنارے پر پہنچنے والے ہو۔ وہ دیکھو ،وہ رہی جیٹی۔‘‘
کنارہ دیکھ کر سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اب تک ایک دوسرے سے لپٹی اور سانس رو کے بیٹھی تھیں۔ جب لانچ جیٹی سے جالگی تو ان کے ہونٹوں پر پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔
منوڑے پر اترنے کے بعد تھوڑا سا چلنا پڑا۔ پھر ٹھاٹھیں مارتا اور جھاگ اڑا تا سمندر نظر آیا تو سب بہنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ چھوٹی بڑی لہریں جھاگ اڑاتی ہوئی کنارے تک آ جا رہی تھیں۔ یہ تماشا مسلسل جاری تھا۔
میں تو جیسے مسحور ہوگیا۔ یوں دیر تک گم صم کھڑا سمندر کو دیکھتا رہا جیسے کسی نے مجھے جادو کے زور سے پتھر کا بنادیا ہو! تھوڑی دیر بعد میں نے جوتے اور موزے اتارے اور پتلون پنڈلیوں تک چڑھانے کے بعد سمندر میں کچھ دور تک چلا گیا۔ وہاں زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ ساحل پر گہرے گڑھے تھے جو تیرنے والوں کے لیے خطرے کا باعث بنتے تھے۔
نگہت، عصمت، درخشاں اورفرزانہ سب ہی لطف اندوز ہو ئیں۔ آپا پہلے تو ڈر کے مارے پانی میں نہیں گئیں اور دور سے نظارہ کرتی رہیں۔ پھر دوسروں کے مجبور کرنے پر وہ بھی پانی میں چلی گئیں لیکن اس وقت زور زور سے چیختی ہوئی وہاں سے نکل آئیں جب ایک کیکڑے نے ان کی ٹانگ پر کاٹ لیا۔ اس نے آپا کی ٹانگ پر ہی نہیں کاٹا بلکہ ان کے انگوٹھے سے بھی لپیٹ گیا۔ وہ ہائے ہائے کرتی خشکی پر آئیں تو سب ان کے گرد جمع ہو گئے مگر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ کیکڑے کوپکڑتا۔ میں نے ہی بہادر بن کر اسے پکڑا اور آپا کے انگوٹھے سے چھڑایا۔
آپا واپس آنے کے لیے شور مچانے لگیں۔ باقی بہنیں بھی تھک چکی تھیں اور پانی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کے سر بھاری ہورہے تھے، اس لیے میں نے واپس چلنا ہی مناسب سمجھا۔ ہم وہاں سے پلٹ کر جیٹی کے قریب آئے اور ایک لانچ میں بیٹھنے لگے۔
تھوڑے ہی فاصلے پر وہ جگہ تھی جہاں سے نیوی کے جوان اپنی لانچوں میں سوار ہو رہے یا اتر رہے تھے۔ اچانک ایک نوجوان پروقار انداز میں چلتا ہوا میری طرف آگیا۔ اس نے صاف اور شفاف انگریزی میں کہا:
’’ ہیلو سلطان! تم یہاں کب آئے؟ تم نے تو آنے کی اطلاع تک نہیں دی۔ مائی ڈیر! تم نے نیوی کے شعبہ انجینئرنگ میں جس عہدے کی درخواست دی تھی اس کا نتیجہ نکل آیاہے۔‘‘
میں وہاں گم صم کھڑا رہ گیا۔ اس وقت عجیب سی صورت حال سے دوچار تھا۔ ظاہر ہے کہ مجھے انگریزی ہی میں جواب دینا تھا۔ اگر میں اسے جواب دے دیتا تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میرا راز کھل جاتا اور یہ ظاہر ہو جاتا کہ میں پرویز کے بجائے سلطان ہوں۔ اگر جواب نہ دیتا اور خاموشی اختیار کیے رہتا تو یہ نہ معلوم ہوتا کہ میں نیوی کے کیڈٹ امتحان میں کام یاب ہوا ہوں یا ناکام! اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ لیفٹیننٹ رئوف تھا۔
اور اب پرویز مستانہ کی زبانی سنئے
رشید نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر پوچھا:’’ یہ تمھیں کیا ہو گیا ہے سلطان؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟‘‘
میں نے اپنی کیفیت پر قابو پالیا اور جوزف مسیح کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ گھبرا سا گیا ہے۔ مجھ سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اگر وہ حویلی میں صفائی پر مامور تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے سامنے جھکتا اور ادب سے پیش آتا۔
میں انتظار کرتا رہا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے جب میرے قریب آیا تو اس نے مری مری ی آواز میں کہا:’’ سلام باؤجی۔‘‘
میں نے کہا:’’وعلیکم السلام، کام کیسا چل رہا ہے؟ تم حویلی میں نہیں آئے؟‘‘
’’آ یا تو تھا مگر آپ اس وقت آرام کر رہے تھے۔ مجھے تو چوہدری صاحب نے بہت صبح آنے کا حکم دے رکھا ہے جی۔‘‘
’’اچھا۔۔۔ اچھا۔۔۔ ٹھیک ہے۔‘‘ میں نے سر ہلا کر کہا۔
لاہور میں سردی کے موسم میں لوگ عمو ماً صافے کا کنارہ چہرے پر لپیٹ لیتے ہیں جسے ڈھاٹا کہتے ہیں۔ یہ چوں کہ ایک عام سی بات تھی اس لیے میں اس پر اعتراض نہ کرسکا۔ البتہ اس بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردیا۔ مثلاً یہ کہ اگر وہ حویلی کا ملازم بھی تھا تو اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں کوئی چور تھا!
اب مجھے اسکول سے گھر جانے کی جلدی تھی تاکہ میں وہ جگہ دیکھ سکوں جہاں وہ اپنا سامان رکھتا ہے۔ اس روز کوشش کے باوجود مجھ سے اوکسیجن نہیں بن سکی جس پر ماسٹر صاحب بہت برا مانے۔
اس دن گھر آنے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور کھانا کھا کر امی کے کمرے میں گیا۔ صبح جب میں اپنی خیریت بتانے ان کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھیں۔ وہ چوں کہ تہجد گزار تھیں، اس لیے اندھیرے اٹھتی تھیں اور ناشتا کرنے کے بعد سوجاتی تھیں۔
جب میں ان کے کمرے میں پہنچا اور میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے میری بلائیں لیں اور تشویش سے کہا:
’’تم خیریت سے تو ہونا میرے لعل؟ احمد بتا رہا تھا کہ تمھارا پیر صبح زینے پر پھسل گیا تھا؟‘‘
’’ جی ہاں ٹھیک ہوں امی! زیادہ چوٹ نہیں آئی، بس پیر ذرا سا چھل گیا تھا، ایک آدھ روزمیں بالکل ٹھیک ہوجائے گا۔‘‘
انھوں نے بے چین ہو کر میرا چہرہ ٹٹول کر دیکھا، پھر سرگوشی میں بولیں:
’’تم نے سلطان کو بلانے کے لیے خط وغیرہ لکھا؟‘‘
’’ سلطان کو بلانے کے لیے کیوں؟ یہاں تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اسے وہیں رہنے دیجیے امی۔‘‘
’’تم نے ابھی تک کچھ معلوم نہیں کیا؟ میں اپنے بچے سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔‘‘
’’تو کیا میں واپس چلا جاؤں؟‘‘ میں نے گھبرا کر کہا۔
’’نہیں، تم بھی یہیں رہو۔‘‘
’’ مگر اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ میں نے سلطان بن کر انھیں دھوکا دیا ہے۔‘‘ میں نے پریشان ہو کر کہا۔
’’تم نے دھوکا نہیں دیا ہے۔ لوگوں نے خود دھوکا کھایا ہے۔ جب وہ آجائے گا تو میں حویلی کے لوگوں کو سب سمجھا دوں گی۔‘‘
’’ایں۔۔۔ اچھا!‘‘ میں نے حیرت سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا:’’ امی! یہ جوزف مسیح کون ہے؟‘‘
’’جوزف مسیح؟ اس کے بارے میں تمھیں کیسے پتالگا؟‘‘
’’ وہ حویلی میں کام کرتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کب سے کام کر رہا ہے اور اسے کس نے رکھا ہے؟‘‘
انھوں نے تشویش سے کہا: ’’میرا خیال ہے کہ کسی نے نہیں رکھا۔ اس لیے کہ اسے تو تمھارے ابا جی۔۔۔مم۔۔۔ میرا مطلب ہے سلطان کے اباجی نے ڈیوڈ مسیح کے ساتھ ہی حویلی سے نکال دیا تھا۔ یہ دونوں بھائی پہلے حویلی میں کام کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ چوہدری حشمت صاحب گیراج سے کار نکال رہے تھے کہ ڈیوڈ مسیح کا بچہ اس کی زد میں آگیا۔ اس کی ماں نے اس دودھ پیتے بچے کو کیاریوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور خود کسی کام میں لگ گئی تھی۔ بچہ گاڑی کے پچھلے ٹائر سے دب کر ختم ہو گیا۔ چوہدری صاحب بہت روئے دھوئے۔ انھوں نے ڈیوڈ اور اس کی بیوی سے بہت معافی مانگی مگر وہ غصے میں اندھا ہورہا تھا۔ چوہدری صاحب اسے معاوضہ دینے پر بھی تیار تھے مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ پولیس نے اسے لمبی سزا دے دی۔ سنا ہے کہ وہ کراچی چلا گیا تھا۔ یہ جوزف اس کا بھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے حویلی میں پھر کہاں رہنا تھا۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس نے خود ہی کام چھوڑ دیا تھا، لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ وہ پھر کام کر رہا ہے۔ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ معلوم میں کب سے کر رہا ہے۔۔۔ میں گلزار سے پوچھ کر بتاؤں گی؟‘‘
’’رہنے دیں امی! میں خود معلوم کرلوں گا۔‘‘
’’ بیٹا! تجھے تو اس کے بارے میں معلوم ہوگا؟‘‘ امی نے اچانک پوچھا ۔
’’کس کے بارے میں امی؟‘‘ میں نے حیرت سے کہا۔
’’ اسی ڈیوڈ کے بارے میں۔‘‘
’’نہیں تو، بھلا مجھے اس کے بارے میں کیوں معلوم ہونے لگا۔ وہ تو آپ نے ابھی بتایا تو معلوم ہوا۔‘‘
’’ حیرت ہے۔‘‘ انھوں نے آہستہ سے کہا۔ پھر گہرا سانس لینے کے بعد بولیں:
’’پرویز بیٹا! تیری پرورش کس نے کی ہے؟مم۔۔۔ میرا مطلب ہے تیرے والد کا کیا نام ہے؟‘‘
میں نے جواب دیا: ’’ان کا نام قریشی صاحب ہے۔ میری سات بہنیں ہیں۔ امی! میں ان کو یہاں لاکر آپ سے ملواؤں گا۔‘‘
’’ ہاں ٹھیک ہے۔‘‘ انھوں نے کہا، پھر کوئی خیال آتے ہی مجھے لپٹا لیا اور کہنے لگیں:
’’ مگر اب میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تم ایسا کرو کہ سلطان کو بھی یہاں بلالو۔ میرا دل خالی خالی سا ہو رہا ہے۔‘‘
’’ٹھیک ہے بلالوں گا۔‘‘ میں نے آہستہ سے کہا۔
انھوں نے دھیرے سے کہا: ’’کل ہی تار دے دینا۔ جب اسکول سے واپس آؤ تو تار گھر پر اتر کر اسے تار دے دینا۔‘‘
میں سر ہلا کر ان کے پاس سے چلا آیا۔ اب مجھے جستجو ہو رہی تھی کہ جوزف مسیح کے بارے میں معلوم کروں مگر میں تو سلطان احمد کی جگہ تھا۔ سلطان کو سب کچھ معلوم ہونا چا ہیے۔ اگر میں کسی سے کچھ پوچھوں گا تو یہی جواب ملے گا کہ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ اب تک کہاں تھے؟ کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟‘‘
میں نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ میں فوزیہ کے کمرے کی طرف گیا اور اس کے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی: ’’کون ہے؟‘‘ پھر قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ فوزیہ دکھائی دی۔ اس نے حیرت سے کہا:
’’ آپ؟ مگر آپ تو ہمیشہ مخصوص انداز سے دستک دیتے تھے۔‘‘
’’ میں نے اپنا انداز بدل دیا ہے۔ تم اس کی پروا نہ کرو۔‘‘
’’آپ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔‘‘ اس نے پلکیں جھپکا کر کہا:
’’آپ نے کہا تھا کہ پرستان سے آئے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ہسپتال سے اپنا دماغ بدلواکرآگئے ہیں۔‘‘
میں نے بھاری آواز میں کہا: ’’ممکن ہے ایسی ہی بات ہو۔‘‘ پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ راحیلہ معلوم نہیں اس وقت کہاں تھی۔ دائیں طرف دو بستر تھے جو خالی پڑے تھے اور بائیں طرف ایک بڑی سی میز اور دو کرسیاں تھیں۔ شاید وہ اس پر اسکول کا کام کرتی تھی۔ میز پر چند کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں جاکر کرسی پر بیٹھ گیا اور کتابیں الٹنی پلٹنی شروع کردیں۔دو کتابوں کے نیچے وہی البم تھا جو ایک روز پہلے اسکول جاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور جو اس نے مجھے نہیں دیکھنے دیا تھا۔ بہرحال اس وقت میں البم کو دیکھ سکتا تھا اور فوزیہ مجھ سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتی تھی۔
’’فوزیہ! ایک بات ہے جو میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا مگر اب بتانی ہی پڑ رہی ہے۔ مجھے کچھ آدمیوں نے اغوا کرلیا تھا۔ انھوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے میرے دماغ میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی ہو، لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔‘‘
’’نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔‘‘ اس نے مسکرا کر کہا جیسے میری بات کو ایک شان دار گپ یا ہوائی سمجھ رہی ہو۔ اس نے چند لمحوں بعد کہا:
’’یہ بتائیے کہ آپ کو کن لوگوں نے اغوا کرلیا تھا؟ اور کیوں؟‘‘
’’رقم وصول کرنا چاہتے تھے۔ میں انھیں چکمہ دے کر بھاگ آیا۔‘‘ میں نے کہا، پھر خاموشی سے البم کے صفحات پلٹے، مگر وہ صفحہ کہیں دکھائی نہیں دیا جس پر دو ایک جیسے بچوں کی تصویر تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ فوزیہ نے اسے البم سے نکال لیاتھا!مگر کیوں؟
میں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جوزف کے متعلق بہرحال معلومات حاصل کرنی تھیں ،اس لیے میں نے کہا:’’فوزیہ،یہ نیا جمعدارجوزف جب سے آیا ہے صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے کان سے پکڑ کر نکال دینا چاہیے۔‘‘
’’صفائی! ہاں یہ تو میں بھی محسوس کر رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت صبح آتا ہے اس لیے پتاہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ باقی سارا دن اپنی کوٹھری میں چار پائی توڑتا رہتا ہے یا پھر گھومتا رہتا ہے۔ اسے چلتا ہی کردیں۔ دو مہینے پہلے رام لچھمن کام کرتا تھا اسے معلوم نہیں
کیوں ابو نے علاحدہ کردیا۔‘‘
’’ میں ذرا اسے ابھی جاکر ڈانٹنا ڈپٹنا چاہتا ہوں۔ تم بھی چلو۔‘‘
’’مجھے کام ہے۔ آپ ہی ہو آئیے۔‘‘ اس نے کہا۔
میں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر آکر میں نے راہ داری طے کی، پھر گیلری میں جاکر برآمدے اور اس کے بعد لان میں پہنچ گیا۔ لان کے دائیں طرف پھاٹک کے قریب ملازموں کے کوارٹر تھے۔ میں کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ جوزف کا کوارٹر کون سا ہے، اس لیے اندازے سے اس طرف چل پڑا۔ جب میں پہلے کوارٹر کے قریب پہنچا تو حمیدے ڈرائیور کی صورت نظر آئی۔ وہ کسی کام سے کوارٹر سے نکل رہا تھا۔ اس نے محبت سے پوچھا:
’’کہاں جارہے ہیں چھوٹے صاحب؟‘‘
’’جوزف کی کوٹھری تک۔ اس سے ایک بات پوچھنی تھی۔‘‘
’’ پتا نہیں کیا بات ہے، منجھلے چوہدری صاحب بھی ادھر ہی گئے ہیں؟‘‘
’’ کون؟ ماموں صاحب؟‘‘ میں نے پوچھا۔ ان کا نام سن کر میرے خون کی روانی تیز ہو چکی تھی۔ ’’وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟‘‘
’’معلوم نہیں سرکار۔‘‘ وہ بولا اور پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ میں اندازے سے آگے بڑھا تو تیسرے کوارٹر میں جوزف کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا اور ماموں گلزار اندر کھڑے تھے۔ جوزف اندر سے کوئی چیز نکال کر آرہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت سانولی تھی اور اوپری ہونٹ پر بھاری اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو راجپوتوں کی طرح اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی اور وہ اسے گھسیٹ کر چل رہا تھا۔’’ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔گھر۔۔۔گھر۔۔۔گھر۔۔۔‘‘
’’یہ لیجیے۔‘‘ اس نے کہا اور ماموں کی طرف ایک ڈبا بڑھا دیا۔ اس پر لگا ہوا لیبل مجھے دور سے نظر آگیا۔ وہ گریس کا ڈبا تھا اور اسے ہم لوگ موٹر سائیکلوں کے پرزوں پر لگانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ماموں کی پیٹھ میری طرف تھی، اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکے مگر جوزف نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بری طرح سے گھبراگیا۔
سلطان احمد کی زبانی
میری سمجھ میں ایک ترکیب آگئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرف کھینچا جدھر سے وہ آیا تھا۔ اپنی بہنوں کا خیال آتے ہی میں نے پلٹ کر انھیں لانچ سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم اس جگہ سے دور ہو گئے تو میں نے کہا: ’’میں چند دن کے لیے کراچی میں اپنے عزیزوں کے ہاں آیا تھا۔ وقت کم تھا اس لیے تم سے ملنا یاد نہیں رہا۔‘‘
میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میری بہنیں لانچ سے اتر آئی تھیں اور اب تشویش سے رؤف کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ نیوی کا ایک افسر مجھے اپنے علاقے میں کیوں لے گیا ہے۔ میں نے انھیں دلاسا دیتے ہوئے کہا: ’’تم لوگ ٹھیرو میں ابھی آتا ہوں۔‘‘
’’مجھے یقین نہیں آرہا ہے کہ یہ تمھارے رشتے دار ہیں۔ رؤف نے شک کے لہجے میں کہا۔
میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا: ’’میرے نتیجے کا کیا رہا؟ میں کام یاب ہوا کہ نہیں۔‘‘
’’ تم کام یاب ہو چکے ہو۔‘‘ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا:’’مگر میں یہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ محکمے کی ڈاک کے ذریعہ سے تمھیں لاہور کے پتے پر آگاہ کیا جائے گا۔‘‘
’’اوہ! اللہ کا شکر ہے۔‘‘ میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔
وہ بولا:’’آؤ جہاز پر چلو تمھیں کھلے سمندر کی سیر کراؤں۔ اپنی رشتے داریوں کو بھی ساتھ لے لو۔‘‘
’’ نہیں میں پھر کسی وقت آؤں گا۔‘‘ میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس کے ساتھ رہا تو میرا راز کھل جائے گا اور میری بہنوں کو معلوم ہو جائے کہ میں پرویز نہیں ہوں۔ اس راز کے کھلنے پر یقینا ان لوگوں کو صدمہ پہنچتا۔
’’ او کے، آؤ تم لوگوں کو کیماڑی پر چھوڑ دوں۔‘‘اس نے کہا: ’’دیکھو انکار نہ کرنا۔‘‘
میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ مجبوراً میں نے اپنی بہنوں کو اس طرف بلا لیا۔ وہ حیران تھیں کہ ان کے موٹر سائیکل میکینک بھائی کی دوستی نیوی افسرسے کیسے ہے؟
میری سات بہنوں اور ہم دونوں کو ملاکر چوں کہ نو افراد ہوگئے تھے، اس لیے رؤف نے ایک بڑی لانچ لے لی۔ ہم دونوں آگے اور بہنیں پیچھے بیٹھ گئیں۔ رؤف سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی اس لیے وہ بہت کچھ سننا اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ حال آنکہ وہ کم ہی بات کرتا تھا مگر اس وقت وہ خاموش ہی نہیں ہو رہاتھا۔ شکر ہے کہ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا اسی لیے میری بہنیں نہیں سمجھ پارہی ہوں گی، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہو گا کہ میں اس کی باتیں کیسے سمجھ رہا ہوں اور میری اس سے کیسے دوستی ہوگئی۔
رئوف باتیں کیے جارہا تھا اور میں صرف ہوں ہاں میں اس کا جواب دے رہا تھا۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کیماڑی آجائے اور میں لانچ سے اتر کر بھاگ لوں مگر سفر جیسے بہت لمبا ہو گیا تھا اور خشکی قریب ہی نہیں آرہی تھی۔
’’ تم بہت سنجیدہ اور خاموش سے ہو، کیا بات ہے؟ مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی! میں نے تمہیں کیڈٹ افسر بننے کی خوش خبری سنائی، مگر تمھارے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک دکھائی نہیںدی؟‘‘
میں بانچھیں پھاڑ کر مسکرایا اور میں نے آہستہ سے اردو میں کہا:’’ دراصل میں خوش خبری پاکر حیرت زدہ تھا، اس لیے میرے منھ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔‘‘
’’تم کہاں ٹھیرے ہوئے ہو؟‘‘ اس نے اچانک پوچھا:’’اور تمھارا فون نمبر کیا ہے؟‘‘
رئوف کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، میرے ہوش و حواس پھر جواب دینے لگے۔ اگر میرا راز کھل جاتا تو پرویز کے گھر والوں کو صدمہ پہنچتا۔ اس کے علاوہ کراچی میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ ویسے میرے کئی اور واقف کار تھے مگر میں ان میں سے کسی کے ہاں جانا نہیں چاہتا تھا ورنہ پھر حویلی تک خبر پہنچ جاتی اور پرویز کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سب سوچ کر میں نے رؤف سے کہا:’’ میں تمھیں خود ہی فون کر لوں گا اور ملنے بھی خود آجاؤں گا۔تم پی این ایس بابر جہاز پر ہو نا؟‘‘
وہ بولا:’’ اچھا،مگر تم مجھ سے اتنی راز داری کیوں برت رہے ہو؟‘‘
کیماڑی آگیا تو لانچ ڈرائیور نے رسی ریلنگ کی طرف اچھال دی۔ کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے رسی ریلنگ سے باندھ دی تاکہ لانچ بالکل کنارے سے لگ جائے اور مسافروں کو اترنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے رئوف کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کیے رہا ۔میں نے آپا ذکیہ کو سہارا دے کر اوپر پہنچایا۔ پھر باقی سب خودہی چلی گئیں۔ رئوف میرے اس رویے پر الجھن میں مبتلا تھا۔ بہر حال اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور کہا، میں اس کے ساتھ آفیسر کلب چل کر چائے پی لوں۔ میں نے بہانہ بنایاکہ میں جلدی میں ہوں۔
وہ بولا: ’’چلو ٹھیک ہے یوں ہی سہی۔ یہ بتاؤ کہ گاڑی کہاں کھڑی کی ہے۔ تمھیں تو نئی نئی گاڑیوں میں سوار ہونے کا بہت شوق ہے۔ آج کل کون سی رکھی ہوئی ہے؟‘‘
اس کے سوالات مسلسل مجھے مصیبت میں گرفتار کر رہے تھے۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب دیتا تو میری حیثیت کا راز کھل جاتا اور پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں نے اپنی بہنوں کے سامنے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ایک طرف لے گیا۔’’ میں چوں کہ ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے دو دن پہلے آیا تھا اس لیے گاڑی نہیں لایا۔‘‘
’’اوہ، تو پھر میں تمھیں نیوی کی وین میں چھوڑ دیتا ہوں۔‘‘ اس نے بے چینی سے کہا۔
’’ نہیں، نہیں میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا۔‘‘ میں نے کہا۔ اس پیارے اور پر خلوص دوست سے جان چھڑانا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔
’’ کیا کہہ رہے ہو دوست۔‘‘ اس نے مجھے حیرت سے یوں دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں: ’’چوہدری حشمت کا بیٹا ٹیکسی میں جائے گا۔‘‘
میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو پانچ نمبر کی بس میں بھی سیر کر چکا ہوں۔ زندگی حویلی میں رہنے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے اور قیمتی کپڑے پہننے کا نام ہی تو نہیں ہے۔ اس میں دکھ مصیبت ،پریشانیاں اور پانچ نمبر کی دھواں دیتی بس کا سفر بھی شامل ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے رونا چیخنا نہیں چاہیے۔صبرسے اس وقت کو گزارنا چا ہے۔
میں کسی بس میں سوار ہو کر اسے شک و شبہ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے نیول کیڈت بننا تھا اور ایسی ویسی حرکت سے وہ میری طرف سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نیوی کی وین میں بیٹھنے کو تیار ہو گیا مگر اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا اور میں جہاں چاہوں گا اتر جاؤں گا۔ اس نے ہامی بھری تو میں نے اس سے دو ہزار رپے مانگے۔
میں نے کہا:’’مجھے شاپنگ کرنا تھی۔ جلدی میں آیا تھا اس لیے زیادہ رقم نہیں لا سکا۔ لاہور جاتے ہی بھجوادوں گا۔‘‘
’’ ہاں، ہاں، ضرور میں ابھی آتا ہوں۔‘‘ اس نے کہا اور ایک طرف کو چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آفیسرز میس میں گیا ہے یا پھر کسی دوست کے پاس۔
وہ دس منٹ بعد وین میں واپس آیا۔ پھر اس نے دوسروں کی نظروں سے بچا کر مجھے دو ہزار رپے دے دیے۔ ہم سب وین پر سوار ہو گئے تو وہ کھڑا دیر تک مجھے دیکھتا اور ہاتھ ہلاتا رہا۔ میں نے ڈرائیور سے صدر تک چلنے کو کہا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ میری بہنیں بہت بے چین ہیں اور مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں لیکن ڈرائیور کی موجودگی میں جھجک رہی ہیں۔
وین صدر کے علاقے میں پہنچی تومیں ریگل سنیما کے پاس اتر گیا۔ جب دین آگے چلی گئی تو بہنوں نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ نیوی والا کون تھا؟ میں اس سے کیسے واقف ہوں؟ میں صدر میں کیوں اتر گیا، ہمارا گھر تو ریڈیو پاکستان کے سامنے ہے لہٰذا وہاں اترنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سوالوں کے جواب میں کہا کہ میں گھر چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔
حقیقت یہ تھی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا تھا۔ گھر پہنچنے میں جو وقت لگتا، میں اس عرصے میں کوئی کہانی گھڑنی چاہتا تھا۔ میں نے سب کو گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ درخشاں اندر جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کہا:’’ادھر آری۔‘‘
’’جی بھائی جان!‘‘ اس نے معصومیت سے کہا۔
’’میں ذرا ایک کام سے انصاری صاحب کے گھر جارہا ہوں۔ تم لوگ پریشان نہ ہونا۔‘‘
’’ پریشانی کی کیا بات ہے۔ انصاری صاحب حیدر آباد تھوڑی رہتے ہیں۔ تیسری گلی میںرہتے ہیں۔ آپ ذرا سی دیر میں واپس آجائیں گے۔ جاتو چکے ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ۔‘‘
’’ہا ں ،میں ابھی آیا۔‘‘ میں نے کہا اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تیسری گلی کی طرف چل پڑا۔ تیسری گلی میں تیز روشنی ہو رہی تھی، اس لیے کہ بجلی کے کھمبے کے علاوہ چند مکان والوں نے بھی سامنے کے رخ پر بلب لگوا رکھے تھے۔ میں نے ستائیسواں مکان گن کر دروازے پر دستک دی تو ایک ہونق آدمی نے دروازہ کھولا اور میری طرف دیکھ کر پلکیںجھپکائیں۔
’’جی ، فرمائیے۔‘‘
’’ وہ انصاری صاحب سے ملنا ہے۔‘‘ میں نے کہا۔
’’ پنساری؟ یہ تمہیں پنساری کی دکان نظر آرہی ہے؟‘‘ اس نے ناگواری سے کہا۔
’’ میں انھیں بیسی کے پیسے دینے آیا ہوں۔‘‘ میں نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اونچا سنتے ہیں۔
’’بیوی؟ کس کی بیوی؟‘‘ انھوں نے کان پر ہاتھ رکھ کر کہا۔’’یہاں تو بیوی ہے نہ بچے۔سب اللہ کو پیارے ہوگئے۔‘‘
’’تو پھر آپ کیوں بچ گئے؟‘‘ میں نے آہستہ سے کہا۔
’’بھئی ذرا زور سے بولو، مچھروں کی طرح کیا بھیں بھیں لگا رکھی ہے؟‘‘
میں نے ان کے کان کے قریب جاکر زور سے کہا: ’’انصاری۔۔۔ انصاری، میں ان سے ملناچاہتا ہوں۔‘‘
’’انصاری کا مکان اس طرف سے ستائیسواں ہے۔ مگر تم اتنی زور سے چیخ کیوں رہے ہو؟ کیا میں بہرہ ہوں؟‘‘
میں نے انھیں سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسری طرف ستائیس گن کر میں نے بند دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور انصاری صاحب کی صورت دکھائی دی۔ شاید مغرب کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر پہلے آئے تھے۔اس لیے کہ اب بھی تسبیح گھما رہے تھے۔
’’السلام علیکم انصاری صاحب! وہ میں بیسی کے پیسے دینے۔۔۔‘‘
’’وعلیکم میاں پرویز! اندر آجاؤ۔‘‘ انھوں نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا: ’’باہر کیوں کھڑے ہو۔‘‘
میں اندر چلا گیا۔ مختصر سا آنگن تھا جہاں ایک طرف مرغیوں کا ڈربا تھا اور دوسری طرف دو چارپائیاں پڑی تھیں۔ سامنے دو کمرے تھے اور دائیں طرف باورچی خانہ۔ آنگن میں تیز روشنی ہورہی تھی۔ میں ایک چار پائی پر بیٹھ گیا۔ انصاری صاحب سامنے بیٹھ گئے ۔میں نے رئوف سے لیے ہوئے دو ہزار رپے ان کی طرف بڑھائے اور معذرت کی کہ میں وقت پر انھیں پیسے نہ دے سکا۔
’’کوئی بات نہیں، اگر تم نے کسی کی مدد کرتے ہوئے دے دیے تھے تو اچھی بات ہے۔ کسی کا کام چل گیا، مشکل حل ہو گئی۔‘‘ وہ بولے۔ انھوں نے رپے رکھ لیے ،پھر باورچی خانے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے۔’’ارے اکبر کی ماں کہاں ہو، یہ پرویز آیا ہے۔ قریشی صاحب کالڑکا۔‘‘
کمرے سے ایک خاتون باہر آ گئیں۔ اور انھیں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ گھر والوں کی خیریت پوچھنے لگیں۔ پھر دو منٹ بعد انھوں نے باورچی خانے کی طرف منہ کر کے زور سے کہا۔’’ اری رضیہ۔۔۔ او رضیہ سنتی ہے۔‘‘
’’جی امی۔۔۔‘‘ باورچی خانے کی طرف سے آواز آئی۔
’’یہ پرویز آیا ہے۔ اس کے لیے ایک کپ چائے بنا کر لے آ۔‘‘
تھوڑی دیر بعد ایک دبلی پتلی لڑکی چائے کا پیالا لیے ہوئے نکلی اور اس نے نزدیک آکر پیالامجھے دے دیا۔ پھر دوسری چار پائی پر جاکر بیٹھ گئی اور دیدے گھما گھما کر میرا جائزہ لینے لگی۔
اس کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے جسم میں پیوست ہوتی معلوم ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی امی نے بھی شاید اندازہ کر لیا۔ انھوں نے کہا:
’’کیا دیکھ رہی ہے رضیہ یہ اپنا پرویز ہے۔‘‘
’’ نہیں امی! یہ پرویز نہیں ہیں۔‘‘ رضیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اور انصاری صاحب چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔
اور اب پرویز مستانہ کی زبانی سنیے۔
میں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اس لیے میں تیزی سے الٹے قدموں واپس آگیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر جو زف مسیح نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یقینا ماموں گلزار کو بھی بتا دے گا۔ پھر وہ دوڑ کر مجھے پکڑلیں گے۔
میں حویلی کی طرف جاتا تو ماموں مجھے دیکھ لیتے۔ اس لیے میں دائیں طرف جاکر ایک درخت کی آڑ میں ہوگیا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا ،اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد ماموں اور جوزف اس کو ٹھری سے کل آئے اور ماموں مجھے ڈھونڈ نے لگے۔
’’ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو وہ واقعی سلطان تھا؟ ‘‘انھوں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
’’ ہاں جی، چوہدری صاحب! چھوٹے سرکار تھے! ‘‘ اس نے کہا اور لکڑی کی ٹانگ گھسیٹتا ہوا نزدیک آگیا۔ میں نے اس کی دائیں کلائی پر زخم کا ایک لمبا سا نشان دیکھا تو میری حالت غیر ہونے لگی، وہ سلطان پر تین بار قاتلانہ حملے کر چکا تھا تو میری کیا حیثیت تھی۔ میں تو ویسے بھی اس کی نقل تھا۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا اور میری اصلیت ظاہر ہو جاتی تو میری پروا کون کرتا؟
وہ کچھ دیر تلاش کرتے رہے پھر یہ سوچ کر حویلی طرف چلے گئے کہ میں ادھرہی آیا ہوں گا۔ جوزف بڑبڑا تا ہوا اپنی کوٹھری میں واپس چلا گیا۔
میدان صاف پاکر میں درخت کی آڑ سے نکلا اور بے تحاشا حویلی کی طرف دوڑنے لگا۔ سامنے والے دروازے سے اندر جانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف ایک باتھ روم تھا جس کے قریب ہی سے ایک چکر دار زینہ بل کھاتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ میں گھومتا ہوا اور بل کھاتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے راہ داری طے کر کے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے دروازے کو لاک کر دیا اور بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔
میں نے سلطان احمد کی مصیبت کا حل دریافت کر لیا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کے ماموں اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے پیچھے کیوں پڑ گئے تھے۔
ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس کی دولت پر قبضہ کر لیں اور اس شان دار حویلی کے مالک بن جائیں۔ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ انھیں دوست دشمن اور اپنے پرائے کی تمیز نہ رہی تھی۔
مگرمیں یہ سب باتیں کیوں سوچ رہا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ ماموں اپنے بھانجے کی جان کے دشمن ہو گئے ہوں۔ یہ سب میرا واہمہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ سوال رہ رہ کر میرے دماغ میں چبھ رہا تھا کہ وہ گریس کا ڈبا، جوزف مسیح سے کیوں لے رہے تھے۔ صرف اس لیے کہ وہ اسے ضائع کر سکیں۔ یقینا جوزف نے ان کے کہنے پر ہی وہ گریس بہت صبح یا بہت رات کو زینے کے دو تین قدمچوں پر لگا دی ہوگی تاکہ میں جو گنگ کرنے کے لیے صبح اٹھوں تو میراپاؤں پھسل جائے اور میں گر کر ختم ہو جاؤں۔
سب جانتے تھے کہ سلطان احمد صبح دوڑ لگاتا ہے اور ورزش کرتا ہے۔ انھوں نے سلطان کے دھوکے میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا یا پھر وہ مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سلطان کی جگہ لے لی تھی اور حالات کو قابو میں کرنا چاہتا تھا۔
اب مجھے صرف ایک دو روز کی مہلت چاہیے تھی ،پھر میں اس سازش کو بے نقاب کر دیتا۔ میں نے سوچا امی نے درست کہا کہ مجھے سلطان کو تار دے کر بلا لینا چاہیے۔ ایک سے دوبھلے ہوتے ہیں۔
میں نے اپنا سانس درست کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنے کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر آگیا۔ اس وقت سہ پہر کے چار بج رہے تھے۔ میں نیچے اترا اور کار پورچ کی طرف گیا۔ وہاں شیورلیٹ کھڑی تھی۔ میں موٹر مکینک ہوں اس لیے ڈرائیونگ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ موٹرسائیکل چلانا تو میں نے سیکھ ہی لیا تھا اس لیے کہ مرمت کرنے کے بعد اسے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ مگر موٹر ڈرائیونگ شوق میں سیکھی تھی۔
مجھے دیکھ کر حمیدے گیٹ پر سے تیز تیز قدموں کے ساتھ آیا اور پوچھنے لگا:’’ کہاں جائیںگے باؤ جی؟‘‘
’’بس ذرا انار کلی تک جانا تھا۔‘‘
’’ مگر اس میں تو منجھلی سرکار کو کہیں جاناتھا۔‘‘
مجھے معلوم تھا کہ منجھلی سرکار کا مطلب ممانی ہے۔
’’ تو پھر؟‘‘
‘‘میں آپ کے لیے ڈاٹسن نکال کر لاتا ہوں۔‘‘
’’چابی مجھے دے دو۔ میں اکیلے جاؤں گا۔‘‘ میں نے کہا۔
’’عماد اوئے عماد، باؤ جی کو ڈاٹسن نکال کر دے گیراج سے۔‘‘ اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔
میرے لیے عماد بھی نیا نام تھا۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کی ذمے داریاں کیا ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا۔ جب گاڑی نہین آئی تو خودہی گیراج کی طرف چلا گیا۔ کیوں کہ حمیدے اپنی کوٹھری میں چلا گیا تھا۔ شاید یہ سوچ کر کہ عماد گاڑی لے آئے گا۔
میں گیراج میں پہنچا تو میں نے کار کی چابی اگنیشن میں لگی دیکھی مگر وہاں عماد نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے چلا گیا ہو۔
میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی اور گیٹ کی طرف موڑ دی۔ وہاں ایک آدمی گیٹ کھولتا نظر آیا۔ وہ پستہ قد اور موٹا سا تھا۔اس کا چہرہ چیچک زدہ تھا اور بال گھنگھریالے۔
مارکیٹ ایریا کے قریب پہنچ کر میں نے کار کو پارکنگ میں کھڑا کیا اور ایک جنرل اسٹور پر جاکر پہلے چیونگم کا ایک پیکٹ خریدا ،پھر تار گھر کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ معلوم ہوا کہ انار کلی کے قریب جانا پڑے گا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ انار کلی وہاں سے کافی دور تھی۔
ایک سنسان سڑک پر پہنچ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا پیچھا کیا جارہا ہے۔ میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا مگر پھر خیال آیا کیوں نہ اسے چیک کر لوں۔ وہ ایک سفید شیراڈ تھی جو میرے پیچھے فاصلہ دے کر آرہی تھی۔
میں نے اپنی کار سڑکوں پر بے مقصد گھمانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی میرے پیچھے ہے۔ میں نے سوچا جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ انار کلی کے قریب تار گھر میں جاکر میں نے فارم لیا اور باہر بیٹھے ہوئے ایک منشی سے اسے بھروایا اور تار بابو کی کھڑکی میں جاکر وہ فارم اسے تھما دیا۔ اس نے مجھ سے پیسے لینے کے بعد ایک مشین ’’گٹ گرگٹ گر رر‘‘ کی پھر مجھے رسید تھما دی۔
میں نے تار پر رحمت کی دکان کا پتا لکھوادیا تھا تاکہ جب سلطان وہاں کام کرنے آئے تو تار اسے مل جائے۔ مضمون کچھ اس قسم کا تھا۔
’’فوراً چلے آئوامی بہت پریشان ہے۔ تمہارا پرویز۔‘‘
میں تار گھر سے نکلا تو میری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی جب میں نے پارکنگ لاٹ میں سفید شیراڈ بھی کھڑی دیکھی۔ میں وہاں کچھ دیر کھڑا رہا اور میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اس آدمی کو تلاش کرنا چاہا جو میرے پیچھے وہاں تک آگیا تھا لیکن اس کا ڈرائیور کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میںاکتا کر گاڑی میں بیٹھ گیا ۔
اس وقت تقریباً ساڑھے چار بجے تھے۔ اس لیے سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ میں سست رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کیوں کہ میرے دماغ میں مسلسل ماموں گلزار کے متعلق خیالات آرہے تھے۔ وہ جوزف کی کوٹھری سے نکلنے کے بعد مجھے تلاش کر رہے تھے۔ مگر بعد میں جب کہ میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا ،انھوں نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آخر کیوں؟
کیا وہ مجھے چھوٹ دے رہے تھے یا پھر کسی خاص موقع کے منتظر تھے؟ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ میں ایک بہت بڑے راز سے آگاہ ہو گیا تھا اس لیے وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی موت کے بارے میں سوچ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑنے لگی۔ میں تو ایڈونچر کی تلاش میں لاہور آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں میری جان کے لالے پڑجائیں گے۔
وہ سڑک سیدھی اور سنسان تھی۔ اس وقت وہاں زیادہ ٹریفک نہیں تھا اس لیے میں نے رفتار تیز کر دی۔ تقریباً ایک میل چلنے کے بعد مجھے ایک بلی دکھائی دی جو بہت سست رفتاری سے سڑک پار کر رہی تھی میں نے اس بچانے کے لیے بریک لگا دیے۔ اس وقت میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب مجھے معلوم ہوا کہ کار کے بریک ڈھیلے ہیں اور میں کار کو نہیں روک سکتا۔
مجھے یقین تھا کہ بریک خود بہ خود ڈھیلے نہیں ہو سکتے۔ ڈھیلے کردیے گئے ہیں۔ میرے کسی دشمن نے میری جان لینے کے لیے بریک ڈھیلے کر دیے یا کرادیے تھے۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور اب میں کسی بھی لمحے ایک بڑے حادثے سے دو چار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔
سلطان احمد کی زبانی سنئے
’’ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ پرویز مستانہ نہیں ہے؟‘‘ انصاری صاحب نے حیرت سے اپنی بیٹی رضیہ سے سوال کیا۔
’’ناک، نقشہ اور خاص طور پر آنکھیں۔‘‘ رضیہ نے کہا۔
انصاری صاحب نے الجھن سے کہا:’’ ناک نقشہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ معلوم نہیں تم کیا کہ رہی ہو۔‘‘
’’ آنکھیں! ابو! کیا یہ آنکھیں آپ کو پرویز بھائی کی معلوم ہو رہی ہیں؟ یہ تو بالکل سپاٹ اور بے جان ہی ہیں۔ ہمارے لیے ان میں کوئی اپنائیت نہیں ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سپاٹ اور روکھا ہے۔ جیسے لکڑی کا بنا ہوا ہے۔۔۔ اور شوخی شرارت اور مسکراتی چمکتی آنکھیں۔۔۔ ان کی کوئی چیز بھی پرویز بھائی جیسی نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے ہم شکل ہیں۔‘‘
وہ لڑکی رضیہ بولے چلی جارہی تھی۔ اگر میں اس سے یہ کہتا کہ وہ ناک نقشے کا فرق بتاسکتی ہے تو یقینا وہ یہ بھی بتا دیتی، اس لیے کہ اس کی نگاہیں بہت تیز معلوم ہوتی تھیں۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کا اعتراف کر لوں۔ میں نے کہا:
’’ہاں میں پرویز مستانہ نہیں ہوں مگر میں کسی کو دھوکا نہیں دے رہا ہوں۔ پرویز کی مرضی سے میں نے اس کی جگہ لی ہے، ایک منصوبے کے تحت۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتاہوں کہ اس راز کو اپنے تک ہی رکھئے گا۔‘‘
میں وہاں سے چلنے لگا تو انصاری صاحب نے چائے پینے کے لیے روکنا چاہا لیکن میں نے شکریہ ادا کر کے معافی چاہ لی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر آیا تو ابا (قریشی صاحب) نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور ایک کاغذ دے کر کہا:
’’ڈاکیا آیا تھا۔ کہنے لگا، آپ کا تار آیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی کسی اور کا ہوگا۔ ہم غریبوں کو کون تار بھیجے گا۔ کہنے لگا رحمت کی دکان پر آیا تھا۔ دکان بند ہے، اس لیے میں نے مکان کا پتا پوچھ لیا اور یہاں چلا آیا۔ میں نے کہا میاں تم ہی پڑھ کر بتا دو۔ لو بھئی اس نے تار پڑھا:
’’امی کی طبیعت خراب ہے۔ جلدی سے چلے آؤ۔‘‘
’’و ہ تار کہاں ہے؟‘‘ میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ دن معلوم نہیں کیسا تھا۔ ہر لمحہ مجھے بے نقاب کرنے اور میرا راز کھولنے پر تلا ہوا تھا۔ اپنا راز کھلنے کی مجھے زیادہ پروا نہیں تھی۔ امی کی طبیعت کا حال سن کر دل بیٹھا جارہا تھا۔
قریشی صاحب نے کہا: ’’ڈاکیا تار دے کر جانے لگا تو میں نے کہا، یہ تو بتا کہ تار کس نے اور کہاں سے بھیجا ہے؟ تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا یہ تار لاہور سے پرویز نے بھیجا ہے۔اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آگئی۔ میں نے کہا ،میاں تمھارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پرویز تو یہاں بیٹھا ہے میرے پاس۔ لاہور جاکر تار کیسے دے سکتا ہے۔‘‘
میں نے تار کے کاغذ پر ٹائپ شدہ الفاظ پر ایک نظر ڈالی اور پھر ہلکے سے ہنس کر بولا:
’’ابا! محکمہ تار سے کوئی غلطی ہوگئی ہے۔ میں جا کر پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے؟‘‘
قریشی صاحب روکتے ہی رہ گئے مگر میں نے کپڑے بدلے اور باہر نکل آیا۔ بہنیں سمندر کی سیر کرنے کے بعد تھکی ہوئی تھیں، اس لیے کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ تار پڑھ کر میرے دل و دماغ میں بھونچال سا آگیا۔ میرے اور پرویز کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہم ٹھیک ایک سال بعد ریڈیو پاکستان کے پاس ملیں گے مگر اب وہ صرف دو ہفتے بعد مجھے لاہور بلا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چاہے کسی اور نے اسے پہچانا ہو یا نہیں ،امی نے اسے ضرور پہچان لیا ہے اور اسے ہدایت دی ہے کہ مجھے کراچی سے بلایا جائے۔
لیکن میں لاہور کیسے جاسکتا تھا؟ کاش کہ کوئی میرے پر لگا دیتا تو میں اڑ کر اس وقت وہاں چلا جاتا۔ میں یہ سوچ کر وہاں سے آیا تھا کہ کبھی پلٹ کر وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن دو ہفتوں کے بعد ہی یہ احساس ہوگیا کہ اپنوں سے دور رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ان کی یاد ہر لمحہ دل میں کسک پیدا کرتی رہتی ہے۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی صورتیں نگاہوں میںگھومتی رہتی ہیں۔
’’یا اللہ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟‘‘
دو گھنٹے پہلے جب رؤف سے اچانک ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس سے دو ہزار رپے لے لیے تھے۔ اب کس سے مانگوں؟ کس کے پاس جاؤں؟ خیال آیا کہ دوبارہ اس سے کہہ کردیکھوں، شاید کام بن جائے۔
میں نے دماغ پر زور ڈالا تو اس کا ٹیلے فون نمبر یاد آیا۔ میں نے ایک پی۔سی۔او جا کراس کا نمبر ڈائل کیا تو آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ رئوف سے رابطہ قائم کرا دے۔ پانچ منٹ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے اس سے اپنی مصیبت بیان کی تو وہ بہت حیران ہوا اور بولا:
’’اچانک لاہور جانے کی تمھیں کیا سوجھ گئی! ابھی تو تم سیر کرتے ہوئے ملے تھے؟‘‘
’’بس ایمرجنسی ہے دوست! کسی طرح سے میرے لیے کوئی بندو بست کرو۔‘‘میں نے کہا۔
’’ ایک ہی طریقہ ہے تم پی۔ آئی۔ اے کی نائٹ کوچ سے چلے جاؤ۔ ابھی کافی وقت ہے۔ تم ایر پورٹ پہنچ سکتے ہو۔ شعبہ ٹکٹ پر میرا ایک دوست ہے، وقار۔ اس سے بات کرنا۔ تمھیں اپنا ٹکٹ تیار ملے گا۔ ہم لوگوں کے لیے ہر جہاز پر چند سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں۔ وہ ان میں سے کوئی ایک تمھارے لیے بک کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟‘‘
’’ہاں شکریہ۔‘‘
’’لاہور پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کرنا۔ اچھا اللہ حافظ۔‘‘
’’اللہ حافظ‘‘ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔
کراچی ایر پورٹ پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ایک تیز رفتار ٹیکسی مل گئی، جس نے چالیس منٹ میں وہاں پہنچا دیا۔ شعبہ ٹکٹ میں وقار احمد نے مجھے ٹکٹ بنا کر دیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔
میں چاہتا تو اپنے بارے میں گھر والوں کو بتا کر آسکتا تھا مگر پھر ایک رونا پیٹنا مچ جاتا۔ ممکن ہے میری ساتوں بہنیں مجھ سے چمٹ جاتیں اور مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیتیں اس لیے میںدور سے انھیں الوداع کہہ کر چلا آیا۔
جب لاہور جانے والی نائٹ کوچ میں سوار ہو رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔’’ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ کھٹ۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔ گھر۔۔۔‘‘ جیسے کوئی شخص ٹانگ گھسیٹ کرچل رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک مسافر تھا جو اس طرح چل رہا تھا۔ غالبا ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ اس آواز کو سن کر پہلے تو میرا ذہن جھن جھنا گیا کہ یہی آواز سن کر مجھ پر بد حواسی طاری ہو گئی تھی اور میں لاہور سے بھاگ کر کراچی آگیا تھا۔ اب یہاں بھی وہی آواز پیچھا کر رہی تھی۔
وہ معقول سا آدمی تھا۔ جب میرے قریب سے گزر کر اس نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے زینے پر قدم رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی ہے۔
لکڑی کی ٹانگ۔۔۔ لکڑی کی ٹانگ۔۔۔ لکڑی کی ٹانگ، میرے دماغ میں جھماکے ہونے لگے۔ حویلی میں نیا جمعدار رکھا گیا تھا۔ اس کی بھی تو ایک ٹانگ لکڑی کی تھی اور وہ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا تھا۔ اس کی مونچھیں بھی راج پوتی انداز میں کناروں سے اٹھی ہوئی تھیں تو کیا اس رات وہ مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا؟
لیکن اسے مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ اسے مجھ سے دشمنی تھی یا اس نے کسی کے کہنے میں آکر ایسا کیا تھا؟ مجھے دوسرا خیال زیادہ صحیح معلوم ہوا۔
نائٹ کوچ نے رات بارہ بجے لاہور ایر پورٹ پر اتارا تو میں ایک ٹیکسی سے ہوٹل ہلٹن پہنچ گیا جو لارنس گارڈن کے قریب ہے۔ وہاں میرا ایک دوست کلرک ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرا دے دیا۔ میں نے رات وہاں گزاری اور صبح ہوتے ہی حویلی کی طرف چل پڑا۔ اس روزجمعہ تھا۔
جب میں ٹیکسی سے اتر کر حویلی میں داخل ہوا تو دربان علی حیدر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور آنکھیں مل کر کہا: ’’چھوٹے سرکار! ابھی تو آپ اندر تھے! اب باہر سے اندر آرہے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری آنکھوں کا قصور ہو اور مجھے سب چیزیں ایک جیسی نظر آرہی ہوں؟‘‘
’’ مجھ جیسا کوئی اندر ہے؟ کیا بک رہے ہو؟‘‘ میں نے حیرت ظاہر کی۔
’’جی ہاں سرکار! میں نے ابھی پانچ منٹ پہلے خود دیکھا ہے۔‘‘ اس نے کہا۔ ’’آپ ڈرائنگ روم میں جاکر دیکھ لیجئے۔ آج سب لوگ وہاں جمع ہیں۔‘‘
’’ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہاں کون چال باز لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔‘‘ میں نے کہا اور حویلی طرف بڑھنے لگا۔
اب پرویز مستانہ کی زبانی سنئے۔
میری آنکھیں بند ہو گئیں تو اسٹیرنگ خود بہ خود ہاتھوں سے چھوٹ گیا ۔کار یکایک بائیںطرف مڑگئی ۔پھر ایک ہول ناک دھماکا ہوا اور مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
کافی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ کار کو حادثہ پیش آچکا ہے۔ وہ ایک کھمبے سے ٹکرا کر رک گئی ہے۔ اس کا ونڈ اسکرین ٹوٹ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں زندہ تھا اور مجھے خراش تک نہیں آئی تھی۔
تھوڑی دیر تک میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ جب میرے ہاتھوں پیروں کی کپکپاہٹ دور ہوئی تو میں دروازہ کھول کر اتر آیا۔ اس کے اگلے حصے کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ دائیں طرف کی ہیڈ لائٹ چکنا چور ہوگئی ہے اور بونٹ چپک کر اٹھ گیا ہے۔ سامنے کی جالی ٹیڑھی
ہوگئی ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
وہ سنسان سڑک تھی، اس لیے وہاں لوگ جمع نہیں ہوئے تھے ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ پولیس عدالت اور کچری وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں وہاں سے پیدل چل پڑا۔ راستے میں خیال آیا کہ دو روز میں مجھ پر دو بار قاتلانہ حملہ ہوا ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بچ
گیا ہوں مگر ضروری تو نہیں کہ ہربار قسمت ساتھ دے۔
کار کے بریک اچانک فیل نہیں ہوئے تھے، انھیں کسی نے حویلی میں ڈھیلا کر دیا تھا یا پھر جب میں سلطان احمد کو تار دینے ٹیلے گراف آفس میں گیا ہوا تھا ،اس وقت کسی نے گڑ بڑ کی تھی۔ اس وقت مجھے وہ سفید کار یاد آئی جو میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اس میں سوار آدمی ہی نے مجھے نقصان پہنچایا تھا لیکن وہ کون ہو سکتا تھا۔
میں تو یہاں کسی سے واقف ہی نہیں تھا۔ ہر شخص، ہر جگہ اور ہر چیز میرے لیے اجنبی تھی۔ حویلی میں سوائے امی کے کون مجھ سے محبت کرتا تھا۔ شاید کوئی نہیں۔ اپنے محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کو تو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔
حویلی پہنچ کر میں سیدھا حمیدے کی کوٹھری میں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر شرما اور گھبرا کر بولا:’’ یہ آپ کہاں چلے آئے چھوٹے سرکار؟ کوئی کام تھا تو حویلی میں بلا لیا ہو تا۔‘‘
’’بیٹھو،میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔‘‘ میں نے ایک مونڈھے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔حمیدے سمٹا سمٹایا میرے سامنے بیٹھ گیا۔
’’یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ ممانی جان کار لے کر شاپنگ کے لیے جائیں گی اور مجھے ٹویوٹا استعمال کرنی ہوگی؟‘‘
’’ چوہدری گلزار صاحب نے۔‘‘ حمیدے نے جواب دیا۔
’’ مگروہ کار تو اب بھی پور ٹیکو میں کھڑی ہوئی ہے۔ ممانی کہیں نہیں گئیں۔‘‘
’’نہیں ابھی تو نہیں گئیں۔ ہو سکتا ہے پروگرام بدل گیا ہو۔‘‘ اس نے بے بسی سے کہا۔
’’یہاں کوئی سفید شیراڈ بھی تھی؟‘‘
’’جی ہاں شکور لایا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ کار لے گیا تھا۔‘‘
’’ اسے کس نے یہاں رکھا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے اور اب کہاں ملے گا؟‘‘
’’اسے بھی چوہدری صاحب نے رکھا ہے، گاڑیوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ ابھی نیا ہی آیا ہے۔ چوبرجی کے پاس رہتا ہے۔ مجھے اس کا گھر معلوم ہے۔ آپ حکم کریں تو میں اسے بلا کرلے آؤں؟‘‘
’’ہاں۔‘‘ میں نے سر ہلا کر کہا۔ پھر اسے بتایا کہ شکور نے میری کار کے بریک ڈھیلے کر دیے تھے جس کی وجہ سے میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ میری جان چلی جائے۔ وہ خود سے ایسا نہیں کر سکتا، کسی کے کہنے پر ہی اس نے ایسا کیا ہے۔
’’یہ تو آپ بڑی عجیب باتیں بتا رہے ہیں۔ یہاں آپ کا دشمن کون ہو گیا؟‘‘ حمیدے نے اپنائیت سے کہا۔
’’ میں نے اس کا پتا چلا لیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ۔۔۔‘‘ میں نے اسے قریب بلایا اور سرگوشی میں اپنا منصوبہ سمجھانے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شکور اور پھر جوزف مسیح کے ساتھ کیاسلوک کرنا ہے اور انھیں کس وقت میرے سامنے پیش کرتا ہے۔
حمیدے نے سر ہلایا:’’ میں سمجھ گیا جناب! آپ بے فکر رہیے۔‘‘
میں بے فکر ہو کر وہاں سے آنے لگا ،پھر مجھے خیال آیا تو میں نے کہا: ’’تم جاکر وہ کار لے آنا، کسی ٹرک میں ڈلوا کر۔‘‘
’’آپ بے فکر رہیے صاحب۔‘‘
میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کی چائے میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مطالعہ گاہ میں پی۔ پھر راحیلہ کے ساتھ کیرم کھیلنے بیٹھ گیا۔ میں تو کلبوں میں کھیل چکا تھا۔ اس لیے میری انگلیاں سیٹ تھیں، لیکن راحیلہ بھی کچھ کم نہیں تھی۔ چوتھے بورڈ میں اس نے مجھ پر گیم کر دیا۔ بہن کی جیت کا سب سے زیادہ مزہ فوزیہ نے لیا اور میرا منہ چڑا کر تالیاں بجائیں۔ ویسے وہ کھیل کے دوران مسلسل بولتی رہی تھی، اس لیے ہاتھ بہکتا رہا۔
رات کے کھانے کے بعد میں اوپر گیا اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر زور سے بند کیا جیسے میں وہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد میں دروازہ کھول کر نکل آیا اور امی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ابھی جاگ رہی تھیں۔ میں نے انھیں ساری باتیں بتا دیں۔ وہ مجھے گلے لگا کر سسکیاں لینے لگیں:
’’ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟‘‘ انھوں نے اپنے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا:
’’آپ میری سگی امی نہیں ہیں تو پھر مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟‘‘ میں نے کہا۔
’’سگی سوتیلی کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس ماں ہوں، اس لیے تجھ سے محبت کرتی ہوں۔‘‘
میں نے کہا: ’’آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ آپ مجھے امی جیسی لگتی ہیں۔‘‘
’’پھر تو مجھ سے وعدہ کر کہ تجھے یہاں رہنا پڑے گا۔‘‘
’’ مجھ سے کچھ محبت کرنے والے کراچی میں بھی ہیں۔ میں انھیں کیسے چھوڑ دوں؟‘‘
’’انہیںیہیں بلا لیں گے میرے بچے! میں نے سوچا ہے کہ سب لوگ ساتھ رہیں گے۔‘‘
پھر انھوں نے ایک حیرت انگیز اور دل چسپ کہانی سنائی:
’’ ایک ماں تھی جس کے دو بیٹے تھے۔ بالکل ایک جیسے۔ ان کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر ان میں سے ایک بچھڑ گیا۔ اب قسمت نے اسے اپنی ماں سے ملا دیا تھا۔ پرویز! تم جانتے ہو کہ ان دونوں بچوں کا کیا نام ہے؟‘‘
’’نہیں، نہیں تو۔‘‘ میں نے نیند بھری آواز میں کہا۔
’’ٹھیک ہے۔ میں کل بتاؤں گی۔‘‘ انھوں نے کہا۔ پھر سرہانے لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ ایک ملازم آیا تو انھوں نے اسے ہدایت دی کہ وہ چچا جان کو بلا کر لائے۔ تھوڑی دیر بعد چچاآگئے تو انھوں نے ان سے کہا کہ کل گھر کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں جمع ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔‘‘ وہ’’ بہتر ہے‘‘ کہہ کر سرہلاتے ہوئے چلے گئے۔
اس رات مجھے عجیب عجیب خواب آتے رہے۔
صبح ناشتے کے وقت سب لوگ موجود تھے، مگر ماموں گلزار کی صورت دکھائی نہیں دی۔ وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ چچی بجھی بجھی سی نظر آرہی تھیں۔ امی میرے سہارے سے نیچے آگئیں۔ ناشتے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہوگئے تو امی پر وقار انداز میں ایک شان دار صونے پر بیٹھ گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ گلزار ماموں تھوڑی دیر بعد آگئے۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے تھے۔
امی نے پر سکون لہجے میں کہا: ’’میں نے کل رات اپنے بچے کو ایک کہانی سنائی تھی، دو ہم شکل بچوں کی کہانی۔ اسے نیند آرہی تھی، اس لیے وہ کہانی ادھوری رہ گئی۔‘‘
’’آپا! آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں۔ دس سال بعد آپ نے پھر وہی کہانی چھیڑدی۔‘‘ ماموں گلزار نے منھ بنا کر کہا۔
’’ہاں، آپ شاید بھول گئیں کہ یہ طے پایا تھا کہ یہ کہانی سلطان کے سامنے نہیں سنائی جائے گی ورنہ اس کا دل دکھے گا، یہ رنجیدہ ہو جائے گا۔‘‘ ممانی نے کہا۔
’’مجھے وہ سب یاد ہے اور میں سلطان کے سامنے کہاں کچھ کہہ رہی ہوں۔‘‘
’’پھر؟ یہ کون ہیں؟‘‘ فوزیہ، راحیلہ اور احمد نے یک زبان ہو کر کہا۔
’’یہ سلطان نہیں پرویز ہے۔ سلطان کا چھوٹا بھائی۔ میرا بیٹا، جو آج سے دس سال پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا اور میں انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ یہ بات تم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی جدائی کے غم میں آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ میرے جگر کا دوسرا ٹکڑا سلطان میرے قریب نہ ہوتا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میری کیا حالت ہوتی۔ میں پاگل ہو جاتی یا پھر مر ہی جاتی۔‘‘
’’ مریں آپ کے دشمن۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟‘‘ ماموں نے کہا۔
’’ امی!‘‘ میں نے چیخ مار کرکہا اور ان سے لپٹ گیا۔ انھوں نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔
’’مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سلطان بھائی لگ رہے ہیں۔‘‘ فوزیہ نے کہا۔
’’ ممانی نے کہا:’’اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ یہ تو فلموں اور ڈراموں والی بات لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی فلمی کہانی سنا رہی ہیں۔‘‘
’’ حال آں کہ یہ حقیقت ہے اور کہانی بالکل سچی ہے۔‘‘
دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ سب نے چونک کر ادھر دیکھا ،پھر دیکھتے ہی رہ گئے کیوں کہ وہاں سے سلطان احمد داخل ہو رہے تھے، میرے بھائی۔
میں دوڑ کر ان سے لپٹ گیا: ’’بھائی جان!‘‘ میں نے روتے اور پھر ہنستے ہوئے کہا۔
’’ بھائی جان! کیا مطلب؟‘‘ سلطان نے حیرت سے کہا: ’’میں تمھارا بھائی کیسے ہوگیا؟‘‘
امی نے کہا: ’’یہ تمھارا بچھڑا ہوا بھائی ہے پرویز احمد جو آج سے دس سال پہلے جدا ہو گیا تھا۔ سلطان! یہ بات تم سے تمام بزرگوں نے چھپائی تھی تاکہ اس کے غم میں آنسو بہا بہا کر میری طرح تم بھی دیوانے نہ ہو جاؤ اور تمھارا دماغ نہ خراب ہو جائے۔‘‘
’’میرا بھائی پرویز۔‘‘ بھائی جان نے مجھے ایک بار پھر لپٹا لیا۔ اب ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ میں اتفاق سے اس وقت ان جیسے ہی کپڑے پہنے تھا۔ سیاہ پتلون اور سفید قمیص، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کا عکس لگ رہے تھے۔ ایسا عکس جو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے پر نظر آتا ہے۔
’’مگر بھائی جان! آپ کہاں چلے گئے تھے اور آپ کی جگہ یہ کیسے آگئے؟‘‘ فوزیہ نے پوچھا، وہ اب بھی الجھن کا شکار تھی کہ ہم میں سے اصل سلطان احمد کون ہے!
’’ یہاں جب حالات خراب ہوگئے اور کوئی میری زندگی کے پیچھے پڑ گیا تو میں کراچی چلا گیا۔ اس میں بھی قدرت کی طرف سے اچھائی تھی۔ مجھے اتفاق سے پرویز مل گیا۔ میں اس کی جگہ چلا گیا اور اسے میں نے یہاں بھیج دیا تاکہ یہ حالات سے نمٹ سکے۔‘‘
’’تمھاری زندگی کے پیچھے کون پڑ گیا خدا نخواستہ۔‘‘ ممانی نے چونک کر کہا۔
’’مجھ پر چار بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ دو بار تو میں نے کوئی توجہ نہیں کی مگر پھر میں چونک گیا۔ چوتھی بار ایک ایسا شخص میرے کمرے میں خنجر لے کر گھس آیا جو بہت تھوڑے عرصے پہلے ملازم ہوا تھا۔ میں گھبراہٹ میں اسے پہچان نہ سکا اس لیے حویلی سے بھاگ کر
کراچی چلا گیا۔‘‘ سلطان بھائی نے کہا۔
’’وہ کون تھا؟‘‘ چچی نے پوچھا۔
’’ جوزف مسیح اور اسے ماموں نے ایک مہینے پہلے ملازمت دی تھی۔ حال آں کہ وہ ہمارے برا چاہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔‘‘
’’یہ جھوٹ ہے۔ میں نے اسے ملازم نہیں رکھا۔ وہ ۔۔۔ وہ ایسے ہی یہاں آگیا ہوگا۔‘‘ ماموں نے غصے سے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے۔ ’’سلطان میاں! مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے تم کو شرم آنی چاہیے۔‘‘
’’ کاش کہ میں جوزف کو یہاں کسی طریقے سے لاسکتا۔‘‘ بھائی جان نے کہا۔
’’جوزف یہیں ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔‘‘ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا۔ پھر میں اس دروازے کی طرف گیا جو لان میں کھلتا تھا۔ میں نے اس دروازے کو کھول کر آواز دی:
’’جوزف! پیارے جوزف! اندر آجاؤ۔ اور زیادہ نہ تڑپاؤ۔‘‘
چند لمحوں بعد جوزف مسیح اپنی لکڑی کی ٹانگ سے آواز پیدا کرتا ہوا اندر آگیا۔ اس کے پیچھے ڈرائیور حمیدے تھا۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے نہ صرف یہ کہ جوزف کو تلاش کیا تھا بلکہ اس کی اچھی طرح سے ٹھکائی بھی کی تھی اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے اقرارجرم نہ کیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔
’’ دو ہفتے پہلے تم میرے سونے کے کمرے میں قاتلانہ حملے کے ارادے سے داخل ہوئے تھے۔ یہ صحیح ہے نا؟‘‘ بھائی جان نے سخت لہجے میں کہا۔
جوزف یہ سن کر رونے لگا۔
’’تمھارے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔‘‘ بھائی جان نے کہا: ’’گر ہم تمھاری زبان سے اقرار چاہتے ہیں۔‘‘
’’مجھے معاف کر دیجئے بی بی جی!‘‘ وہ آگے آکر امی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔
’’کیا سلطان صحیح کہہ رہا ہے؟‘‘ امی نے پوچھا۔
’’میرا سینہ ڈیوڈ کی حالت دیکھ کر پھٹ رہا تھا اور میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس موقع پر چوہدری صاحب نے کہا کہ اگر میں چھوٹے سرکار کو ختم کر دوں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ حویلی اور تمام دولت ہم لوگوں کے قبضے میں ہوگی۔
’’سن رہے ہو گلزار۔ اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟‘‘
’’یہ بکواس کر رہا ہے آپا۔‘‘ماموں گر جے۔
بھائی جان نے کہا:’’یہ صحیح کہہ رہا ہے ماموں جان! دس سال پہلے اس کے بھائی ڈیڈ مسیح نے انتقام میں اندھا ہو کر پرویز کو اس حویلی سے اغوا کر لیا اور کراچی چلا گیا تھا۔ پھر ابا جی نے جب اسے ایک مقدے میں جیل کی سیر کرا دی تو اس نے پرویز کو قریشی صاحب کے سپرد کر دیاجنھوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ ماموں نے اس کے بھائی جوزف کے جذبہ انتقام کو ابھارا اور مجھے ختم کرانے کی کوشش کی تاکہ ہماری جائیداد پر قابو پاسکیں۔‘‘
’’تو کیا جوزف کا کوئی بھائی بھی ہے کراچی میں؟‘‘ فوزیہ نے حیرت سے کہا۔
’’ہاں، وہ مجھے پرویز سمجھ کر التجا کر رہا تھا کہ میں اس کے گھر چلوں۔‘‘
’’بھائی کے انتقام میں اس نے ہی تم پر حملہ کیا ہوگا۔ مجھے تمھاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔‘‘ ماموں نے جھنجھلا کر کہا۔
میں نے کہا: ’’کہانی اس کے انتقام پر ختم نہیں ہوتی ماموں۔ میں نے جب بھائی جان کی جگہ لے لی تو آپ نے دھوکے میں میرا بھی قصہ ختم کرنا چاہا۔‘‘
’’ تم کیا بکواس کر رہے ہو پرویز میاں! ‘‘انھوں نے آنکھیں دکھا کر کہا۔
’’آپ نے اسی جوزف کے ذریعہ سے زینے پر گریس ملوا کر اسے پھسلواں بنوایا تاکہ میں اس پر سے پھسل کر اپنے ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھوں یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔‘‘
ماموں جان نے بے چینی سے پہلو بدلا اور بڑ بڑا کر رہ گئے۔
میں نے کہا:’’ کیا اس سلسلے میں بھی کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ میں جوزف کی کو ٹھری کی طرف گیا تھا تو میں نے آپ کو خود اس سے گریس کا ڈبا لیتے دیکھا تھا۔ وہ ڈبا آپ نے ہی اسے دیا ہو گا اور بعد میں واپس لے لیا ہو گا کہ کسی کی نظر اس ڈبے پر نہ پڑ جائے۔‘‘
’’میں تو جو زف کی کوٹھری میں اس کا حال پوچھنے گیا تھا کہ اتفاق سے اس نے گریس کا ڈبانکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کوئی یہ ڈبا اس کی کوٹھری میں رکھ کر چلا گیا ہے اور اسے سازش کے ذریعہ سے دوسروں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے ڈبالے لیا تاکہ اس معاملے کی تحقیق کرا سکوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ جموں نے بات بنائی مگران کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان سے بات بن نہیں رہی ہے۔
پھر آپ نے ایک ہفتہ پہلے شکور کو رکھا اور سب سے یہ کہا کہ اسے گاڑیوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جارہا ہے مگر اس کا اصل کام یہ تھا کہ وہ موقع ملنے پر میری کار کے بریک ڈھیلے کر دے تاکہ میں کار چلانے کے دوران حادثے کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے کل شام ایسا ہی کیا۔ اس وقت میں بھائی جان کو ٹیلے گرام دینے گیا تھا۔ اس نے میرا پیچھا کیا ،سفید شیراڈ پر۔ اس کے بعد ٹیلے گراف آفس پر میری کار کے بریک ڈھیلے کر دیے۔ میری کار بجلی کے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی مگر شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ ‘‘
’’یہ جھوٹ ہے۔ صرف الزام ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ شکور کو میں نے ملازم ضرور رکھا تھا، لیکن اس سے میں نے تمھاری کار کے بریک ڈھیلے کرنے کو نہیں کہا تھا۔‘‘ماموں نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ مار کر غصے سے کہا۔
حمیدے خاموشی سے ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ شکور کو جاکر بلا لائے۔ میری ہدایت کے مطابق وہ شکور کو تلاش کر کے حویلی میں لے آیا تھا اور اس نے چند کرارے ہاتھ اس کی کھوپڑی پر جڑکر اس سے جرم کا اعتراف کرا لیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد کشور،حمیدے کو ساتھ لے آیا اور اس نے روتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اس نے ماموں کے کہنے پر میری کار کے بریک ڈھیلے کیے تھے۔
ماموں کی حالت خراب ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ غصہ ہوتے رہے۔ پھر ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ رونے لگے۔ ممانی پھر فوزیہ اور پھر راحیلہ نے انھیں شرمندہ کیا۔ انھوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اس لیے انھوں نے ایسی غلط حرکت کر ڈالی۔ پھر انھوں نے امی کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔
امی بہت دیر تک خاموش رہیں جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پارہی ہوں۔
بھائی جان نے کہا:’’ صبح کا بھولااگر شام کو گھر آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ماموںاپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو آپ انھیں معاف کر دیں امی۔‘‘
’’ گلزار! ہو سکتا ہے کہ میں تمھیں معاف نہ کرتی اور کان پکڑ کر حویلی سے باہر نکال دیتی لیکن تمھاری اس خراب حرکت پر سلطان کراچی گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنے بھائی سے ہوگئی اور میری آنکھوں کا تارا اور جگر کا ٹکڑا میرے پاس آگیا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ میں سلطان کے کہنے پر تمھیں معاف کرتی ہوں۔‘‘ انھوں نے گہرا سانس لے کر کہاپھرماموں کو گلے لگا لیا۔
میرا خیال تھا کہ شکور اور جوزف کو پولیس کے حوالے کردیا جائے، لیکن بھائی جان نے مخالفت کی اور کہا کہ ان لوگوں نے ماموں کے بہکائے میں آکر ایسی حرکت کی تھی۔
۔۔۔۔۔
جب ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو بھائی جان نے کہا:
’’ اب تمھارا کیا ارادہ ہے؟ تم کیا کرو گے؟‘‘
’’ میں پڑھوں گا اور پھر بڑا آدمی بنوں گا۔‘‘
’’شاباش! مجھے تم سے یہی امید تھی۔‘‘
’’ میں باقاعدہ کسی اچھے سے اسکول میں داخلہ لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہنوں اور امی ابو کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں، لیکن انھوں نے اتنے عرصے میری پرورش کی اور مجھے اپنے ساتھ رکھا کہ وہ اپنے معلوم ہونے لگے ہیں۔ امی نے بھی ان لوگوں کو حویلی میں لانے کی اجازت دے دی ہے۔‘‘
’’ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے کراچی چلے جانا۔ میں ان لوگوں کے ٹکٹ منگوا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کل شام ہی تمھاری واپسی ہو جائے گی۔‘‘
’’آپ کا شکریہ۔‘‘ میں نے گرم جوشی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔
بھائی جان بولے: ’’ تمھاری خوشی، میری خوشی ہے پرویز! سدا خوش رہو۔ پھولو پھلو۔‘‘
میں دوسرے دن کی فلائٹ سے لاہور سے کراچی آگیا۔ جہاز میں بیٹھنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا اس لیے مجھے عجیب سا لگا۔
میں شام کو گھر پہنچا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے درو دیوار میرے انتظار میں بے تاب ہوں۔ میں دو ہفتوں کے لیے وہاں سے غیر حاضر رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں ان دو ہفتوں میں کیا ہوا ہو گا۔
میں گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے نگہت آرا کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ صحن میں چوکی پربیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔
’’بھائی جان؟ امی بھائی جان آگئے۔ بھائی جان! آپ کہاں چلے گئے تھے؟‘‘ اس نے کہا۔
’’ معاف کرنا، میں دو ہفتے پہلے لاہور چلا گیا تھا۔ وہ میرے بھائی جان مل گئے تھے نا۔۔۔ انھوں نے مجھ سے کہا۔۔۔ پھر وہ خود ہی لاہور پہنچ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک سانحہ کے تحت ہم دونوں بھائیوں کو۔۔۔‘‘
انھیں سنانے کے لیے میری زبان پر بہت سی دل چسپ اور حیرت انگیز کہانیاں مچل رہی تھیں۔ میں اس وقت بہت زیادہ جوش میں تھا اور جلد از جلد سب کچھ کہہ ڈالنا چاہتا تھا اس لیے گڑ بڑا گیا تھا۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔
’’دو ہفتے پہلے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟‘‘ نگہت آرا نے حیرت سے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے میری ناک پر کسی گینڈے کی طرح سینگ نکل آیاہو۔
اس کی چیخ و پکار سن کر پہلے آپا ذکیہ اندر سے نکل آئیں۔ انھوں نے مجھے دیکھ کر عادت کے مطابق ناک سکیٹری اور منھ ٹیڑھا کر کے بولیں: ’’رات کہاں رہ گیا تھا شہزادے؟‘‘
’’ کل رات؟ اوہ ہاں۔۔۔ کل رات۔‘‘ میں نے گڑ بڑا کر کہا۔ مجھے یاد آیا کہ میری جگہ بھائی جان میرا کردار ادا کر رہے تھے اور انھوں نے کسی کو میری غیر موجودگی کا شبہ نہیں ہونے دیا تھا۔
صورت حال دل چسپ اور بڑی حد تک سنگین ہو گئی تھی۔ پہلے بھائی جان یہ یقین دلا رہے تھے کہ وہ پرویز ہیں اور میں لاہور میں بیٹھا سب کو سلطان بن کر چکما دے رہا تھا، لیکن اب میں صحیح بات بتانا چاہتا تھا کہ میں دو ہفتوں سے غیر حاضر رہا تھا اور میری جگہ کوئی اور تھا۔
’’ ہاں کل رات کی بات ہے۔‘‘ آپا نے لہجہ بگاڑ کر کہا: ’’بتا تا کیوں نہیں کہاں گیا تھا؟ جب سے ٹنکی، مٹکے اور بالٹیاں خالی پڑی ہیں۔ گھر میں ایک بوند پانی کی نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ نل پرجاتے؟‘‘
میری تو سٹی گم ہو گئی۔ پانی نہ ہونے پران لوگوں کو واقعی مصیبت اٹھانی پڑی ہوگی۔
’’وہ میں گوہر کے ہاں چلا گیا تھا کیرم کھیلنے ،دیر ہو گئی تو اس کے ہاں سوگیا۔ بہر حال اب تم لوگ چلو۔ میں سب کو لینے آیا ہوں۔‘‘
’’ کہاں چلیں؟‘‘ اماں نے اندر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔
’’لاہور، اب ہم لاہور میں رہیں گے۔‘‘
’’ لاہور؟ ہاں لاہور ضرور چلیں گے۔ وہاں تو میں خوب سیر کروں گی۔ شالامار، مینار پاکستان، لارنس گارڈن، قذافی اسٹیڈیم۔‘‘ درخشاں نے تالیاں بجا کر کہا۔
’’دیوانی ہوگئی ہے نگوڑی! وہاں جا کر رہیں گے کہاں؟‘‘ عصمت آرانے اسے جھڑ کی دی۔
’’ ہم لوگ وہیں رہیں گے، ایک حویلی میں۔‘‘ میں نے کہا۔ پھر خاندان کے سب لوگوں کو جمع کر کے ساری کہانی سنائی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
’’ کب چلیں گے لاہور؟‘‘ درخشاں نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے بہت جلدی تھی۔
’’بس شام کو ہی۔‘‘
’’اور یہ سارا سامان کیسے جائے گا؟‘‘ ابا نے پوچھا۔
’’یہیں چھوڑ دیں یا کسی کو دے دیں۔ وہاں سامان کی کمی نہیں ہے۔‘‘ میں نے کہا۔
’’ نہیں بھئی نہیں، میں تو اپنا پان دان یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔‘‘ اماں نے کہا۔
’’ٹھیک ہے۔ سب ہلکا پھلکا سامان رکھ لیجئے۔ وہاں سب چیزیں مل جائیں گی۔ ہم لاہور میںکسی جنگل میں پڑائو ڈالنے نہیں جارہے ہیں۔‘‘
سب نے ہنگامی طور پر تیاری شروع کر دی۔ جن چیزوں سے انھیں برسوں سے وابستگی تھی وہ اچانک کیسے چھوڑ دیتیں؟ وہ چیزیں، وہ محلہ، وہ لوگ، سب ہی انھیں عزیز تھے۔ صبح جب محلے میں انھوں نے لوگوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے۔
دوسرے روز دوپہر کو جب ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر ائیر پورٹ جارہے تھے تو مجھے ٹیکسی کے شیشے میں انصاری صاحب اور رضیہ کا عکس دکھائی دیا۔ وہ ہمارے گھر کی طرف آرہے تھے۔ شاید انھیں ہماری روانگی کی خبر دیر سے ملی تھی۔ ہڑ بونگ میں مجھے ان لوگوں سے ملاقات کا خیال نہ رہا۔ اب اگر وہاں پانچ منٹ بھی رکتے تو دیر ہو جاتی۔
ٹیکسی کچھ اور آگے بڑھ گئی تو وہ دونوں آئینے میں چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرا کچھ پیچھے رہا جارہا ہے۔ کچھ کیا بہت کچھ بلکہ سب کچھ۔ میں نے اپنا بچپن وہاں گزارا تھا۔ ان گلیوں اور کھپریل کی چھتوں والے تمام مکانوں سے یادوں کی لمبی ڈوریں بندھی تھیں۔ اب جو میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا تھا تو مجھے رونا آرہا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہچکیوں کی آوازیں آئیں تو میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ سب ہی رو رہے تھے۔ ان گلی کوچوں سے شاید سب کے دل بندھے ہوئے تھے۔
ٹیکسی گلی طے کر کے سڑک پر آگئی اور ٹریفک میں شامل ہوگئی تو وہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اب ہم ایر پورٹ کی طرف جارہے تھے اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے والے تھے۔