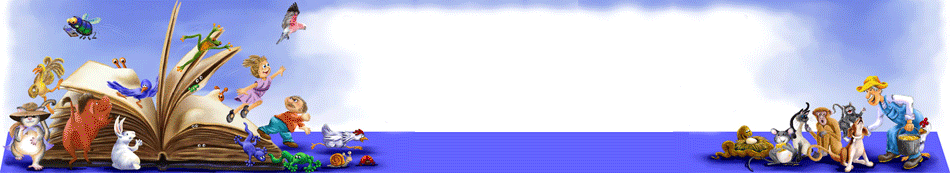سیما صدیقی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک تھا بادشاہ۔۔۔ اس کے دو بیٹے تھے ’’زریاب‘‘ اور ’’نایاب‘‘۔ زریاب…
فلیٹ نمبر ۳۱۲
سیما صدیقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وہ پارک کا نسبتاً تاریک گوشہ تھا۔ میں ٹہلتا ہوا وہاں پہنچا تو ٹھٹھک کر رہ گیا۔ وہ پھر وہاں موجود تھا۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ میں رکنے پر مجبور ہوگیا۔
’’میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟‘‘ میں نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا: ’’ ہاں بیٹھو!‘‘
اس کے انداز میں بے نیازی تھی اور لہجہ کچھ خشک سا تھا۔ میں وہاں بیٹھا تو وہ اپنی جگہ سمٹ سا گیا۔ مجھے خود پہ حیرت ہوئی کیوں کہ اجنبیوں سے بے تکلفی میرے مزاج کا حصہ نہ تھی۔ اسی اثناء میں پارک کے برقی قمقمے جل اٹھے۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ وہ چوڑے کندھوں والا ایک سخت گیر شخص تھا۔ اس نے جرسی پہنی ہوئی تھی اور اس کے کندھوں پر ایک سفری بیگ لٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں۔۔۔ ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے منفرد بنا رہا تھا۔ نہ معلوم وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا یا اس کی پتلیاں ساکن تھیں۔ میں کچھ الجھ سا گیا۔ اب وہ میری طرف متوجہ تھا۔ توبہ ہے اگر وہ جان لے کہ میں اس کے بارے میں کیا محسوس کررہا ہوں تو وہ کیا سوچے؟
’’آپ کہاں رہتے ہیں؟‘‘ میں نے نام پوچھنے کے بجاے رہائش سے متعلق سوال داغ دیا۔ جو میری گڑبڑاہٹ کا ثبوت تھا۔
’’یہیں! زیادہ دور نہیں۔‘‘ اس نے مختصر اور مبہم سا جواب دیا۔
’’آپ کا نام کیا ہے؟‘‘ اب میں نے الٹی گنتی شروع کی۔
’’شاذلے۔‘‘ اس نے پھر کم گوئی کا مظاہر ہ کیا، جواباً میرا نام تک نہ پوچھا۔
’’ میرا نام احسان ہے۔ ایک نجی کمپنی میں ملازم ہوں، پارک کے مرکزی دروازے سے جو سرمئی اپارٹمنٹ نظر آرہے ہیں، وہیں رہتا ہوں، تیسری منزل پر، فلیٹ نمبر ۳۱۲۔‘‘
میں نے ڈھیٹ بن کر اپنا مکمل تعارف پیش کیا۔
’’کیا چاہتے ہو؟‘‘ شاذلے نے ایسی رکھائی سے پوچھا کہ مجھے اس کی بداخلاقی اور اپنی بے وقوفی پہ غصہ آگیا۔
’’چاہنے سے کیا مرا د ہے؟ کیا دو انسان ایک دوسرے سے یونہی بات نہیں کرسکتے؟ ضروری ہے کہ کوئی مطلب ہو۔‘‘
’’مطلب نہیں تو کچھ مقصد تو ہوگا؟‘‘ اب کی اس نے منطق کی بات کی تو میں ذرا سنبھل گیا۔
’’ہاں بالکل! دراصل میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔‘‘ اس کا چہرہ کچھ ایسا سپاٹ اور بے تاثر رہا جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ لمحے توقف کے بعد بولا۔
’’تین ملاقاتوں سے پہلے میں کسی سے دوستی نہیں کرتا اور اگر دوست بنا لوں تو اسے اپنے گھر لے جائے بغیر نہیں رہتا۔‘‘
’’میں یہاں روز آتا ہوں۔‘‘ میں نے جلدی سے کہا۔ گویا میرا مطلب تھا کہ تین ملاقاتیں کچھ ایسی مشکل نہیں۔ اس کو خاموش دیکھ کر میں نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔
’’ایک دوسرے کے گھر جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔۔۔ میں سامنے ہی رہتا ہوں۔ میں نے انگلی سے اشارہ کرنا چاہا تو شاذلے نے قدرے درشتی سے میری بات کاٹ کر کہا۔
’’ٹھیک ہے، ٹھیک ہے! مجھے یاد ہوگیا، سرمئی اپارٹمنٹ، تیسری منزل ، فلیٹ نمبر ۳۱۲۔‘‘
’’ میرا مطلب تھا کہ آپ کسی دن آکے میرے فلیٹ پہ چاے پی سکتے ہیں۔‘‘
میری اس پیش کش پہ بھی وہ خاموش رہا تو میں نے جھینپ کر اپنا بے ربط انٹرویو پھر شروع کیا۔
’’آپ کام کیا کرتے ہیں؟‘‘ شاذلے نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا: ’’ریسرچ۔‘‘
’’ریسرچ۔۔۔! مگر کس چیز پر ریسرچ؟‘‘
شاذلے چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا ہو پھر بولا: ’’ یہ میں دوستی کے بعد بتاؤں گا، اگر ہوئی تو!‘‘
یہ کہہ کر وہ اچانک ہی کھڑا ہوگیا اور خدا حافظ کہے بغیر ہی چل پڑا۔ اس کی چال بھی مجھے کچھ عجیب سی لگی، گویا وہ قدم اٹھا کر نہ چل رہا ہو، بلکہ اس کے پیروں تلے اسپرنگ یا پہیے لگے ہوں۔ وہ کچھ اچھلتا ۔کچھ پھسلتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہوگیا۔
*۔۔۔*
کیا شاذلے کوئی ’’پراسرار ہستی‘‘ ہے؟ میں نے کروٹ بدل کر پھر سوچا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ضرور یہ میرا وہم تھا، اگر وہ چلنے کے بجاے، اچھل یا پھسل رہا ہوتا تو میرے علاوہ اور لوگ بھی تو نوٹ کرتے۔ شاید میں جاسوسی ناول زیادہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے تکیہ منھ پر رکھ کر سونے کی کوشش کی مگر ذہن وہیں اٹکا رہا۔ اس کی آواز اتنی پھنسی پھنسی کیوں تھی۔ جیسے منھ کے بجاے ناک سے بول رہا ہو! آخر اس کی شخصیت میں کون سی ایسی کشش یا خوبی ہے؟ بظاہر تو وہ ایک اکھڑ ا اور بدمزاج سا آدمی ہے۔ میں اس سے دوبارہ کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ کیا کل وہ وہاں آئے گا؟ کیا وہ بھی مجھ سے ملنا چاہے گا؟۔۔۔ اف۔۔۔ بھاڑ میں جائے، وہ اور اس کی دوستی۔ میں نے اوڑھی ہوئی چادر کو دور پھینکا اور چاے بنانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کیا۔ سوچ سوچ کر سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں اکیلا ہی اس فلیٹ میں رہتا تھا۔ والدین دوسرے شہر میں تھے۔ ملازمت کی خاطر آدمی کو گھر بار چھوڑ کر کہاں کہاں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ماں باپ کو تسلی دے رکھی تھی کہ میں جلد ہی تبادلہ کرا لوں گا۔ میرے دوست احباب بہت کم تھے۔ پڑوسیوں سے بھی زیادہ مراسم نہ تھے۔ مجموعی طور پر میں ایک لیے دیے رہنے والا، کم گو شخص تھا اور اسی بات پہ مجھے خود حیرت تھی کہ ’’ میں ‘‘ اور پارک میں ملنے والے ایک ’’اجنبی‘‘ کے گلے پڑ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی کرلے۔
*۔۔۔*
یہ ’’شاذلے‘‘ سے میری تیسری ملاقات تھی۔ آج فیصلہ ہونا تھا کہ وہ مجھے دوستی کے قابل سمجھتا ہے یا نہیں؟ ان تین ملاقاتوں میں شاذلے کے مزاج کی خشکی قدرے کم ہوئی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ مجھے دوست بنالے گا مگر ذہن وسوسوں کا شکار تھا۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے اور بے تکلفانہ فضا پیدا کرنے کے لیے میں کینٹین سے ’’چھولوں‘‘ کی دو پلیٹیں لے آیا۔ ایک میں نے شاذلے کو پکڑائی اور دوسری کو ہاتھ میں لے کر چنوں اور پھلکیوں کو چمچے سے الٹنے پلٹنے لگا۔ جیسے پلیٹ میں ہاکی کھیل رہا ہوں۔ شاذلے کی جانب دیکھا تو وہ تقریباً بت بنا چاٹ کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا: ’’ارے دیکھ کیا رہے ہو، کھاؤ نا یار!‘‘
’’یار‘‘ کہہ کر میں نے دانستہ اسے یہ تاثر دیا کہ میں اسے دوست بنا چکا ہوں گو دوستوں کو یار کہنے پہ میری والدہ کافی خفا ہوتی تھیں۔ شاذلے نے میرے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے پلیٹ ایک طرف رکھی اور بولا: ’’تم نے پہلی ملاقات میں پوچھا تھا ناں کہ میں کہاں رہتا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟‘‘
’’ہاں! پوچھا تو تھا۔‘‘ میں نے چاٹ سے بھرا چمچہ منھ میں ڈالا۔
’’تو سنو! میں آیا ہوں مریخ سے!!‘‘
’’کیا!‘‘ چھولوں کی پلیٹ میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔
’’تم ۔۔۔ مم۔۔۔ مذاق کررہے ہو!‘‘ میں ہکلایا۔
’’نہیں۔۔۔ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟مریخ میں کوئی کسی سے مذاق یا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، وہ ایک سنجیدہ سیارہ ہے۔‘‘
میں گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا لیکن قدم گھاس کی چادر میں کچھ دھنس سے گئے۔
’’بیٹھو میرے دوست!‘‘ شاذلے نے پہلی بار مجھے دوست کہا مگر اب میں اس سے دور۔۔۔ بہت دور بھاگنا چاہتا تھا۔
’’میں نے کہا ناں۔۔۔ بیٹھ جاؤ۔‘‘ شاذلے کے لہجے میں اب تحکم سا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔ اس کا ہاتھ بالکل سرد تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اب بھاگنا بھی چاہتا تو نہیں بھاگ سکتا تھا۔
’’دیکھو! ڈرو نہیں۔‘‘ شاذلے کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی نرمی محسوس ہوئی۔
’’تم نے پوچھا تھا ناں کہ میں کس چیز پر ریسرچ (تحقیق) کررہا ہوں؟ تو سنو ! میں ’’انسان‘‘ پہ تحقیق کررہا ہوں۔ جیسے تم نوٹس بنانے کے لیے گھنٹوں لائبریری میں بیٹھتے ہو۔ تو کبھی کوئی کتاب ایشو(جاری) کرا کے گھر لے جاتے ہو۔ اسی طرح میں اپنی سہولت کے لیے تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔۔۔ تم تیار ہو؟‘‘
’’میں۔۔۔ نن۔۔۔ نہیں۔۔۔ بالکل نہیں!‘‘ میں ٹھیک طرح بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، خواتین باتوں میں مگن تھیں اور کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ تھا۔
’’ میں نے بتایا تھا ناں کہ جس کو دوست بنا لوں اسے گھر کے جائے بغیر نہیں رہتا۔ جلدی واپس چھوڑ جاؤں گا۔ آؤ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو اور دیکھو! میں ’’نہ‘‘ سننے کا عادی نہیں۔‘‘ شاذلے کا لہجہ دھمکی آمیز ہوگیا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا مگر میں کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ہم پارک سے باہر نکل آئے۔ سرمئی فلیٹ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ کوئی غیر مرئی طاقت مجھے کھینچ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی کار بغیر ڈرائیور کے خودبخود چلتے دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں پھر قریب پہنچ کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ آگے والی گاڑی، اسے رسی کی مدد سے گھسیٹ رہی ہے۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔ شاید میں بے ہوش ہو کر سڑک پر گرنے والا تھا۔
*۔۔۔*
آنکھ کھلی تو مجھے کچھ سردی کا احساس ہوا۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈ بڑھتی گئی۔ میں نے اپنے پاؤں سکیڑ لیے، کچھ لمحے یونہی پڑا رہا۔ ذہن کام نہیں کررہا تھا کہ میں کہاں ہوں؟ اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اٹھنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا سا گیا۔ موسم اتنا سرد تھا کہ ہاتھ پاؤں اکڑ سے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کسی فریج میں اکڑوں بیٹھا ہوں۔
’’اٹھ گئے؟‘‘ شاذلے کی آوا زپہچان کر میں نے مڑ کر دیکھا۔ آواز وہی تھی مگر شخصیت اور حلیہ بدل چکا تھا ۔ وہ سرخ تنی ہوئی جلد، چوڑے کندھوں، سرخی مائل آنکھوں اور سپاٹ چہرے والا طویل قامت روبوٹ لگ رہا تھا۔ جس نے سرخ لبادہ پہنا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کے درمیان سرخ سی روشنی کسی ’’نائٹ بلب‘‘ کی طرح جل بجھ رہی تھی۔
’’تم شاذلے ہو؟‘‘ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔
’’ہاں !‘‘ اس نے حسب عادت مختصر جواب دیا۔
’’آج بہت سردی ہے۔‘‘ میں نے دونوں مٹھیوں کو بغل میں دباتے ہوئے کہا۔
’’ہاں! درجہ حرارت تقریباً منفی ۸۰ ہے۔‘‘
’’کیا!‘‘ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔
’’ہاں! مریخ کا درجہ حرارت عموماً اتنا ہی رہتا ہے۔‘‘
’’ کیا! ‘‘ میں دھک سے رہ گیا۔ ’’ کیا تم مجھے مریخ لے آئے، میں تو مرجاؤں گا ٹھنڈ سے۔‘‘ میں تقریباً ر و دینے کو تھا اور میرے دانت بجنا شروع ہو گئے تھے۔
’’ نہیں! ابھی ’’ہاٹ ڈرنک‘‘ پی لو گے تو سردی بھاگ جائے گی۔ یہاں آکسیجن محض اعشاریہ ایک پانچ فیصد ہے لہٰذا تمہارے لیے آکسیجن سیلنڈر اور ماسک ’’زمین‘‘ سے منگوا لیے گئے ہیں۔‘‘
شاذلے نے ٹیڑھے سے گلاس میں جو کچھ دیا وہ مشروب ہر گز نہ تھا، گولہ گنڈا قسم کی پسی ہوئی رنگین برف تھی۔ میں نے ہمت کرکے اسے منھ میں ڈال لیا۔ حیرت انگیز طور پر ٹھنڈ کا اثر کم ہونے لگا۔ جونہی میری طبیعت بحال ہوئی ہم اس غار نما مکان سے نکل آئے۔ باہر سرخ مٹی کے طوفانی جھکڑ چل رہے تھے۔ پورا سیارہ سرخ مٹی (Fezzous) سے بھرا پڑا تھا۔ شاذلے نے مجھے بھی ایک لبادہ اوڑھا دیا اور چشمہ پہنا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں چل بھی نہیں پارہا، پاؤں جم نہیں رہے تھے۔ شاذلے نے بتایا کہ یہاں ’’کشش ثقل‘‘ زمین کے مقابلے میں صرف ایک تہائی ہے۔ یعنی ہم مریخ پہ اچھلیں گے تو زمین سے تین گنا زیادہ اوپر جائیں گے۔ ہم خرگوشوں کی طرح اچھل اچھل کر چل رہے تھے۔ کچھ آگے گئے تو پہاڑ اور برف کے بڑے بڑے تودے نظر آئے۔ شاذلے بولا۔
’’ہمارے ہاں پانی صرف اعشاریہ صفر تین فیصد ہے۔ ہم اسی برف سے کام چلا رہے ہیں۔‘‘ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد آخر میں نے تھک کر پوچھا۔
’’تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟‘‘
’’تجربہ گاہ۔‘‘ شاذلے نے پھر تفصیلی جواب سے گریز کیا۔ مجبوراً مجھے پوچھنا پڑا: ’’مگر کس لیے۔۔۔؟‘‘
’’تمہارا دماغ کھول کر۔۔۔ کچھ نوٹس بنانے ہیں۔‘‘ اس کے لہجے کا کھردرا پن لوٹ آیا۔
’’کیا!!‘‘ میں گرتے گرتے بچا۔ ’’تم یہ نہیں کرسکتے!‘‘ میں نے کمزور سے لہجے میں دھمکی دی۔
’’کیوں؟‘‘ اس نے سادگی سے پوچھا۔
’’دیکھو مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔‘‘ میرا لہجہ اب التجائیہ ہوگیا۔
شاذلے نے ٹھنڈی سانس لی۔ (وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ہی سانس لے رہا تھا) پھر بولا۔
’’دیکھو! احسان!‘‘ اس نے پہلی بار میرا نام لیا۔ ’’اگر ہم تمہارے آنے سے فائدہ اٹھائیں گے تو تم بھی اٹھاؤ۔ گھومو پھرو، یہاں کے بارے میں جانو۔ ہمارا سال تقریبا 687 دن کا ہوتا ہے، ہمارا حساب کتاب کچھ الگ ہے مگر میرا وعدہ ہے کہ تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ ہاں! مگر یاد رکھو! واپس جا کر تم یہاں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروگے۔‘‘ (اور ’’ساتھی‘‘ کے لیے کہانی تو بالکل نہیں لکھوگے)
’’مگر یہاں دیکھنے کے لیے ہے کیا، سواے سرخ ریت اور سفید برف کے؟‘‘
’’کیوں نہیں ہے، ہماری بیرونی سطح بنجر اور ویران لگتی ہے مگر اندر اسکول، کارخانے، بازار، ہسپتال اور تفریح گاہیں، سب کچھ ہیں، دراصل ہماری ’’اڑن طشتری‘‘ قدرے ویران علاقے میں اتری تھی۔ مگر دیکھو! کہیں کے بارے میں جاننا ہو تو وہاں کی زبان سیکھنا ضروری ہے، جیسے میں نے سیکھی۔‘‘ شاذلے نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔
’’میں اتنا لمبا عرصہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔‘‘ میں نے گھبرا کر کہا۔ ’’ویسے بھی میں کبھی اچھا طالب علم نہیں رہا، پڑھنے لکھنے سے گھبراتا ہوں۔‘‘ میں نے سوچا کہ جب وہ میرا دماغ کھولیں گے تو یہ خود ہی پتہ چل جائے گا لہٰذا بتانے میں کوئی ہرج نہیں۔
’’چلو!! تو میں تمہیں ’’اسکول‘‘ کے دورے پہ ہی لے جاتا ہوں، مریخی اصول یہ ہے کہ جو بات منع کی جائے وہ پہلے کرتے ہیں۔‘‘
کچھ دور چلنے کے بعد ایک سرخ ٹیلا نظر آیا جس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ جس سے ہم اندر گھسے۔ یہ ایک ’’اسکول‘‘ تھا۔ عمارت کافی گرم تھی، شاید ہیٹر چل رہے تھے۔ شاذلے نے بتایا کہ ہم حکمرانوں سے زیادہ اپنے بچوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں کیوں کہ یہ ہی مریخ کا مستقبل ہیں۔ مریخی بچے بھی کافی بڑے تھے۔ چہروں پہ ذرا معصومیت نہ تھی۔ عجیب بات یہ کہ سارے بچے ’’گنجے‘‘ تھے۔ ان کے سر لمبوترے اور ساخت انڈوں کے چھلکوں کی طرح تھی۔ کندھوں پہ اینٹینا لگے تھے۔ یہ طالب علم کرسی نما نشستوں پہ بیٹھے تھے اور سامنے پروجیکٹر نما قسم کی چیز رکھی تھی، جس پہ کوئی پروگرام چل رہا تھا۔
’’استاد کہاں ہے؟‘‘ میں نے مڑ کر شاذلے سے پوچھا۔
’’یہاں استاد نہیں ہوتے، جو سکھانا ہو، کمپیوٹر میں فیڈ کر دیاجاتا ہے۔‘‘
’’ہائیں!! مگر کیا کتابی علم کے علاوہ انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ مثلاً اخلاقیات، اٹھنا بیٹھنا، تمیز تہذیب، ہمارے ہاں تو بچوں کو۔۔۔‘‘
’’ہاں۔۔۔ ہاں۔۔۔ ٹھیک ہے۔‘‘ شاذلے نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹی اور بولا: ’’دیکھے ہیں بچے میں نے، پارک میں ایک دوسرے سے ’’ابے تبے‘‘ کرکے بات کرتے، مذاق مذاق میں گالیاں دیتے اور شوقیہ سگریٹ پیتے۔۔۔‘‘
’’سب بچے ایسے نہیں ہوتے۔‘‘ میں نے زمینی بچوں کا کمزور سا دفاع کیا۔
پھر اخلاقاً ایک مریخی بچے کے گنجے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا مگر وہ جانے کیا سمجھا، مجھے گھور کر دیکھا اور سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈر ہوا کہ کہیں مار نہ بیٹھے، میں فوراً پلٹا۔ شاذلے نے بچے کو اپنی زبان میں کچھ سمجھایا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔
’’بچہ ہے نا۔۔۔ ڈر گیا تم سے۔‘‘
’’ہائیں! ڈر گیا!‘‘ یہ لمبا چوڑا، خوفناک ’’مشینی بچہ‘‘ اور مجھ سے ڈر گیا؟ میں نے دل میں سوچا، پھر شاذلے سے پوچھا: ’’آخر میری کس بات سے ڈر گیا؟‘‘
’’اجنبیت سے۔۔۔ ہمارے بچے اجنبیوں سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبان سیکھو، نہیں سیکھو گے تو ان سے گھلو ملو گے کیسے؟‘‘ شاذلے نے پھر وہی مشورہ دیا تو میں نے دل میں سوچا۔ ایسے سخت پتھریلے بچوں کے ساتھ ، میں گھل مل کر کروں گا بھی کیا؟
اسی اثناء میں چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاذلے میرا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم سے باہر نکلا لیکن پھر کنارے ہو گیا کیونکہ جس سوراخ سے ہمیں باہر نکلنا تھا، وہاں سے بچوں کے والدین اندر آنے لگے۔ وہ انہیں لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مائیں بھی تقریباً باپوں جیسی ہی تھیں۔ وہی قدو قامت، وہی لباس، وہی سپاٹ اور بے تاثر چہرے، بس فرق یہ تھا کہ ان کے بال، مردوں سے لمبے تھے اور انہوں نے اسے جوڑے کی شکل میں کس کے باندھ رکھا تھا۔
بچے قطار بنائے باہر آنے لگے۔ ماں باپ دیوار سے ٹیک لگائے، خاموش اور مودب کھڑے تھے۔ جس کا بچہ آتا وہ اس کی انگلی پکڑ کر سوراخ سے باہر نکل جاتا۔ اچانک ایک بچہ قطار توڑ کر درمیان سے نکلا اور دوڑ کر ایک عورت سے لپٹ گیا۔ اس نے چٹاخ سے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بازو سے پکڑ کر اسے دوبارہ لائن میں کھڑ ا کردیا۔ میں نے شاذلے کی طرف دیکھا تو اس نے میری نظروں کا سوال پڑھ لیا، کہنے لگا۔
’’ماں ہے۔۔۔ بچے کی۔‘‘
میں نے کہا: ’’سگی؟‘‘
کہنے لگا: ’’ہاں! سگی ہی تو ہے، تب ہی تو مارا ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بااصول اور مہذب مریخی بنے نہ کہ بے اصول اور بدتہذیب۔‘‘
اسکول سے باہر آئے تو میں نے شاذلے سے کہا: ’’مجھے سخت بھوک لگی ہے، کیوں نہ کسی ہوٹل میں چلیں، لنچ کے لیے۔‘‘
’’ہمارے ہاں پانی ’’نایاب‘‘ ہے اس لیے ’’اناج‘‘ اگانے اور ’’کھانے‘‘ پکانے کا لمبا چکر نہیں۔ نہ مویشی ہیں، نہ پھل سبزی۔ بس خوراک کی گولیاں دستیاب ہیں، جتنی چاہیں مفت کھا سکتے ہیں۔ ڈنر اور لنچ کا یہاں کوئی تصور نہیں، نہ ہم تم لوگوں کی طرح کھانا پکانے اور کھانے میں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔‘‘ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس میں سے ’’بنٹی‘‘ کی شکل کی رنگ برنگی گولیاں نکال کر میری ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ اب معلوم نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا یا میرے بھوک بھوک کا شور مچانے پہ مجھے گولی دے رہا تھا۔ میں نے گولی منھ میں ڈالی تو عجیب پھیکی اور بے ذائقہ محسوس ہوئی۔
’’آہ!‘‘ میرے منھ سے بے ساختہ آہ نکل گئی۔ دل میں سوچا۔ کہاں وہ قیمہ، پراٹھا اور نان اور کہاں یہ ’’کھانے‘‘ کا روکھا پھیکا انتظام! جب میں اماں کے پاس تھا تو کھانے پینے میں خوب نخرے کرتا تھا۔ آج ’’ٹینڈے‘‘ کیوں پکا دیئے؟ شوربہ پتلا کیوں ہے، چاول گیلے کیوں ہیں؟ واقعی انسان کو جو نعمت حاصل ہو، اس کی قدر نہیں کرتا۔ بے شک وہ بہت ناشکرا ہے۔
’’گولیاں کھا کر مجھے ’’انرجی‘‘ سی محسوس ہوئی۔ اب ہمارا رخ ’’مریخی ہسپتال‘‘ کی جانب تھا۔ وہاں دور دور تک ڈاکٹروں کا نام و نشان نہ تھا۔ مریخی مریض البتہ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شاذلے نے میری متلاشی نگاہوں کا مقصد بھانپ لیا اور بولا: ’’یہاں استاد کی طرح ڈاکٹر بھی موقع پہ موجود نہیں ہوتے، وہ اپنی رہائش گاہوں سے خود کار سٹیلائٹ سسٹم کی مدد سے علاج کرتے ہیں۔ مریض اپنا آپریشن خود کرتے ہیں، سرجن صرف ہدایات دیتے ہیں۔ مریخ میں کرنسی(افراط زر) کا کوئی چکر نہیں، علاج تعلیم ہر چیز مفت ہے۔‘‘ میں نے شاذلے سے کچھ جلن سی محسوس کی اور ہسپتال کا دوبارہ جائزہ لینے لگا کہ کوئی خامی نکال سکوں۔ سامنے فرج کی طرح الماریاں رکھی تھیں۔ ایک کو کھولا کہ شاید مریخی پھل فروٹ رکھے ہوں مگر دھک سے رہ گیا۔ اس میں لمبے لمبے بازو، پیلی پیلی ناکیں، کرکرے کان اور لجلجے دماغ رکھے تھے۔
’’یہ۔۔۔ یہ کیا ہے؟‘‘ میں نے گڑبڑا کر فرج بند کردیا۔
’’یہ اسپیئر پارٹس (فالتو پرزے) ہیں ہمارے۔ اگر بازو میں درد ہو تو اسے ٹھیک کرنے کے بجاے بدل دیا جاتا ہے۔‘‘
’’اچھا!!‘‘ میں نے تھوک نگلا۔ ’’ میرے خیال میں یہاں سے چلتے ہیں، مجھے کچھ متلی سی محسوس ہورہی ہے۔‘‘
شاذلے نے مہربانی کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر آگیا۔ تھوڑی دیر ٹہلنے سے میری طبیعت بحال ہو گئی۔ اب شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پہ دو چاند نظر آرہے تھے۔ مگر یہ چاند گول نہ تھے، لگتا تھا بڑے بڑے چمک دار پتھر ہیں۔ میں نے پہلے چاند کو اور پھر شاذلے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ قدرے فخریہ لہجے میں بولا۔
’’ہاں! ہمارے ہاں ایک نہیں دو چاند ہوتے ہیں۔‘‘
میں نے شاذلے کی حس مزاح کو پرکھنے کے لیے ازراہ مذاق کہا۔
’’اور اب تو تین ہو گئے، میں بھی تو یہاں آگیا ہوں۔۔۔ ہاہا۔۔۔ کیا خیال ہے؟‘‘
شاذلے نے مجھے گھورا۔۔۔ اور گھورتا ہی چلا گیا پھر قدرے خشک لہجے میں بولا: ’’مریخ پر مذاق کرنا منع ہے۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے، اگر کوئی مزاحیہ شاعری کرنے لگے یا ہنسی مذاق والی کہانی لکھ بیٹھے تو ہم اسے وہاں دفن کردیتے ہیں۔‘‘ اس نے سنجیدگی سے برف کے ایک تودے کی جانب اشارہ کیا۔
’’کہانی کو دفن کرتے ہیں یا لکھاری کو؟‘‘ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
’’دونوں کو۔‘‘ شاذلے نے سرد لہجے میں جواب دیا۔
میں نے آکسیجن سیلنڈر کی مدد سے ایک لمبی سانس لی اور چپ چاپ شاذلے کے ساتھ چلنے بلکہ پھدکنے لگا۔
’’وہ دیکھو!‘‘ شاذلے نے اشارہ کیا۔ دور وہ سفید رنگ کا جو مینار نظر آرہا ہے، اس وقت یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ چلوگے؟‘‘
مسلسل چلتے چلتے، میری پنڈلیوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا: ’’مشاعرہ گاہ‘‘ ابھی دور ہے، کیوں نہ ٹیکسی کرلیں؟‘‘
’’کیا! اتنے سے فاصلے کے لیے۔۔۔؟ ہم صرف دوسرے شہر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ شہر کے اندر ہم پیدل ہی سفر کرتے ہیں۔ ہماری اچھی صحت کا یہی راز ہے۔‘‘
’’اور میرے ممکنہ انتقال کا بھی شاید یہی راز ہو۔‘‘ میں بڑبڑایا تو شاذلے نے کہا۔ ’’ کیا کہہ رہے ہو؟‘‘
’’کچھ نہیں!!‘‘ مجھے شدت سے اپنی موٹر سائیکل یاد آرہی تھی چار قدم دور سے ڈبل روٹی بھی لانی ہوتی تو بھی میں اسی سے سفر کرتا تھا۔ مشاعرے میں، تیس پینتیس کے قریب ’’مریخی‘‘ سرخ چادروں پہ بیٹھے تھے۔ سامنے اسٹیج کی دیوار پر کچھ میٹرز لگے تھے، جیسے ہمارے بجلی کے میٹر ہوتے ہیں۔ ان میں ہرے نیلے بلب جل بجھ رہے تھے۔ حاضرین محفل ہاتھ اٹھا کر داد دیتے تو کبھی آنکھیں بند کرکے سر دھنتے محسوس ہورہے تھے۔ جبکہ شاعر غائب تھے۔ معلوم ہوا کہ شاعر ان میٹرز کے ذریعہ کلام ارسال کررہے ہیں اور حاضرین ’’ایئرفون‘‘ لگائے اسے سن رہے ہیں۔
میں فرش پہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک روبوٹ نما مریخی آیا اور میرے سر کے بال ہٹا کر جلد پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں استرا اور دوسرے میں اسکرو ڈرائیور ٹائپ چیز تھی۔
’’یہ کیا کررہے ہو؟‘‘ میں بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
شاذلے نے مجھے کندھے سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا ور بولا: ’’کچھ نہیں ہماری ایک ’’قومی نظم‘‘ ہے یوں سمجھو جیسے تمہارا قومی ترانہ۔ یہ مریخ کی روایت ہے کہ ہم اسے ہر نئے مہمان کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔‘‘
میرے بال کٹ کٹ کر شانے پہ گرنے لگے۔۔۔ دہشت سے میری حالت خراب ہونے لگی۔
’’یہ کیا کررہا ہے آخر۔۔۔!‘‘ میں تقریباً رو دینے کو تھا۔
’’ یہ دماغ کا اسکرو کھول کر، یادداشت کے خانے میں اس نظم کی چپ ڈال دے گا، تمہیں یاد ہوجائے گی، جب چاہو گے دہرا سکو گے۔‘‘ شاذلے نے سمجھایا۔
’’مجھے نہیں دہرانی یہ مریخی نظم۔‘‘ میں کراہ اٹھا مگر میرے چیخنے چلانے کا اس روبوٹ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ جیسے جیسے نظم میرے دماغ میں سما رہی تھی، مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کائنات کے کسی حصے میں شاعری کے ساتھ ایسا غیر شاعرانہ سلوک ہو رہا ہوگا۔ آہ! شاعری وہ بھی بذریعہ سرجری!! جب ہم مشاعرہ گاہ سے نکلے تو میں پاؤں کہیں رکھتا تھا اور پڑتے کہیں تھے۔ دل بند ہونے کے قریب تھا۔ میری حالت دیکھ کر شاید شاذلے کو رحم آگیا۔۔۔ بولا: ’’چلو کسی تفریحی مقام پہ چلتے ہیں۔‘‘
’’نہیں!‘‘ میں نے پہلی بار سختی سے کہا۔ ’’بہت ہوگئی تفریح میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔۔۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے واپس چھوڑ آؤگے۔ تم جلدی سے اپنا کام نمٹا لو۔۔۔ وہی جس کے لیے تم مجھے یہاں لائے تھے!‘‘
’’میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہارا دماغ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، اندر سے کچھ نہیں نکلے گا۔‘‘
’’کیا مطلب! آخر کیا نکلنا چاہیے دماغ سے؟‘‘ میں نے چڑ کر کہا۔
’’عقل!‘‘ شاذلے نے مختصر جواب دیا۔
’’اچھا! تو تم بہت عقل مند ہو جو کسی ’’جینئس‘‘ کے بجاے مجھے اٹھا لائے۔‘‘ میں جل کر بولا۔
’’ہاں۔۔۔ میں مانتا ہوں۔۔۔ غلطی ہوگئی۔‘‘ شاذلے نے اعتراف کیا۔ اب ہم شاذلے کے گھر واپس آچکے تھے، اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا:
’دیکھو! میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ مریخی جھوٹے وعدے نہیں کرتے۔ مگر اس وقت یہ ممکن نہیں۔ جب ہم اپنے کسی مشن پر ’’اڑن طشتری‘‘ زمین پر بھیجیں گے تو تمہیں بھی روانہ کردیا جائے گا۔۔۔ ابھی تم یہ مشروب پی کر سو جاؤ۔‘‘ میں پسی ہوئی لال برف کا ملغوبہ کھانا یا پینا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی میں نے گلاس ہاتھ میں لے لیا، کیا کرتا میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھا۔ مشروب پیتے ہوئے میں نے سوچا۔ زمین سے جو آکسیجن سلینڈر آیا ہے وہ بہت جلد ختم ہوجائے گا۔ کیا سو جانا رسک نہیں ہوگا؟ کیا مجھے ’’ابدی نیند‘‘ سلایا جا رہا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند نے آلیا۔۔۔ پھر کیا ہوا؟ کیا زندگی ختم ہوئی۔۔۔ کیا کہانی تمام ہوئی؟
*۔۔۔*
پارک میں رش نظر آرہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ کبھی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو پھر ڈھے جاتا کبھی اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر ان کی جھریوں کو بے یقینی سے دیکھنے لگتا۔ کبھی گرمی گرمی کہہ کر اپنا گریبان کھولنے لگتا۔ وہ اپنے اردگرد کھڑے تماشائیوں سے بے نیاز سا لگتا۔ اس کی خالی خالی آنکھوں سے محسوس ہوتا جیسے اپنے حواس میں نہ ہو۔ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ اس بزرگ کا کیا کیا جائے؟ ایک لمبے قد کے نوجوان نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا۔
’’کیوں بابا! گھر بھول گئے ہو کیا؟ اس عمر میں اکیلے کیوں نکلتے ہو، کسی پوتے نواسے کو ساتھ کیوں نہیں لے لیتے؟‘‘
’’پوتا۔۔۔ نواسا۔۔۔؟‘‘ بوڑھا جیسے حیرت سے گنگ رہ گیا۔ پھر سنبھل کر بولا: ’’میری تو اگلے سال عید پہ شادی ہے!‘‘
’’ہائیں ! شادی!!‘‘ مجمع میں موجود سب ہی لوگ ہنسنے لگے۔
’’بے چارہ! کچھ کھسکا ہوا ہی لگتا ہے۔‘‘ ایک موٹے شخص نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
اسی اثناء میں بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایک اور صاحب، بوڑھے کے قریب پہنچے اور اکڑوں بیٹھ کر بولے۔
’’ہاں بھئی! بابا جی۔۔۔ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟‘‘ بوڑھے نے چند لمحے توقف کیا، جیسے ذہن پہ زور دے رہا ہو پھر اچانک اس کی آنکھوں میں زندگی کی لہر سی ابھری، وہ جوش بھرے انداز میں بے قراری سے بولا۔
’’پارک کے سامنے، سرمئی اپارٹمنٹ، فلیٹ نمبر 312۔‘‘
’’کیا!‘‘ وہ صاحب چیخ پڑے۔ ’’کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو میرا ہے، میں مالک مکان ہوں، آج کل خود ہی رہ رہا ہوں۔ ہاں پینتیس چالیس سال قبل البتہ میرے والد نے ایک شخص کو کرایہ پہ دیا تھا، جو سنا ہے اچانک غائب ہوگیا۔ کچھ پتا نہ چلا، اب تو مر کھپ بھی گیا ہوگا!‘‘
بوڑھے کی آنکھوں میں گویا زندگی بجھ سی گئی۔ چہرہ صدمے سے سفید پڑگیا۔ مگر بہت جلد اس نے خود کو سنبھال لیا، گردن گھما کر اردگرد کھڑے تماشائیوں کو دیکھا پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بیٹھ گیا۔ درخت سے ٹیک لگائی اور آنکھ بند کرکے ایک ایسی ’’ نظم‘‘ گنگنانے لگا جس کی ’’زبان‘‘ سے پارک میں موجود کوئی شخص واقف نہ تھا۔
*۔۔۔*
Facebook Comments